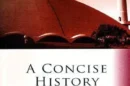مولانا محمد عثمان رمضان
مدرسہ ڈسکورسز اسلامی تہذیب میں جدید علم الکلام کی تشکیل کا ایک زریں باب ہے جسے اکیسویں صدی کے آغاز میں ہند و پاک کے دینی مدارس سے سندِ فضلیت حاصل کرنے والے نوجوان علما ء رقم کر رہے ہیں۔ مدرسہ ڈسکورسز، جدید دور اور معاصر علمی فضا میں مسلمانوں کی علمی، عقلی اور کلامی روایت کی بازیافت ہے۔ یہ ماضی ،حال اور مستقبل میں ایک متحرک اور نامیاتی تعلق کا خواہاں ہے جس کے حصول کے لیے نہایت عمدہ اور مفید مطالعاتی نصاب اور تربیتی نظام تخلیق کیا گیا ہے ۔ پہلے دن سے مدرسہ ڈسکورسز کا یہ منہج رہا ہے کہ شرکاء کو ایسا علمی اور فکری ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی جائے جو علمی پیچیدگیوں سے آراستہ ہو اور فکری وابستگی کے اصرار سے پاک ہو۔ یہاں سوالات کے حتمی جوابات نہیں دیے جاتے اور نہ ہی جوابات کی صحت یا عدم صحت کو موضوعِ بحث بنایا جاتا ہے بلکہ جدید دور میں پیدا ہونے والے سوالات کی بہتر تفہیم اس کا بنیادی ہدف ہے تاکہ شرکاء اس تفہیم کی بنیاد پرکلامی چیستان میں موزوں تعلیل اور توجیہ کے قابل ہو سکیں ۔
مدرسہ ڈسکورسز تبلیغی مشن نہیں بلکہ ایک تعلیمی اور تحقیقی پروگرام ہے۔ تعلیم اور تبلیغ میں بہت بنیادی فرق ہوتا ہے یہی فرق متعلم اور مبلغ کی حیثیات اور ذمہ داریوں پر بھی اثرانداز ہوتا ہے۔ سادہ الفاظ میں تعلیم ایک پروسس کا نام ہے جس میں مختلف تصورات اور تصدیقات کو دیکھا، سمجھا اور سیکھا جاتا ہے اور تبلیغ ایک خواہش کا نام ہے جس میں اپنے نکتہ نظر کو سچائی اور تیقن کے ساتھ دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ مدرسہ ڈسکورسز چونکہ ایک خالص علمی academic پلیٹ فارم ہے اس وجہ سے اس کی اپنی مخصوص حرکیات ہیں۔ علمی دنیا کا اپنا ایک خاص مزاج ہوتا ہے۔ اس کی اپنی مخصوص اقدار ہوتی ہیں ۔یہاں دلائل کے ساتھ اپنی آراء کا اظہار کیا جاتا ہے اور دوسروں کو اپنی آراء کے اظہار کا حق دیا جاتا ہے۔ علمی دنیا میں ہمیشہ اپنی رائے میں غلطی اور دوسروں کی رائے میں صحت کا ا مکان تسلیم کیا جاتا ہے ۔ جہانِ دانش دراصل جہانِ اکتشاف ہوتا ہے ۔ اس میں امکان کا یہ عنصر ہررائے/ بیانیے کو ممکنہ بنا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے MD (مدرسہ ڈسکورسز) میں حتمی جوابات پر اصرار نہیں کیا جاتا بلکہ ممکنہ بیانیے پیش کیے جاتے ہیں۔ پروفیسر ابراہیم موسیٰ نے آئن لائن کلاس میں ایک سوال کے جواب میں اس بات کا اظہار یوں کیا کہ میرے پاس اس سوال کا حتمی جواب نہیں بلکہ ممکنہ بیانیہ ہے۔
. بعض حضرات نے اس چیز کو بنیاد بنا کر مدرسہ ڈسکورسز پر تنقید بھی کی ہے کہ اس میں سوالات کے جوابات نہیں دیے جاتے اور اسے ایک خامی کے طور پر پیش کیا ہے جبکہ یہ مدرسہ ڈسکورسز کی خامی نہیں بلکہ اس کی مختلف خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ یہاں کسی تناظر پر مبنی ،فکری پیراڈائم کو ترجیح نہیں دی جاتی بلکہ تنقیدی اور متحرک انداز ِفکر کو سراہا جاتا ہے ۔ اختلافِ رائے قابل مذمت نہیں بلکہ قابل رحمت ہوتا ہے ۔ اگر اختلاف کی بنیاد علمی ہو اور اس کا استدلال قوی ہو تو یہاں علمی اختلاف سے حظ اٹھایا جاتا ہے ۔ یہاں شرکاء میں علمی مزاج ، تحقیقی رویے اور تخلیقی قوتوں کو ابھارا جاتا ہے ۔ کسی نکتہ نظر پر اصرار یا کسی متعین رائے کو مسلط نہیں کیا جاتا بلکہ زیرِ بحث موضوع سے متعلق ابحاث کا استقصا کر کےفیصلہ شرکاء کی صوابدید پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔
مولانا وقار احمد
مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ میرا مادر علمی ہے، میں نے علمی و فکری غذا نصرۃ العلوم گوجرانوالہ سے حاصل کی اور ابھی بھی کر رہا ہوں ۔نصرۃ العلوم میں موجود مختلف اساتذہ کے زیر سایہ ہونی والی فکری تربیت کی بدولت مجھے تاریخ سے مناسبت پیدا ہوگئی، بالخصوص برصغیر میں شاہ ولی اللہ اور ان کی تحریک، دیوبندی جماعت کے افکار میری دلچسپی کا موضوع بن گئے، اس کے ساتھ ساتھ علماء ہند کی تاریخ و افکار پر تنقیدی نگاہ اور ان سے آج کے حالات و مسائل کے لیے اخذ و استفادہ بھی نصرۃ العلوم کے ماحول سے میرے مزاج کا حصہ بن گیا۔
۲٠۱۶ء کے اواخر میں پتہ چلا کہ استاد گرامی مولانا عمار خان ناصر نوٹرے ڈیم کے کچھ حضرات کے ساتھ مل کر مدارس کے فضلا کے لیے کوئی ایسا کورس متعارف کروا رہے ہیں، جس میں قدیم تراث اسلامی اور جدید فلسفہ کے مباحث پڑھائے جائیں گے۔ روایت پسند ہونے کی بنا پر پہلے تو یہ خیال پیدا ہوا کہ میں یہ کورس نہیں کرتا، امریکی جدید مباحث اور قدیم تراث میں سے ہمیں کیا پڑھائیں گے۔ ان کے اس سے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔؟ پھر معاً یہ خیال آیا کہ جو مرضی پڑھائیں، مدرسہ نصرۃ العلوم میں 7 سال گزارنے کے بعد کوئی ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا، جو کچھ وہ پڑھائیں گے، اسے نقد و نظر کی کسوٹی پر پرکھیں گے، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لی جائے ، نہیں تو کوئی زبردستی تو ہمیں کسی بات کے ماننے یا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس ذہن کے ساتھ میں نے داخلے کی درخواست استادجناب عمار خان ناصر صاحب کو بھیج دی۔اور ساتھ ہی پروگرام اور اس کی انتظامیہ کے بارے میں مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔
پہلے دو سمسٹرز میں میں نے اس کورس کو بہت ہلکا لیا، مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا اس کی افادیت سامنے آتی گئی۔ کورس کے دوران اندازہ ہوا کہ یہ کورس متعدد حوالوں سے مفید ہے، خصوصا ابن خلدون، شاہ ولی اللہ اور مولانا عبید اللہ سندھی کی مختلف مباحث کو سمجھے اور ان کو عقلیات جدیدہ پر پرکھنے میں بڑی سہولت ہوئی، چنانچہ اس کے بعد اس کورس میں میری دلچسپی شاہ ولی اللہ اور مولانا عبید اللہ سندھی کے حوالے سے بھی بڑھتی چلی گئی۔
یہ کورس مدارس کے فضلاء کو تین چیزیں عطا کر رہا ہے:
- مسلم علمی روایت سے مضبوط آگاہی
- جدید سائنسی علوم کے کارنامے ، دائرہ کار اور جدیدیت کے جلو میں مذہب کو پیش آنے والے چیلنجز سے آگاہی کے ساتھ فلسفہ جدیدہ سے مذہبی فکر کی ہم آہنگی کے امکانات و ممکنہ اسالیب سے روشناسی
- خود اعتمادی و خود آگاہی میں اضافہ
میرے نزدیک ان تینوں خوبیوں کے پیدا ہونے کا بڑا سبب ڈسکورس کے ماحول میں موجود زندہ دلی ، خوشگوار تعلیمی ماحول اور اس کے ساتھ مقصد کی لگن اور تڑپ ہے۔امید ہے کہ یہ کورس مستقبل میں نوجوان علماء کو اسلام کی سطحی فکر کا اسیر ہونے سے بچانے میں معاون ہوگا۔میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اس کورس میں پڑھنے والے جامد مذہبیت سے محفوظ رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کسی ایسی نفسیات کا شکار بھی نہیں ہوں گےجو تاریخ اسلامی اور سیرت رسول سے ان کوبے بہرہ کر دے۔
مولانا محمد نوید
اس مختصر تحریر میں، میں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ مدرسہ ڈسکورسز کیاکررہا ہے ؟اورکیاکسی مدرسے سے درس نظامی اور تخصص کرنےیاکسی یونیورسٹی سے شعبہ علوم اسلامیہ میں اعلی سطحی ڈگری لے لینے کے بعد بھی کوئی ایسی گنجائش باقی رہتی ہے کہ اس سے بھی اعلیٰ سطحی مباحث کے لیے مزید کسی کورس کو پڑھا جائے ؟
پاک وہند میں علومِ دینیہ تفصیل سے پڑھنےکے لیے درس نظامی کا نظام ِتعلیم موجود ہے ،اور درسِ نظامی کے بنیادی دینی علوم کا جامع نصاب ہونے میں دو رائیں بھی نہیں ہیں۔ اس کے باوجود اگر درس نظامی کی اپنی حیثیت کو مدنظر رکھاجائے تو مذکورہ بالاسوال ذہن میں پیدا نہیں ہوتا کہ مدرسے کا نصاب مکمل پڑھ لینے کے بعد کسی اور نصاب کی ضرورت ہے یا نہیں ۔ کیونکہ مہتمم دارالعلوم دیوبند قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ مشہور ہے جو انھوں پاکستان کے مختلف مدارس کے دستار بندی کے اجتماعات میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے مدارس عربیہ میں سند فراغت عالم دین ہونے کی نہیں ہوتی ، بلکہ عالم دین بننے کی صلاحیت کی ہوتی ہے ، یعنی اس بندے نے مدرسے میں رہتے ہوئے بنیادی دینی علوم پڑھ لیے ہیں ،اب اگر یہ شخص اِن علوم میں مزید مہارت پیدا کرکے عالمِ دین بننا چاہے تو بن سکتا ہے ۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان میں یہ بات واضح لفظوں میں موجود ہے کہ ہمارے مدارس حرفِ آخر نہیں ہیں،بلکہ عشق کے امتحان اور بھی ہیں ۔ یہ بیان آج کے ان فارغینِ مدرسہ کے سامنے لازمی ہونا چاہیے جوفراغت کے بعد اپنے آپ کو عالم الکل سمجھنا شروع کردیتے ہیں ۔
ہمارے مدارسِ عربیہ میں رائج علوم و فنون اور ان کے موجودہ نظام تعلیم میں درسِ نظامی کے علاوہ بعض فنون میں تخصصات کا کسی حد تک رواج موجود ہے ۔ان تمام درجات اور شعبہ جات کے نصاب اپنی جگہ کتنے ہی مفید کیوں نہ ہوں، بلکہ واقعۃ مفید بھی ہیں ، مگر دوسری طرف اس حقیقت سےبھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس نصاب کو اچھی طرح پڑھنے کے بعد بھی طلباء کوجدید دور کے عملی ،فکری، سیاسی ،معاشی ،معاشرتی ، ملکی اور عالمی قانونی مسائل سے تفصیلی واقفیت تو دور کی بات ، مختصر تعارف بھی حاصل نہیں ہوتا،جس کی وجہ سے جب ان کے سامنے جدیدطرز فکر کاکوئی سوال آتاہے تو چہ جائے کہ وہ اس کا جواب دیں، وہ اس سوال کو اچھی طرح سمجھ بھی نہیں پاتےاور ان کا افق ذہنی مخصوص ددائرہ فکر ہی میں محدود رہتاہے ،اس کی وجہ واضح ہے کہ اس سے پہلے ان کااس قسم کے سوالات سے نہ واسطہ پڑا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی علمی تربیت کی گئی ہوتی ہے ،اور ہمارے مدارس میں مروجہ نظام کے مطابق کوئی ایسی گنجائش بھی نظر نہیں آتی کہ جہاں ان مباحث کو جگہ دی جاسکے ۔جہاں تک ان مسائل کی اہمیت کا تعلق ہے تو وہ کسی بھی صاحب فراست پر مخفی نہیں ہے ۔
اس ساری صورت حال میں ابراہیم موسی صاحب نے جو خود بھی بنیادی طور پر مدرسے ہی کے فیض یاب ہیں ، درس نظامی سے فارغ التحصیل علمائے کرام کے لیے ایک ایسا جامع پروگرام ترتیب دیا ہے کہ جس میں اس پروگرام کے شرکاء کو پہلے یہ سوالات بتائے گئے کہ ہمارے اردگرد کی دنیا کے لوگوں کے کیا سوالات ہیں ،اس وقت دنیا کس طرح سوچ رہی ہے ،ان کے سوچنے کی علمی ، فکری اور تجرباتی بنیادیں کیا ہیں ؟ تاکہ ہم ان سوالات کو ان کی حقیقی سطح پر رکھ کر ان کا سامناکرسکیں ۔اس کام کے لیے ایم ڈی منتظمین نے جو طریقہ اختیار کیا وہ بھی کوئی اجنبی نہیں تھا ، بلکہ اسی قسم کے سوالات کو اپنی ہی تراث میں تلاش کرکے ان کا تفصیل سے مطالعہ کروایاگیا، ان سوالات کےتفصیلی مطالعے سے نہ صرف نفس مسئلہ واضح ہوا بلکہ ماضی میں اس مسئلے کے بارے میں اختیار کیے جانے والے مختلف مواقف اور مکاتب فکر کا بھی تفصیلی تعارف سامنے آگیا۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ، بلکہ ان مسائل کا موجودہ حالات میں کیا انطباق ہے اور کیا موقف ہے، یہ اصل مسئلہ ہے ۔
ایم ڈی کی خوبی یہ ہے کہ اس مرحلے میں آکر یہ اپنے شرکاء کو بالکل آزاد چھوڑدیتاہے اور کسی ایسے سوال کا جواب دینے سے گریز کرتا ہے کہ جس کا تعلق موجودہ حالات میں کسی مسئلے کے بارے میں موقف اختیار کرنے کے ساتھ ہو، بلکہ ایم ڈی انتظامیہ اپنے شرکاء کو اس موقف پربغیر کسی ذہنی دباؤکے تبصرے اور نقد کی اجازت دیتی ہے، بلکہ سوالات اٹھانے کو پسند بھی کرتی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے ۔ایم ڈی کی اس دوطرفہ کاوش نے شرکاء کو دہرا فائدہ دیا ، ایک تو ان کو اپنے علمی تراث سے واقفیت حاصل ہوئی اور دوسرا موجودہ مسائل کے بارے میں کوئی موقف اختیار کرنے میں مددملی ۔اس تفصیل کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایم ڈی نے درحقیقت اُسی کام کو آگے بڑھایاہے جس کی بنیاد مدرسے نے خود رکھی اور مزید ترقی کے لیے آزاد چھوڑ دیا تھا، آگے چل کر یہ طالب علم کیا راہ اختیار کرے گا یہ مدرسے کا نہ موضوع ہے اور نہ ہی مدرسے نے کبھی اس پرسوچا ہے۔
میرا خیال ہے کہ بعینہ یہی کورس یا اس قسم کے کورسز کا پاکستان کی بڑی بڑی جامعات میں شروع ہونے چاہییں تاکہ ہمارے طلباء جو چیزیں باہر کی یونیورسٹیوں کی سرپرستی میں پڑھتے ہیں وہی چیزیں ان کو اپنے گھر ہی میں رکھ کر پڑھائی جاسکیں ، تاکہ وہ خدشات پیدا ہی نہ ہوں جو نامعلوم افراد کی جانب سےسامنے آرہے ہیں اور ایک ایسی کھیپ تیار ہوسکے کہ جو موجودہ دنیا کو اسی کے ذہن کے مطابق سمجھنے اور ان کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ کیا پاکستان میں کسی کو بھی ان حالات کا اندازہ نہیں ہوا کہ جو اس وقت دنیا کے ہیں ؟ کیا ان سوالات کی اہمیت پہلے کسی نے نہیں جانی ؟اگر کسی اور کو ان حالات کا ادراک ہے تو ان سوالات کو یہاں زیر بحث کیوں نہیں لایاگیا ؟ یا ان کو موضوع تحقیق کیوں نہیں بنایاگیا؟ میرے خیال میں اس کی بڑی وجہ ہمارے دینی علوم میں رسوخ رکھنے والے افراد کی عدم توجہ ہے ۔ اگر کسی طرح روایتی علوم پر دسترس رکھنے والے علماء کی اس طرف توجہ مبذول کروا دی گئی تو ممکن ہے کہ غیر معمولی نتائج برآمد ہوں ۔اس کورس کے لیے ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ابھی تک راقم الحروف کے سامنےتادم تحریر کوئی ایسا اعتراض سامنے نہیں آیا جوبراہ راست مدرسے سے منسلک افراد کی جانب سے ہو ، بلکہ جب مدرسے والوں کو اس کورس کا علم ہوتاہے تو ان کی طرف سے غیر معمولی دلچسپی ظاہر کی جاتی ہے ، کیونکہ ان کو اپنی اس علمی کمزوری کا بخوبی اندازہ ہے ۔
مولانا فرہاد علی
امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الدر المنثور فی التفسیر الماثور کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ ’’میں نے ایک مفصل اور ضخیم تفسیر لکھی جو پچاس جلدوں پر مشتمل تھی۔ پھر میں نے لوگوں کے رجحان پر غور کیا تو یہ عقدہ وا ہوا کہ لوگ طویل کتابوں کے مطالعہ سے گریز پا ہیں، اسی لئے میں نے اس تفسیر میں اس کی تلخیص کی.’’ یہ تلخیص آٹھ جلدوں میں ہے۔ افسوس کہ امام سیوطی کی یہ مفصل تفسیر دستیاب نہیں ہے۔اسی طرح صاحب ہدایۃ کی اسّی جلدوں پر مشتمل تصنیف بھی نایاب ہے۔ ہدایۃ انھی اسّی جلدوں کا عطر ہے۔
سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے دستیاب کتابوں سے استفادہ کرلیا؟ تسلیم کہ سب کا بالاستیعاب مطالعہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، مگر ہمیں جن موضوعات سے دلچسپی ہوتی ہے، کیا ان پر دستیاب کتابیں ہم پڑھ چکے ہیں؟
مدرسہ ڈسکورسز کے دوسرے یونٹ میں جیسے جیسے آگے بڑھتے رہے، یہ سوال مزید شدت سے سامنے آیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ہم تو اپنی روایت سے بے خبر ہی نہیں، غافل بھی ہیں۔ میں اپنی بات کروں تو مجھے امام ماتریدی رحمہ اللہ کی کسی کتاب کا علم ہی نہیں تھا، چہ جائیکہ اس سے استفادہ کرنا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی دو چار مشہور کتابوں کے علاوہ یہ حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا کہ ان کی درء تعارض العقل و النقل کے نام سے دس بارہ جلدوں میں کوئی ضخیم اور مفید کتاب بھی ہے۔ اسی طرح امام رازی کی تحریر پہلی بار نظر نواز ہوئی۔ اس کے بعد سعد الدین تفتازانی کی کتاب شرح العقائد کی ابتدائی ابحاث پڑھنے کا زاویہ نظر ہی بدل گیا۔
بعض چیزوں کو ہم نے ہمیشہ سطحی سمجھا، مگر اس کورس کے دوران معلوم ہوا کہ جنہیں ہم آسان اور سطحی چیزیں سمجھ رہے تھے، وہ درحقیقت بڑی گہرائی رکھتی ہیں۔ ہم معرکہ عقل و نقل کو سادہ سا مسئلہ سمجھ بیٹھے تھے مگر امام رازی رحمہ اللہ کے دلائل پڑھ کر اندازہ ہوا کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ امام رازی کے دلائل کے جوابات کے لئے جب ابن تیمیہ کی تحریر پڑھی تو امام ابن تیمیہ کی وسعت علمی اور ذہانت و نکتہ سنجی پر انگشت بدنداں تھا۔
یہاں مجھے مسرت اور حسرت کے ملے جلے احساسات نے گھیر لیا۔ حسرت اس بات پر تھی کہ علم الکلام کی بالکل ابتدائی بحث پر کتب خانے موجود ہیں مگر ہم کبھی نصابی کتابوں کے دائرے سے باہر نہیں نکلے۔ مسرت اس بات پر ہوئی کہ ہمارے اسلاف نے کس طرح علمی ماحول اور خالص علمی انداز میں ایک دوسرے پر تنقید کی جس کے نتیجے میں علم الکلام نے ترقی کے زینے عبور کیے۔ دور حاضر میں اس مکالمہ اور علمی تنقید کے حوالہ سے ہمارا رویہ افسوس ناک ہی نہیں، شرمناک بھی ہے۔
مدرسہ ڈسکورس میں ہمیں جو مواد پڑھنے کو ملتا ہے، اس میں انگریزی تحریریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ انگریزی تحریریں پڑھنے ہوئے محسوس ہوا کہ مغرب علوم کی کن حدوں کو چھو رہا ہے۔ مثلاً انہوں دیوی اور دیوتاوں سے منسوب داستانوں پر جتنی ریسرچ کی ہے، ان کی تخلیق کے اسباب اور معاشرے پر ان کے اثرات کا جائزہ جن پہلووں سے لیا ہے، وہ حیران کن ہے۔ علاوہ ازیں علم الکلام میں جن ابحاث کا ضمنی طور پر ذکر ملتا ہے، ان کو مستقل علم کی حیثیت دینا ان کی کاوشوں کا مرہون منت ہے۔فراہم کردہ مواد کو پڑھنے سے اندازہ ہوا کہ خیر و شر کے تصورات کتنے متنوع ہیں۔
جیسا کہ عرض کیا، ہم بعض معاملات کو سادہ سمجھتے ہیں مگر در حقیقت وہ پیچیدہ ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم اسلام کو پورے عالم کے لئے اسوہ اور راہ عمل سمجھتے ہیں اور یہ صحیح بھی ہے، مگر اسلامی ممالک کے علاوہ مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگے ہوئے معاشروں میں اسلام کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اس سوال کی اہمیت اور پیچیدگی اس وقت کھل کر سامنے آتی ہے جب ہم ان معاشروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کے ہاں خیر و شر، اخلاق اور اقدار کی بنیادیں ہی کچھ اور ہیں اور اس پر استوار عمارت کا نقشہ اسلام کے پیش کردہ ماڈل سے بالکل مختلف ہے۔ اسلامی اقدار، اخلاق اور اصولوں کو جب تک ان کے اذہان و قلوب میں نہیں اتارا جائے گا اور اسلام کی آفاقیت کو واضح نہیں کیا جائے گا جو کہ وقت کی اہم ضرورت اور دانتوں پسینہ لانے والا کام ہے، تب تک اسلام کو ان کے دلوں میں نہیں اتارا جا سکتا۔
ہمیں مغربی فلسفے کی تاریخ پر Sophie’s world کا مطالعہ کروایا جا رہا ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ یونانی فلاسفہ کا کارنامہ کیا تھا۔ آج سائنسی دور میں ہم بڑی آسانی سے یونانی فلاسفہ کے پیش کردہ بعض نظریات کو غلط ثابت کرسکتے ہیں، مگر ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کے مسلّمہ پیراڈائم سے باہر نکل کر سوچا اور قدرتی تبدیلیوں اور ماحولیاتی تغیرات کی توجیہ کے لیے دیو مالائی داستانوں کو مسترد کیا اور خود فطرت میں اس کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوئے، یہ الگ موضوع ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ انہوں نے سائنسی طریقہ کار کی پہلی اینٹ رکھ دی۔
God and Logic in Islam اپنے موضوع پر انتہائی مفید کتاب ہے۔ ہمیں اس کتاب کے کے چند صفحات مطالعہ کے لیے دیے گئے۔ اس میں جہاں مصنف نے عقل کے متنوع تصورات کو بڑی خوبصورتی سے واضح کیا ہے، وہاں اسلامی تاریخ اور مسیحی تاریخ میں مشترک معرکہ ہائے فکر کو بھی بیان کیا ہے جس کی روشنی میں ہم اپنی فکری جدوجہد کے خد وخال واضح کرسکتے ہیں۔ ہم اس پر غور کرسکتے ہیں کہ مسیحیت کو جب بھی کوئی فکری چیلنج درپیش ہوا تو وہ اس سے کیسے نبرد آزما ہوئی ۔ اس سے کون سی غلطیاں سرزد ہوئی اور اس کے کیا نتائج نکلے۔ ان پہلووں پر غور کرکے ہم ان غلطیوں سے بچ سکتے ہیں۔
آخر میں مدرسہ ڈسکورس کے تمام منتظمین کا بالعموم اور ڈاکٹر ابرہیم موسی، ڈاکٹر ماہان مرزا، پروفیسر وارث مظہری اور مولانا عمار خان ناصر کا بالخصوص تہہ دل سے شکر گذار ہوں جنہوں نے ہمیں اسلام کی فکری روایت سے متعارف اور انسانی فکر کے نئے پہلووں سے روشناس کرایا۔ اللہ تعالی ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کو بہترین صلہ عطا فرمائے، آمین۔
مولانا محمد عرفان ندیم
دنیا کی معلو م تاریخ میں اب تک بائیس نامور تہذیبوں نے جنم لیا ہے اور تہذیبوں کے سلسلے میں زمانے کا یہ اصول رہا ہے کہ زمانہ ہمیشہ غالب تہذیب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ مغلوب تہذیبیں غالب تہذیب کی رسم و رواج اپنانے اور ان کے طور طریقے اپنانے پر مجبور ہو جاتی ہیں ۔ ماضی میں اسلامی تہذیب کے عروج کے زمانے میں ہمیں اس کے واضح شواہد ملتے ہیں جب بغداد ، قرطبہ اور اشبیلیہ علوم و فنون کے مراکز ہوا کر تے تھے اور دنیا بھر کے یہودی اور عیسائی اہل علم حصول علم کے لیے ان شہروں کا رخ کرتے تھے ۔ لیکن آج صورتحال یکسر مختلف ہے ۔ پچھلے پانچ سو سالوں سے مغربی تہذیب نے دنیا کو ہر طرح سے مسخر کر لیا ہے ۔ علوم وفنون سے لے کر سیاسی اور عسکری شعبہ جات میں مغربی تہذیب نے جو ترقی کی ہے اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ اسلامی تہذیب اپنا تشخص برقرار نہ رکھ پائی ۔ مغربی تہذیب کا سب سے بڑا حریف اگر کوئی ہو سکتا تھا تو وہ اسلامی تہذیب تھی مگر ہم پچھلے تین چار سو سالوں سے جس ذہنی، سماجی اور سیاسی انحطاط سے گزر ے اس میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم مغربی تہذیب کے چیلنج کا جواب دے سکتے ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مغربی تہذیب مکمل طور پر غالب آ گئی اور ہم نے اپنی بچی کچھی میراث کو گلے لگانے میں ہی عافیت جانی ۔
اب اکیسویں صدی میں عالم اسلام کے مختلف گوشوں میں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو ا ہے اور بعض جگہوں پر انفرادی کوششیں اس ضمن میں ہوئی ہیں ۔ مدرسہ ڈسکورس کو بھی میں اسی احساس کے تحت دیکھ رہا ہوں ۔ کورس کا حصہ بننے سے قبل تذبذب کی حالت تھی لیکن اب تک کی کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد شرح صدر ہو گیا ہے اور کورس کی اہمیت و افادیت بھی واضح ہو گئی ہے ۔ دراصل ہمارے ہاں ان مباحث کو اہل مدارس اور یونیورسٹی میں سے کسی نے بھی اہم نہیں سمجھا جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ جدید سائنس نے ہمارے لیے کیا مسائل اور چیلجنز پیدا کر دیئے ہیں اور ہم نے انہیں کیسے رسپانڈ کرنا ہے ۔ کورس کی ابتدائی کلاسز میں ابھی تک جو مواد پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے اور جس طرح کی ڈسکشن ہوئی ہےاور شرکاء نے جو کارکردگی پیش کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ منتظمین کی یہ کوشش ضرور بار آور ہوں گی اور اس کورس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں گے ، بلکہ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کوشش قابل تقلید بن جائے گی اور اہل علم اس طرح کے مباحث کا آغاز کر دیں گے۔ ابھی تک کی کلاسز سے بہت ذیادہ نہیں تو اتنی بات ضرورسمجھ میں آ گئی ہے کہ اس وقت ہمارے مسائل کیا ہیں ، ہمیں کن چیلنجز کا سامنا ہے ، لوگ خصوصا مغرب میں لوگ sکائنات اور خدا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ، سائنس اور مذہب کے مسائل کیا ہیں ، سائنس نے مذہب کو کن کن پہلووں سے لاجواب کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمیں جدید حالات میں اپنی بات کو کس طرح پیش کرنا ہے اور مغربی تہذیب کے ساتھ کس طرح مکالمہ کیا جا سکتا ہے ۔دنیا کی معلو م تاریخ میں اب تک بائیس نامور تہذیبوں نے جنم لیا ہے اور تہذیبوں کے سلسلے میں زمانے کا یہ اصول رہا ہے کہ زمانہ ہمیشہ غالب تہذیب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ مغلوب تہذیبیں غالب تہذیب کی رسم و رواج اپنانے اور ان کے طور طریقے اپنانے پر مجبور ہو جاتی ہیں ۔ ماضی میں اسلامی تہذیب کے عروج کے زمانے میں ہمیں اس کے واضح شواہد ملتے ہیں جب بغداد ، قرطبہ اور اشبیلیہ علوم و فنون کے مراکز ہوا کر تے تھے اور دنیا بھر کے یہودی اور عیسائی اہل علم حصول علم کے لیے ان شہروں کا رخ کرتے تھے ۔ لیکن آج صورتحال یکسر مختلف ہے ۔ پچھلے پانچ سو سالوں سے مغربی تہذیب نے دنیا کو ہر طرح سے مسخر کر لیا ہے ۔ علوم وفنون سے لے کر سیاسی اور عسکری شعبہ جات میں مغربی تہذیب نے جو ترقی کی ہے اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ اسلامی تہذیب اپنا تشخص برقرار نہ رکھ پائی ۔ مغربی تہذیب کا سب سے بڑا حریف اگر کوئی ہو سکتا تھا تو وہ اسلامی تہذیب تھی مگر ہم پچھلے تین چار سو سالوں سے جس ذہنی، سماجی اور سیاسی انحطاط سے گزر ے اس میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم مغربی تہذیب کے چیلنج کا جواب دے سکتے ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مغربی تہذیب مکمل طور پر غالب آ گئی اور ہم نے اپنی بچی کچھی میراث کو گلے لگانے میں ہی عافیت جانی ۔
اسلامی علمی روایت میں علم الکلام کا ارتقاءایک خاص تناظر میں ہو ا تھا، اسلامی فتوحات کے نتیجے میں اسلام جب عجمی علاقوں میں پہنچا اور وہاں کے مقامی فلسفوں سے اس کا واسطہ پڑا تو اس کے نتیجے میں علم الکلام کی بنیاد پڑی۔ عباسی عہد میں یونانی علوم کے تراجم ہوئے تو علم الکلام ایک چیلنج کے طور پر مزید نکھر کر سامنے آیا۔ یہ دور اسلامی علمی روایت اور علم الکلام کے عروج کا دور تھا ، بعد میں جب اسلامی تہذیب اور مختلف خطوں سے مسلمان حکومتوں کا خاتمہ ہوا تو ہماری علمی روایت بھی کمزور پڑ گئی۔ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں نوآبادیاتی دور کے نتیجے میں ہم اپنی روایت سے کٹ گئے اور اسے آگے نہیں بڑھا سکے ۔ اب ہم دفاعی پوزیشن پر کھڑے ہیں اور تہذیب ، روایت اور تراث میں جو باقی بچا ہے صرف اسی کی حفاظت کو اپنی زندگی کا وظیفہ سمجھتے ہیں۔ یہ رویہ بیک وقت صحیح بھی ہے اور غلط بھی مگر اتنی بات ضرور ہے کہ ہمیں اپنی تہذیب ، روایت اور تراث کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامی پوزیشن اختیار کرنی پڑے گی ۔ صرف علم الکلام کو دیکھ لیں، مغربی دنیا کی ہر نامور یونیورسٹی میں تھیالوجی کے نام سے ماسٹر سے لے کر پی ایچ ڈی تک کورس پڑھایا جا رہا ہے اور پاکستان کی کسی ایک یونیورسٹی میں بھی اس طرح کا کوئی کورس شامل نصاب نہیں۔ پڑھانا تو دور کسی یونیورسٹی میں تھیالوجی کے نام سے کوئی ڈیپارٹمنٹ ہی موجود نہیں ۔ اور مدارس میں جو علم الکلام پڑھایا جا رہا ہے، وہ وہی ہے جو یونانی فلسفے کے رد کے لیے مرتب کیا گیا تھا جبکہ دنیا آج ایک ہزار سال آگے بڑھ چکی ہے ۔ جدید سائنس نے بہت ساری نئی حقیقتو ں کو آشکار کر دیا ہے اور آج ہمیں یونانی فلسفے نہیں بلکہ جدید سائنس اور جدید مغربی فلسفے کو مد نظر رکھ کر نیا علم الکلام ڈویلپ کرنے کی ضرورت ہے ۔
مدرسہ ڈسکورسز کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ کلاسیکی اسلامی علمی روایت کے احیاء کی کوشش کی جائے ۔ تاہم کورس کے بعض شرکاءاور عمومی طور پر سوسائٹی میں بھی یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ ہمارے دینی ادارے اور علماءدور جدید کے ان سوالات کو رسپانڈکیوں نہیں کر رہے اور اس اعتراض کو بنیاد بنا کر بعض اوقات مدارس اور علماءکے بارے میں غیر مناسب اور ناشائستہ رویہ اپنایا جا تا ہے ، تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر کام کو مدارس اور علماءکے کھاتے میں ڈال دینا مناسب نہیں ۔ مدارس اور علماءکا دائرہ کار محدود اور وسائل بہت کم ہیں اور اتنے محدود وسائل کے ساتھ اپنا وجود برقرار رکھنا اور معاشرے کو دینی راہنمائی فراہم کرتے رہنا ہی بڑی بات ہے ۔ نظریہ ارتقاءاور اس جیسے دیگر سائنسی و فکری مسائل پر غور و فکر اور ریسرچ کے لیے وقت اور سرمایہ دونوں درکار ہیں ۔بذات خود مغرب میں اگران سوالات پر ریسرچ ہو رہی ہے تو یہ کام کلیسا یا کوئی مذہبی ادارہ نہیں کر رہا بلکہ وہاں کی یونیورسٹیوں میں ہو رہے ہیں اس لیے کچھ کام ہماری یونیورسٹیوں کو بھی کرنا چاہیے اور ہمارے عصری تعلیمی اداروں اور ماہرین تعلیم و تحقیق کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ خود اسلامی علمی روایت جب اپنے عروج پر تھی تب یہ کام کسی مذہبی ادارے میں نہیں بلکہ عام تعلیمی اداروں میں ہوا تھا۔
ایک اور اہم بات کہ اپنی علمی روایت کے احیاءکے لیے ایسے افراد ناگزیر ہیں جو پختہ ذہن کے حامل ، اپنی علمی روایت کا گہرا ادارک ، بڑوں پر کامل اعتماد ، وسیع مطالعہ اور تنقیدی نقطہ نظر کے حامل ہوں ۔ ایسے لوگ جن کا ذہن ناپختہ ، مطالعہ محدود ، تنقیدی ذہن سے عاری ، ہر کس و ناکس سے متاثر اور ہر علمی و فکری مسئلے پرفورا ایمان لانے والے ہوں ان سے علمی روایت کے احیاءکی امید نہیں لگائی جا سکتی اورایسے لوگ بجائے فائدے کے الٹا نقصان کا باعث بنتے ہیں ۔ ایسے لوگ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے اور کم از کم ایسے لوگوں سے کسی بہتری کی امیدنہیں کی جا سکتی۔ علمی روایت کا احیاءبڑا اہم کام ہے کہ اس میں مختلف ذہن کھپانے پڑتے ہیں اور ہر ذہن اپنی استعداد کے مطابق غور فکر اور تحقیق و جستجو کرتا اور کسی نتیجہ فکر تک پہنچتا ہے ۔یہ تحقیق و جستجو اور نتائج غلط بھی ہو سکتے ہیں لہذا صحیح نتائج کے ساتھ بعضوں کے گمراہ ہونے کا خدشہ بھی بدستور موجود رہتا ہے ۔ اس لیے اس کام کے لیے ایسے افراد کا چناو ناگزیرہے جو غیر معمولی صلاحیت کے حامل اورکامل درجے کا تنقیدی شعور رکھتے ہوں بصورت دیگر بجائے فائدے کے الٹا نقصان کا خدشہ ہے ۔
مولانا محمد تہامی بشر
بطور خاص جو چیزیں اس کورس میں شرکت کے بعد میرے غور و فکر کا حصہ بنیں، وہ یہ ہیں:
جدید سائنسی طرز فکر کے فہم انسانی پر عمومی غلبے کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کی ضرورت، اس طرز فکر کے شیوع سے مسلم تصور علم میں در آئی تبدیلی کا جائزہ، جدید علم کلام کی ضرورت و عدم ضرورت اور پھر عدم ضرورت کی صورت میں کسی بھی موقف کو جدید ذہنی شاکلے کے لیے قابل اطمینان علمی سطح پر پیش کرنے کی ضرورت۔
مجموعی طور پر اس کورس کی ڈسکشنز معلومات میں اضافے اور فکری افق کی توسیع میں مددگار ثابت ہوئیں۔علم سے متعلق سوفسطائی نظریے کی درست تفہیم میں مدد ملی۔ علامہ تفتازانی اور امام ماتریدی کے تصورات کو جدید فکری رجحانات و تناظرات میں رکھ کر سمجھنے میں مدد ملی۔ جدید افکار کے گہرائی سے مطالعہ کی ضرورت کا احساس بڑھا۔ تاریخ کے مطالعےمیں ابن خلدون کے اسلوب اور اس کے مغربی تصور تاریخ کے قریب تر ہونے کا علم ہوا۔یہ بھی مزید واضح ہوا کہ ہمارے روایتی دینی ادارے عالمی سطح پر چھائے ہوئے طرز فکر سے یکسر بے خبر ہیں۔
فائزہ حسین
مدرسہ ڈسکورسز کے تیسرے سمسٹر میں ہمیں سائنسی طریقہ کار کے بارے میں جاننے کا موقع ملا کہ کس طرح سائنسی تحقیق کا منہج ترتیب پاتا ہے اور کیوں سائنسی تحقیقات کبھی ایک جگہ کھڑی نہیں رہتیں بلکہ مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزرتی رہتی ہیں۔ مذہب کے ایک طالب علم کے طور پر ہمیں سائنس کے منہج کے بارے میں زیادہ جاننے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے میرے لیے یہ بہت مفید تھا کہ میں سائنس کی تاریخ کے بارے میں اور اس بارے میں جان سکوں کہ سائنسی تحقیق کیسے آگے بڑھتی ہے۔ ہمیں یہ جاننے کا موقع ملا کہ کسی بھی معاشرے کی سوچ ایک مجموعی سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے جو اس کے تجربات کی بنیاد پر ایک خاص شکل اختیار کرتی ہے، اگرچہ ہمیں اس کے داخلی طریقہ کار کا زیادہ تعارف نہ ہونے کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک خاص ترتیب سے، معاشرے کے خیالات اور اطوار سے متاثر ہوئے اپنا سفر طے کرتی ہے۔ اسی سے اسلامی علوم کے ارتقا اور نمو کے سفر کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ نگاہ میسر آیا۔
مروجہ طرز فکر میں تاریخ کوبہت ہی سطحی انداز میں دیکھا جاتا ہے۔ تاریخ کو سمجھنے کے لیے مختلف زاویوں سے اس کی پیچیدگیوں کو جانچنا ضروری ہے، کیونکہ تاریخ ہی ہے جہاں ہمارے تجربات، علوم اور علمی سفر محفوظ کیے گئے ہیں۔ سائنس اور تاریخ کے بارے میں علمی نظریات کو ایک وسیع تناظر میں دیکھنے سے یہ سمجھنے میں آسانی محسوس ہوتی ہے کہ چونکہ علوم کی ساخت ہی ایسی ہے کہ ان میں انسانی کوشش اور تحقیق کی مسلسل ضرورت رہتی ہے، اس لیے ہر دور میں مخصوص حالات کی بنا پر جو نظریات، مفروضے یا حقائق سمجھے گئے، ان سے بلاضرورت لگاو کی کیفیت پیدا نہ ہو۔
اگر ہم مذہب کا علمی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ بہت سے تصورات جنھیں ہم ابدی حقائق سمجھتے ہیں، وہ اپنے دور کی پیداوار ہونے کی وجہ سے ہمارے دور کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ علمی کمیونٹی کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ان سوالات کی جانب توجہ کرنا ہے تاکہ ہم نظریات کو ان کے تاریخی سیاق میں رکھ کر علمی تجزیہ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ مثلا صنفی عدم مساوات، غلامی، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت، جدید ریاست میں اقلیتوں کا مقام اور کردار، اور ان جیسے کئی دیگر مسائل۔ پیچیدگیوں کا حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک علم تک محدود نہ رہا جائے بلکہ دیگر علوم اور علمی روایات میں بھی نظائر تلاش کیے جائیں اور ان کے ذریعے سے فکر تازہ وجود میں لائی جائے۔
مولانا محمد رفیق شنواری
امریکہ کی ایک معروف کیتھولک یونیورسٹی، یونیورسٹی آف نوٹرے ڈیم میں اسلامیات کے پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم موسیٰ صاحب نے پاک و ہند کے دینی مدارس کے فضلاءکے لیے ” مدرسہ ڈسکورسز” کے عنوان سے ایک تین سالہ کورس متعارف کروایا ہے جو پچھلے سال شروع ہوا تھا اور آئندہ سال اختتام پذیر ہوگا۔
پروفیسر ابراہیم موسیٰ فلسفہ لسانیات کے متخصص ہیں اور اس باب میں ابتدائی دینی تعلیم مدرسے سے لینے کی بدولت اسلامی علوم اور تراث کے ساتھ ان کا گہراتعلق واضح طور پر ان کے کام میں محسوس ہوتا ہے۔ ان کے سامنے یہ حقیقت واضح ہے کہ اسلامی علوم و فنون کے کسی بھی پہلو پر کام تراث کے ساتھ مضبوط تعلق اور کامل فہم کے بغیر بہر صورت ادھورا ہوگا۔ اسی طرح پروفیسر صاحب یہ بھی جانتے ہیں کہ مدارس کا نظام تعلیم کئی اعتبار سے قابل نقد و اصلاح ہونے کے باوجود طلبہ کا تراث کے ساتھ گہرے فہم اور مضبوط گرفت کا رشتہ استوار کر دیتا ہے۔ انہی باتوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ مدارس میں پروان چڑھنے والی تراث فہمی کی ان صلاحیتوں کے لیے مغرب کے جدید اسلوب ِ تحقیق اور نقد و نظر کے نئے اور متعارف منہاج کے مطابق نشوونما کا موقع پیدا کیا جائے جو ممکن ہے مستقبل میں مغرب اور اسلام کے درمیان علمی وتہذیبی مکالمے کی بنیاد ثابت ہو۔
اس فکر کو عملی شکل دینے کے لیے ” مدرسہ ڈسکورسز” کے عنوان سے یہ پروگرام متعارف کرایا گیا جس کومالی طور پر امریکہ کا ایک مشہور ادارہ جان ٹمپلٹن فاونڈیشن سپورٹ کر رہا ہے۔ اس منصوبے کو عملی شکل دینے میں پروفیسر صاحب کو نوٹرے ڈیم یونیورسٹی کے رفقائے کار، خاص طور پر ڈاکٹر مہان مرزا کے علاوہ پاکستان سے مولانا عمار خان ناصر اور ہندوستان سے مولانا ڈاکٹر وارث مظہری کا تعاون بھی حاصل ہے۔ اس کورس کا دورانیہ تین سال رکھا گیا ہے جس کو چھ سمسٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہفتہ وار تدریسی سرگرمیاں آن لائن رکھی گئی ہیں اور استفادہ کو آسان بنانے کے لیے تدریس کے اوقات شام کے بعد رکھے گئے ہیں۔ نصاب کے طور پر علم کلام ، عقیدہ ، فلسفہ اور فلسفہ تاریخ کے اہم مباحث انتخاب کیا گیا ہے اور ان کی لیے کسی مخصوص کتاب کے بجائے مختلف مصنفین کی تحریریں منتخب کی گئی ہیں۔
سمسٹر کے آغاز میں ہمارے سامنے عمومی سولات رکھے گئے۔ بعد میں ان سوالات کا تفصیلی تعارف، طلبہ کی طرف سے اشکالات و جوابات کا سلسلہ اور بحث کے سمٹنے تک جزوی سوالات بھی شامل ہوتے گئے۔ یوں پورے سمسٹر میں زیر بحث آنے والے تقریباً تمام موضوعات کا ایک جامع خاکہ شرکاءکے سامنے آگیا۔ ہر پہلو سے متعلق شہرہ آفاق اور نہایت معتبر اصحابِ قلم کی کتابو ں کے منتخبات کو تدریسی مواد کے طور پر رکھاگیا۔ تدریس کی ذمہ داری پاکستان سے مولانا عمار خان ناصر، ہندوستان سے مولانا ڈاکٹر وارث مظہری صاحب اور یونیورسٹی آف نوٹرے ڈیم سے ڈاکٹر ماہان مرزا صاحب نے اٹھائی، جبکہ وقتاً فوقتاً ڈاکٹر ابراہیم موسیٰ بھی شریک گفتگو ہوتے رہے۔
کلاسز کا انتظام اس طور پر کیا گیا کہ ایک ہفتہ قبل ہمیں اگلی کلاس میں پڑھایا جانے والا مواد بھیج دیا جاتا اور کلاس کے مقررہ دن سے ایک یا دو دن پہلے پاکستانی طلبہ کے ساتھ مولانا عمار خان ناصر جبکہ ہندوستانی طلبہ کے ساتھ مولانا ڈاکٹر وارث مظہری ایک گھنٹے کی تیاری کی کلاس منعقد کرتے۔ اس میں ہر شریک اس مواد کو پڑھ کر کلاس میں شریک ہوتااور متن کی کسی مشکل کو سمجھنے کے لیے اپنا سوال استاد کے سامنے رکھ دیتا۔ کورس کی مرکزی کلاس شام سات بجے سے، درمیان میں عشاءکے لیے بیس پچیس منٹ کے وقفے کے ساتھ، رات دس بجے تک چلتی۔ یہ سب سے اہم اور بنیادی کلاس ہوتی جس میں پاک و ہند کے تمام شرکاءشریک ہوتے۔ اس کو دو یا تین حصوں میں تقسیم کر کے ہر استاد اپنا حصہ پڑھا دیتا اورآخر میں شرکا کے سولات کا جواب دیتا۔ مرکزی کلاس کے علاوہ طلبہ کی استعداد میں اضافہ کے لیے چند ذیلی سرگرمیاں بھی اس کورس کا حصہ ہیں۔ مثلاً شرکاءکو تین یا چار افراد پر مشتمل گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر گروپ، ہفتہ میں ایک دفعہ یونیورسٹی آف نوٹرے ڈیم کے کسی طالب علم کے ساتھ مخصوص موضوع پر انگریزی میں مکالمہ کرتا ہے۔ موضوع کا انتخاب اور متعلقہ مواد بذریعہ ای میل پہلے سے ارسال کر دیا جاتا ہے۔ ایک ہفتہ وار کلاس انگریزی زبان کے حوالے سے ہوتی ہے، جبکہ ایک کلاس تاریخ فلسفہ پر مبنی مشہور ناول Sophie’s World کو گروپ کی شکل میں مشترکہ طور پر پڑھنے کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔
اس کورس کا خاص پہلو سلیبس کی ترتیب وتدوین، تدریسی انداز اور عمل تعلم کو آسان سے آسان تر بنانے کے لیے اختیار کردہ حکمت عملی ہے۔ اولا کسی بھی موضوع سے متعلق نہایت اہم سوالات کا تعین ہوتا ہے۔ پھر ان سوالات کے جوابات کے لیے کسی ایک کتاب یا کسی ایک مصنف کو ہمیشہ پڑھتے رہنے کے بجائے نہایت مستند تحریروں کا انتخاب ہوتا ہے۔ ان منتخبات کو سمجھنے کے لیے الگ کلاس رکھی جاتی ہے۔ پھر استاد کے ساتھ پڑھنے اور تنقیدی جائزہ لینے اور اپنے سوالات پیش کرنے کے لیے الگ سیشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد مزید غور وفکر کے لیے طلبہ کے آپس میں مل بیٹھنے اور مذاکرے کا اہتمام ہوتا ہے۔ ان تمام مراحل میں بالکل بھی متوجہ نہ وہنے والے کے دماغ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور چپک جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پڑھانے کے انداز میں مسلسل تقریر اور محض لکھوانے کے بجائے مکالمہ اور طالب علم کو بولنے اور سوال پوچھنے کا موقع دینے کا اسلوب کافی موثر محسوس ہوتا ہے۔