جناب وحید مراد فرماتے ہیں کہ ”فلسفۂ تعلیم کی تاریخ میں ہمیشہ یہ سوال موجود رہا ہے کہ تعلیم کا مقصد “جاننا”ہے یا “ہونا (becoming)‘‘؟ جاننا معلومات کے حصول کا عمل ہے جبکہ ہونا انسان کے باطن میں اس علم کے سرایت کر جانے، کردار، شعور اور وجود کی تشکیل کا نام ہے۔ جدید دنیا نے صرف جاننے کو کافی سمجھا اور علم سے اپنی ذات کی تعمیر اور اپنے وجود کی گہرائی تک پہنچنے کے عمل کو کم اہم سمجھا“۔
میری رائے میں جناب وحید مراد کا یہ کہنا سادگی ہے کہ ”اسی لیے آج کا تعلیم یافتہ انسان زیادہ باخبر تو ہے مگر کم باشعور؛ اس کے علم میں وسعت تو آئی مگر اس کے ہونے میں وہ گہرائی پیدا نہ ہو سکی جو علم کو تجربے اور تجربے کو بصیرت میں بدلتی ہے۔“ تعلیم عامہ سے درکار واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے ایسے نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ علم میں صرف سوال اٹھانا فکر کی بے نسبی کو بڑھا دیتا ہے اور علم میں انتشار کا باعث ہوتا ہے۔ ایسا سوال جو علم کی نمو کا باعث بنتا ہے وہ موضوع سے متعلق ہوتا ہے اور اس کی توسیع اور گہریابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہمارے ممدوح محترم بنیادی موضوع کو طے کیے بغیر جو سوالات اٹھا رہے ہیں وہ زیادہ مفید نہیں ہیں۔ مثلاً اگر ہم عصر حاضر میں تعلیم عامہ (public instruction) کے عمل اور معنویت سے واقف ہوتے تو becoming کا سوال بھی بامعنی ہو جاتا۔ ممدوح محترم عصر حاضر میں becoming کے سوال کو تعلیم عامہ سے الگ دیکھ اور سمجھ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے قومی منظر نامے پر جو علم چھایا ہوا ہے وہ معاشرے میں cognitive dissonance کا اظہار ہے، اور جو قومی عمل سامنے آ رہا ہے وہ مکمل طور پر pathological ہے۔ اگر کوئی معاشرہ پاگل اور درندہ بیک وقت ہو جائے تو بقا کے امکانات معدوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
میں اس بات سے متفق ہوں کہ فلسفۂ تعلیم میں knowing اور becoming کے سوالات بہت اہم ہیں۔ لیکن جدید فلسفۂ تعلیم اور جدید تعلیمی نفسیات نے اس کا جو جواب دیا ہے اور اس کے حصول اور تحقق کے جو ذرائع پیدا کیے ہیں ان کو کیونکر نظرانداز کیا سکتا ہے؟ جاننے کا سوال تو عقلی، وقوفی اور فہمی ہے جبکہ becoming کا سوال اخلاقی اور وجودی ہے۔ becoming کا نقطۂ ماسکہ انسان کا باطن اور اس کی حریت ہے۔ یہ سوال انسان کی ایسی اخلاقی خودی (moral self) سے ہی ابھرتا ہے جو آٹونومی کی حامل ہو اور حریت سے متصف ہو کیونکہ اس کے بغیر انسان کے ایک مکلف مخلوق ہونے کا کوئی معنی باقی نہیں رہتا۔ becoming کا سفر انسانی باطن میں نمودار ہونے والے داعیے سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا راستہ/سانچہ اخلاقی اور روحانی اقدار ہیں۔ knowing کی جہت افقی جبکہ becoming کی جہت عمودی ہے۔ اسلام انسان کا ایک واضح تصور رکھتا ہے اور انسان کی پوری becoming اللہ کا عبد بننے کی سرگزشت ہے۔ becoming کا سوال قدری ہے، علمیاتی، فکری وغیرہ نہیں ہے۔ becoming ایک عملی جدوجہد ہے، تصوف میں اس عملی جدوجہد کا نام مجاہدہ ہے اور تعلیم عامہ میں اس کو کام (work) کہا جاتا ہے۔ مجاہدے اور جدید کام میں کوئی نسبتیں نہیں ہیں۔
مجاہدہ، کام اور becoming , یاد رہے کہ انسانی becoming انفس سے آفاق تک ہے۔ جو چیز انفس میں مجاہدہ ہے آفاق میں عین وہی چیز ج.ہا.د ہے۔ حضور علیہ الصلٰوۃ و السلام نے ج.ہا.د کو اسلام میں رہبانیت فرمایا ہے۔ انفسی توازن (balance) تزکیہ ہے جو مجاہدے سے قابل حصول ہے اور آفاق میں توازن عدل ہے جو ج.ہا.د کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ تعلیم عامہ بھی becoming کے انسانی سوال کو ہی اڈریس کرتی ہے لیکن اس سوال کی مکمل تقویم کو بدل دیتی ہے۔ روایتی تصوف اور تعلیم عامہ becoming کے دو تناظر اور جوابات ہیں۔ مذہبی تناظر میں becoming اخلاقی اور روحانی ہے، جبکہ تعلیم عامہ میں becoming سیاسی اور معاشی ہے، یعنی مکمل طور پر مادی ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہی غور کر لیا جائے تو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ organizational work مجاہدے سے کہیں زیادہ سخت اور گھلا دینے والا ہے۔ مجاہدے کا مطلب روح کی آبیاری اور فروغ ہے جبکہ جدید کام (modern work) چند ٹکوں کے عوض روح لیوا ہے۔ مجاہدہ اختیاری ہے جبکہ جدید کام مطلقاً جبری ہے اور غلامی سے بدتر ہے، اور ایک پیٹ کو بھرنے کے وسائل بھی فراہم نہیں کرتا۔
جدید ریاست becoming کی جائز انسانی طلب کو تعلیم عامہ کے ذریعے مکمل طور پر کھسوٹ (appropriate) لیتی ہے اور اسے مادی، یعنی معاشی بنا دیتی ہے۔ اس وقت ہمارے ہاں تصوف کے جو مظاہر ہیں اس میں سلوک کوئی ایجنسی نہیں رکھتا۔ یہ تعلیم عامہ کی مشین سے گزر کر اس کی شرائط پر ڈھلے ہوئے انسان کا تصوف اور سلوک ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں جو لوگ سلوک اور تصوف سے وابستہ ہیں وہ بنیادی طور پر تعلیم عامہ کی شرائط پر ڈھل کر اور اپنی کسی residual بے چینی کا حل ڈھوندھنے ادھر گئے ہیں، اور جس تصوف اور سلوک کے وہ پیروکار ہیں وہ بھی تعلیم عامہ کی شرائط پر بننے والا تصوف ہے، اور اسی باعث وہ اس قدر کریہہ المنظر ہے۔ تصوف انسان کو شریعت کی عطا کردہ اخلاقی اور روحانی اقدار پر ڈھالنے کا نام ہے۔ ایک ایسا انسان جو تعلیم عامہ کی شرائط پر ڈھل چکا ہو، اس کے تصوف اور سلوک کی تحقق سے کوئی نسبت باقی ہی نہیں رہتی۔ ایسے انسان کا تصوف اور سلوک بھی مکمل طور پر حصولی (acquisitive) ہی رہتا ہے کیونکہ تعلیم عامہ مادی سطح وجود پر ایک acquisitive society and individual ہی بنا سکتی ہے۔ اس تناظر میں آر ایچ ٹانی کی کتاب The Acquisitive Society دیکھ لینا مفید ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ صرف اس صورت میں مفید ہو سکتا ہے اگر مطالعۂ متن کا اسلوب تحقق پر مبنی ہو نہ کہ حصول پر۔ تصوف اہلِ تحقق و تحقیق کا شغل تھا، اب اہلِ حصول کی رزمگاہ ہے۔ جدید تصوف کی تمام وجودیات بازار کی شرط پر قائم ہے۔ اسی لیے تمام عبادات و وظائف کا مقصود بھی یہ دنیا ہے، کسی قدر وغیرہ کا تحقق نہیں ہے۔ جدید خارجی سیاسی اسلام اور حصولی تصوف ہماری تہذیب اور معاشرے میں جدیدیت کی شرائط پر سامنے آنے والے مظاہر ہیں، اور ان کی دینی اقدار سے نسبتیں نہایت موہوم ہیں۔
جناب وحید مراد کے خیال میں ”اہم سوال یہ نہیں کہ تعلیم کس کے ماتحت ہو، ریاست کے، مذہب کے یا فرد کے بلکہ یہ ہے کہ علم کا مقصد کیا ہو؟ کیا تعلیم محض شہری نظم کی بقا کے لیے ہے یا انسان کی اندرونی تکمیل کے لیے؟ جب تک یہ سوال واضح نہیں ہو گا، ہر نظامِ تعلیم خواہ سیکولر ہو یا مذہبی طاقت کے سانچے میں ڈھلا ہوا، آلاتی علم ہی رہے گا، جو انسان کو بہتر نہیں بلکہ زیادہ کارآمد بنانے میں مصروف ہے۔“
جیسا کہ میں نے ان پوسٹوں کے شروع میں عرض کیا تھا کہ جب تک ہست و باید کی گفتگو، یعنی تشخیص و تجویز، الگ الگ نہیں ہو گی، کار علمی لاحاصل رہے گا۔ یہ ضروری اس لیے ہے کہ ہست و باید اور تشخیص و تجویز فطری طور پر الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ علمی دلائل اور فکری اصالت وغیرہ کا نہیں ہے، امکانِ مکالمہ کا ہے۔ یہ سوال تو بہت اچھا اور مزے کا ہے کہ ”علم کا مقصد کیا ہو؟“ فرصت کے اوقات میں اس پر طبع آزمائی شاید پرلطف بھی ہو اور مفید بھی۔ ایسی تحریریں لکھی جاتی رہیں گی لیکن وہ کبھی مفید نہیں ہو سکتیں کیونکہ ان کا مشغلہ ”پس چہ باید کرد“ ہے۔ اسی باعث ہمارے ہاں سب تحریریں وعظ سے آگے نہیں جا سکی ہیں۔ جب تک ہست کے ”شدہ“ کا پتہ نہ چلے، باید کے ”کرد“ کا سراغ نہیں مل سکتا۔ کیا یہ بات سمجھنا دشوار ہے کہ ہمارے علوم کا ہمارے زندہ مسائل سے تعلق بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے؟
مثلاً ممدوح محترم کی کتاب بہت اچھی ہے اور انھوں نے اس پر کافی محنت کی ہے۔ لیکن تجزیہ اور تجویز اس وقت مفید ہوتے ہیں جب وہ خلا میں نہ ہوں بلکہ کسی واقعاتی حقیقت سے جڑے ہوئے ہوں۔ عقلی اور تجزیاتی علوم کا موضوع ہست ہے، اور اگر ہم elephant in the room کے ادراک سے قاصر رہیں تو پھر باقی کس بات کی اہمیت رہ جاتی ہے؟ میں مصنف کی اس بات سے متفق ہوں کہ رٹا کلچر عام ہے، لیکن یہی تو وہ تعلیمی کلچر ہے جو ریاست تشکیل دیتی ہے۔ وہ جب چاہے گی اس صورت حال کو تبدیل کر دے گی کیونکہ جبر و استحصال کا استمرار اس رٹا کلچر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔
ممدوح محترم ”جب تک“ کی شرط تو لگاتے ہیں اور یہ جاننے سے راضی نہیں کہ جدید عہد میں اہلِ اسلام ”علم کا مقصد“ معلوم بھی نہیں کر پائے تھے کہ جدید ریاست نے تعلیم عامہ کے آلاتی ذرائع سے ان کی ہر چیز کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ تعلیم عامہ کا علم انسان کو بہتر تو نہیں بناتا بلکہ اس کو ایک resource کے طور پر کارآمد بنانے میں مصروف ہے۔ ممدوح محترم کی یہ بات درست ہے لیکن اتنی معمولی بات معلوم ہونے کے بعد تجزیہ فوراً موقوف ہو جاتا ہے اور ججمنٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ججمنٹ کے بعد عمل کا مرحلہ ہوتا ہے اور ہمارے ہاں وہ عمل جھگڑے میں سامنے آتا ہے۔ مثلاً اگر ہم ان میں سے کسی سوال پر بات شروع کریں تو پھر فوری طور پر سوال اٹھایا جائے گا کہ تعلیم عامہ کیا ہوتی ہے اور جب تعلیم عامہ کو موضوع بنائیں تو پھر اس طرح کے غیرمتعلق سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت مشکل صورت حال ہے۔
علم کی گفتگو کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت جلد بکھر کر toxic ہو جاتی ہے اور جانبین کو معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ کون کیا بات کر رہا ہے؟ اگر ہمارا دستیاب علم یہ جاننے کے وسائل نہیں رکھتا کہ تعلیم عامہ کی واقعیت کیا ہے، اس کی وجودیات کیسے متعین ہوئی ہے، اور اس کی حرکیات کے گھیرے میں آیا ہوا انسان کن شرائط پر تشکیل پا رہا ہے تو ایسے علم سے دستبردار ہو جانا ہی بہتر ہے۔
جناب وحید مراد کی بات ابھی شروع بھی نہیں ہو پاتی کہ انھیں اوہام گھیر لیتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ ”یہ تمام گفتگو بالآخر چند اہم فکری سوالات اٹھاتی ہے۔ یہ سوالات صرف ریاست اور تعلیم کے باہمی تعلق کے نہیں بلکہ انسان، علم، شعور، مذہب، ریاست اور تہذیب کے باطن میں پوشیدہ رشتوں کی معنویت کے ہیں۔ مثلاً اگر تعلیم ریاستی سانچے سے آزاد ہو جائے تو کیا وہ اپنی اخلاقی و روحانی سمت برقرار رکھ سکے گی؟ کیا ریاست کے بغیر تعلیم کا نظم و ضبط بکھر نہیں جائے گا؟ یا مسئلہ ریاست کا نہیں، بلکہ تعلیم کے اصل مقاصد اور اس کی تہذیبی بنیادوں کی گمشدگی کا ہے؟ کیا جدید ریاست کو محض طاقت و سرمائے کا آلہ سمجھنا درست ہے یا وہ انسانی تجربے کے ایک طویل ارتقائی سفر کی منطقی صورت ہے؟ کیا مذہب اگر ریاست یا تعلیم کے اداروں میں شامل ہو جائے تو اپنی روح کھو دیتا ہے یا وہ اخلاقی توازن اور انسانی ضمیر کی صورت میں ان اداروں کو معنویت بخشتا ہے؟ کیا اسلام کی روح جدید ریاست کے ڈھانچے میں جذب ہو سکتی ہے یا ہمیں ہر نئے تجربے کو “شرعی” اور “غیر شرعی” خانوں میں بانٹ کر فکری جمود میں رہنا ہے؟ اور آخر وہ کون سا فکری و اخلاقی فریم ورک ہے جو تعلیم، ریاست اور مذہب تینوں کو باہم ہم آہنگ کر کے انسان اور سماج دونوں میں توازن پیدا کر سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے بغیر نہ تعلیم کی نئی تعبیر ممکن ہے نہ ریاست کی نئی تفہیم اور یہی وہ سوالات ہیں جن پر گفتگو ضروری ہے۔“
میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ ”بالآخر“ کہاں سے ٹپک پڑا۔ ابھی تو ”بالآغاز“ کا جنم ہی اٹکا ہوا تھا۔ میں تو منتظر تھا کہ وہ تعلیم عامہ کا بنیادی ترین سوال حل کر کے آگے چلیں گے۔ وہ ابھی متذبذب ہیں۔ جناب وحید مراد نے تعلیم عامہ سے متعلق، غیر متعلق اتنے سوال اٹھائے ہیں کہ ناطقہ سر بگریباں ہونا بھی بھول جاتا ہے۔ مثلاً وہ پوچھتے ہیں کہ ”کیا اسلام کی روح جدید ریاست کے ڈھانچے میں جذب ہو سکتی ہے یا ہمیں ہر نئے تجربے کو “شرعی” اور “غیر شرعی” خانوں میں بانٹ کر فکری جمود میں رہنا ہے؟“ میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی تعلیم عامہ اور جدید ریاست کی چولیں ٹھیک سے نہیں بیٹھ رہیں تھیں کہ ابوالسوال اور ام السوال بھی آ پہنچے۔ استعمار کی بدروح کے روبرو، اسلام کی روح کا سوال تو سید امیر علی نے اٹھایا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا بنا وہ تاریخ سے پوچھنا چاہیے، اور جہاں تک روح اور ڈھانچے کا تعلق ہے اس پر مفتی عبدالقوی صاحب سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ ابھی تعلیم عامہ اور ریاست کا مسئلہ ٹھیک سے سوجھا بھی نہیں تھا کہ معاملہ چیستاں بن گیا۔
جیسا کہ میں نے گزشتہ میں عرض کیا تھا کہ مسلم شعور میں association of ideas کا مسئلہ بہت گہرا ہے۔ بات جتنی بے سرو پا ہو گی، اتنا ہی وہ ذہنوں کو لبھائے گی، اور کسی موضوع پر مترتب بات کرنا لوگوں کو برانگیختہ کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اب اگر ممدوح محترم کے سوالات کو لکھ لیا جائے تو ہمارے علوم میں جاری انتشار کی ایک لاگ بک بن جاتی ہے۔ تعلیم عامہ ایک عملی نظام کے طور پر فرد اور معاشرے کا روزمرہ تجربہ ہے۔ اس پر ریاست اور عوام کے ہر روز اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ تعلیمی نتائج ہمارے معاشرے کی ساخت پر بتدریج اثرانداز ہوتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کو تیزی سے بدل رہے ہیں۔ پوری قوم، یعنی ریاست اور معاشرہ، تعلیم عامہ سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم ہیں کہ اس سے مکمل حالت انکار میں ہیں۔ اس واقعاتی نظام کی تفہیم کے ہم معمولی سے معمولی علمی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ہم ایک ایسے مظہر کو جو بہت حد تک حسی بھی ہے بیان کرنے پر قادر نہیں تو اسلام کی روح اور ریاست کے ڈھانچے کے ملاپ کا تجربہ بیان کرنے پر کیسے قادر ہو سکتے ہیں؟ علمی گفتگو کے نتیجہ خیز ہونے کے لیے اس کا شروع ہونا ضروری ہے۔
جناب وحید مراد نے اپنے اس پیراگراف میں تعلیم عامہ پر بھی جو سوال اٹھائے ہیں ان پر گفتگو بھی بے سود ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ سوالات کسی تفہیمی طلب سے پیدا نہیں ہوتے بلکہ ایک ایسی moral timidity کا اظہار ہیں جو کسی بھی فکری اور قدری پوزیشن لینے کو ناممکن بنا دیتی ہے۔ کیا تعلیم عامہ کا مسئلہ روح اور ڈھانچے کے ملاپ کے مسائل ہونے سے مشروط ہے؟ یہ اپروچ مفید نہیں۔ اگر ہم یہ طے کرنے بیٹھ جائیں کہ تعلیم عامہ پر گفتگو سے پہلے کون کون سے موضوعات پر گفتگو conclude ہونا ضروری ہے، تو کوئی علمی بات ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ انہدام شعور کے احوال میں ہمارے ہاں association of ideas کے جو اسالیب رائج ہو گئے ہیں اس میں ایسے موضوعات کی تعداد کروڑوں میں چلی جائے گی۔ اس طرح گفتگو کے آغاز و انجام کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ زیر بحث مکالمہ کوئی استثنا نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اب یہ ایک معمول ہے۔


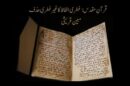















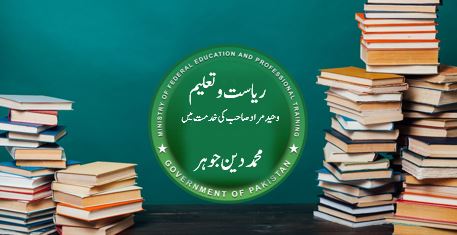



کمنت کیجے