یحیی بن ابی کثیر (م ١٢٩ ه) سے مروی ہے کہ سنت قرآن مجید پر قاضی ہے۔ قرآن مجید سنت پر قاضی کی حیثیت نہیں رکھتا۔ ان لفظوں سے متبادر مفہوم میں جو قباحت دکھائی دیتی تھی، اس کو محسوس کیا گیا اور ان کے شاگرد امام اوزاعی (م ١٥٧ ه) سے سوال کیا گیا۔ انھوں نے جواب دیا کہ قرآن مجید کو سنت کی (تفسیری) احتیاج سنت کو قرآن مجید کی (تفسیری) احتیاج سے زیادہ ہے۔ امام احمد بن حنبل (٢٤١ ه) تک جب قرآن و سنت کے باہمی تعلق کی یہ بحث پہنچی۔ تو یہ قول گویا ان سے بھی منسوب ہوگیا. انھوں نے ایسی ہر بات کو جسارت قرار دیا اور درست موقف کی نشان دہی فرمائی۔ انھوں نے فرمایا کہ درست موقف یہ ہے کہ سنت قرآن مجید کی تفسیر کرتی اور اس کی مراد کو بیان کرتی ہے۔ ابن عبد البر (م ٤٦٣ ه) سے جب امام اوزاعی کے موقف کے بارے میں سوال کیا گیا تو انھوں نے وضاحت کی کہ امام اوزاعی کہنا چاہتے تھے کہ سنت قرآن مجید کے بیان اور مراد پر قاضی ہے۔ یعنی جو سنت کہہ دے گی، ہم وہ مان لیں گے۔
شاید ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ سنت دینِ ابراہیمی کی حیثیت میں قرآن مجید پر مقدم ہے، مؤخر نہیں۔ ان کو دو وجوہات سے مسائل پیش آرہے تھے۔ ایک، یہ لوگ قرآن مجید کے الفاظ کو حاکم نہیں مانتے تھے اور دوسرے، سنت کو قرآن مجید سے مؤخر سمجھتے تھے۔ لہذا انھیں قرآن مجید کے ساتھ سنت کی تطبیق میں مسائل کا سامنا تھا۔ خالہ اور بھانجی کے ایک نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت قرآن مجید کے لفظوں ہی سے مبرہن تھی اور اس سے قرآن مجید کے ظاہر کی مخالفت کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن چونکہ یہ لفظوں کو حاکم نہیں مانتے تھے اور لفظوں کو اپنے مدعا کی ادائیگی میں کافی تصور نہیں کرتے تھے، لہذا وہ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ دوسرا وہ فطرت کی درست تقویم سے نا آشنا تھے۔ محرماتِ طعام فطرت ہی سے واضح تھے۔ اور قبل از قرآن ہی واضح تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انھیں فطرت کے حقائق کو دیکھنے میں دقت تھی۔ یہ وجہ ہے کہ ابن کثیر کے قول کی ظاہری قباحت کے باوجود ان سب کا اس پر اتفاق تھا کہ اس کے جوہر میں ایک ایسی بات ہے، جسے سمجھنے اور ماننے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ کہ سنت قرآن مجید کے لیے تبیین کے مقام پر فائز ہے۔ امام شافعی نے احتمالِ معنی کے اصول میں اس مسئلہ کو حل کرنا چاہا۔ امام شاطبی جو اصولوں کے لیے قطعی ہونے کی اٹل شرط کے قائل تھے، انھوں نے اسے تبیین کے اصول میں حل کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس بات پر یقینِ محکم رکھتے تھے کہ قرآن و سنت باہمی اختلاف کا محل نہیں ہوسکتے۔ لہذا تطبیق کا کوئی نہ کوئی رستہ موجود ہے۔ انھوں نے اسے دریافت کیا اور اسے نبھا کر بھی دکھایا۔
غامدی صاحب عربی زبان کے فہم میں یدِ طولی رکھتے ہیں۔ انھیں اپنے اساتذہ فراہی و اصلاحی کی پشت پناہی حاصل تھی۔ انھوں نے قرآن مجید کے مدعا کو اسی کے لفظوں ہی سے سمجھنے کا اصول وضع کیا۔ احتمالِ معنی کا پورا مبحث ان کے استاد کے الفاظ میں محض قلتِ علم یا قلتِ تدبر کا نتیجہ تھا۔ قرآن مجید محض ایک ہی تاویل کا احتمال رکھتا ہے اور وہ تاویل ہر نئی ریڈنگ میں مختلف ہو سکتی ہے۔ لیکن ہر ریڈنگ میں وہ تاویلِ واحد ہی رہے گی اور وہ تاویل جو بھی ہوگی، قطعی ہوگی۔ البتہ یہ معمہ اپنی جگہ حل طلب ہے کہ تعددِ تاویلات کا انکار خود تاویل کا انکار کیوں نہیں بنتا۔ متن خود کا بدل نہ ہو، تو تاویل کا اختلاف ہمیشہ ممکن رہتا ہے۔ جیسے عیسی علیہ السلام کے فوت ہونے اور اس طرح کے دوسرے مقامات پر اختلاف اسی مدرسہ کے اکابرین کے مابین ظاہر ہوا۔ یہ اختلاف لفظوں کے حاکم ہونے کے باوجود واقع ہوا۔ مدرسۂ فراہی میں قلتِ علم کا عارضہ تو شاید ممکن نہیں، یہ قلتِ تدبر کا شاخسانہ ہوگا۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ کے کرم سے متوفی کے معنی غامدی صاحب پر واضح ہوگئے، وگرنہ بہت گمراہی پھیلتی۔ (ایک جگہ کا قلتِ تدبر تو واضح ہوگیا، باقی کیا کچھ قلتِ تدبر کی نذر ہوا ہے، معلوم ہونا باقی ہے۔ لیکن فی الحال سب کچھ قطعی ہے۔ انتباہ: قلتِ علم کا اس مدرسہ میں کوئی دخل نہیں)۔ غامدی صاحب کا کمال یہ ہے جس کا اہلِ روایت کے پاس کوئی توڑ نہیں۔ وہ یہ کہ وہ دعوی ایسا کرتے ہیں، جو بہت grand ہوتا ہے اور جس میں لفظی زور زیادہ اور استدلال کم ہوتا ہے۔ جب وہ کسی ایسے دعوی پر کھڑے ہو جائیں ، تو ان کے ناقدین کس دلیل سے عدمِ دلیل کا مداوا کریں گے۔ مثلاً سنت کے تاریخی تقدم پر قیاس آرائیوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ملتِ ابراہیمی کی اتباع کے حکم کو سنت کے تقدم پر منطبق کرنا، یکسر سمجھ سے باہر ہے۔ ملتِ ابراہیمی کی اتباع کا حکم اس ملت کی اتباع کا حکم ہے، جسے وحی کے ذریعہ واضح کیا جا رہا ہے۔ یہ اتباع بعد از قرآن ہے۔ یعنی ملت ابراہیمی جسے بذریعہ وحی واضح کیا جا رہا ہے، اس کی اتباع کرو۔
غامدی صاحب کی فکر کو سمجھنا ہے، تو وہاں سمجھیں جہاں انھوں نے اسلاف سے اختلاف کیا ہے اور نئی رائے قائم کی ہے۔ مثال کے طور زکاۃ کے حکم کو انھوں نے سنت کی ذیل میں بیان کیا ہے۔ سنت اپنی سند اور اپنے حکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر انحصار رکھتی ہے۔ اس میں قیاس کو کوئی دخل نہیں۔ یعنی ہم نماز کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز کے اعمال پر قیاس کرتے ہوئے، نماز میں کچھ دوسرے امور کو بطور سنت داخل کردیں۔ غامدی صاحب نے زکاۃ کو بطور سنت قبول تو کیا، مگر قیاس و علت پر مبنی ایک پورا نظام سنت کی حیثیت میں خود اپنے تئیں اس میں داخل کردیا۔ یعنی خود شارع بن گئے۔ سنت کے باب میں اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی کہ یہ امت کے اجماع و تواتر کے خلاف ہے۔ جو امر اپنی سند میں اسلاف کے اجماع و تواتر پر مبنی ہو، اس کی خلاف ورزی پر کیا کوئی منطقی دلیل دی جائے گی۔ غامدی صاحب نے ایک جانب حدیث سے کسی بھی دینی حکم کے بطور سنت منتقل ہونے کو ممتنع قرار دیا اور خود سنت میں اپنے قیاسات کو داخل کردیا۔ محرماتِ طعام اوّلا قرآن مجید اور ثانیاً احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ غامدی صاحب نے ایک غلط استدلال کے تحت قرآن مجید کے محرمات کو فطرت پر ایک تتمہ کی حیثیت میں پیش کیا۔ پھر انھیں سنت میں داخل کردیا۔ یہ کونسی سنت یے، جس سنت کا آج تک پوری امت میں سے محض غامدی صاحب ہی کو انکشاف ہوا ہو۔ یہ علم بھی ان کی ربع صدی میں سے پہلے بیس سال گزرنے کے بعد ان پر آشکار ہوا۔ غامدی صاحب اصول و مبادی میں اجماع و تواتر کو سنت کی اولین شرط قرار دیتے ہیں اور پھر اپنے قیاسات سے سنت کی فہرست مرتب کرتے ہیں۔ ان کے اصولوں کی بنیاد محض تحکم اور زورِ کلام ہے۔ اور ان کی فقہ ان کے متفرد قیاسات۔ ہمارے اس دعوی کی دلیل دیکھنی ہو، تو سنت کی فہرست پر نظر دوڑائیں۔ سور، مردار اور خون کی حرمت کو سنت کی فہرست میں شامل کرنا تحکم نہیں، تو کیا یے۔ وہ حکم جو صریح نصِ قرآنی پر مبنی ہو، غامدی صاحب نے اپنے متفرد قیاس کی بنیاد پر اسے سنت میں شامل کردیا۔ یہ امورِ دینیہ میں تصرف نہیں، تو کیا ہے؟
ہماری علمی روایت تسلسل کا عنوان ہے۔ اس میں مسائل بھی ہماری توجہ کا مرکز ہیں اور ان مسائل سے نبرد آزما ہونے کی جدو جہد بھی۔ یحیی بن ابی کثیر کے بیانیہ کو جس ڈھنگ میں برتا گیا اور اس کی درست تاویل کی گئی، یہ ہماری روایت کا درخشاں باب ہے۔ غامدی صاحب جس روایت کے امین ہیں، اس کی عمر سو سال سے زیادہ نہیں۔ وہ چودہ صدیوں پر محیط روایت کو درخورِ اعتنا تصور نہیں کرتے۔ لیکن اس دم کٹی روایت کو سینہ سے لگائے بیٹھے ہیں۔اس سے ورا محض دورِ اول ہے، جسے وہ قابلِ اعتناء قرار دیتے ہیں۔ وہ ایک ہی جست میں بزعمِ خویش دورِ اوّل میں پہنچ جاتے ہیں۔ نظمِ قرآن کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گویا امام فراہی صدیوں کو پھلانگتے ہوئے اس وقت میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں قرآن مجید نازل ہورہا تھا۔ جو شخص اپنے بارے میں اس امکان کو درست سمجھتا ہو، وہ روایت کی اہمیت کو کیا سمجھے گا۔ دوسرا یہ کہ جس کے سامنے قرآن مجید نازل ہو رہا ہو، کیا اس کے فہم سے اختلاف ِکیا جاسکتا ہے۔ اس کے فہم میں تفہیم کم اور اذعان زیادہ ہوگا۔ غامدی صاحب نے محض نئے جوابات فراہم نہیں کیے، انھوں نے سوالات کو بدلا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ سوالات بدلے بغیر نئی تعبیرِ دین کی جگہ پیدا نہیں کی جاسکتی۔ دین کیا ہے، دین کی حقیقت اور اس کے مقاصد کیا ہے، وغیرہ جیسے سوالات۔ قرآن مجید کا میزان و فرقان ہونا، نظمِ قرآن کا مسئلہ، قرآن مجید کا سرگزشتِ انذار ہونا، سنت کا قرآن مجید سے مقدم ہونا، دین کے قطعی ہونے کا مبحث، حدیث اور سنت کا امتیاز، سنت کا محض متواترات تک محدود ہونا، قرآن مجید کے فہم میں literalism پر اصرار وغیرہ۔ یہ سوالات دستیاب اور حاضر جوابات سے عدم اطمینانی کو ظاہر تو کرتے ہی ہیں، مگر یہ ان جوابات کی طرف بھی نشاہدہی کرتے ہیں، جن کی طلب ماحول میں موجود ہے۔ غامدی صاحب کی مقبولیت کی وجہ ان کے علمی کام سے باہر اور خارج میں پائی جاتی ہے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ غامدی صاحب پر تنقید آسان اور تردید مشکل ہے۔ تنقید اصول، دلیل اور استدلال پر مشتمل ہوتی ہے۔ لیکن تردید مقبولیت کے معدوم ہونے سے جڑی ہے۔ غامدی صاحب کی مقبولیت کا امتحان ان کے دین میں تفردات نہیں، کیونکہ وہ انھی تفردات کی بنا پر مقبول ہیں۔ ان کی مقبولیت کا امتحان وہ مقامات ہیں، جہاں وہ اپنی کسی مجبوری کے تحت روحِ زمانہ کے برخلاف کوئی موقف اختیار کرتے ہیں۔ ان کے بیان کی قوت ہو یا استدلال کی صحت، ان کے مخاطبین انھیں سننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ غامدی صاحب نے لوگوں کو guilt سے آزادی دی ہے اور ان کی پاپولیرٹی کی یہی وجہ ہے۔
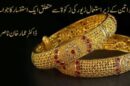
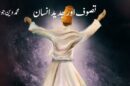
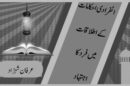
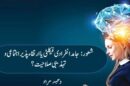














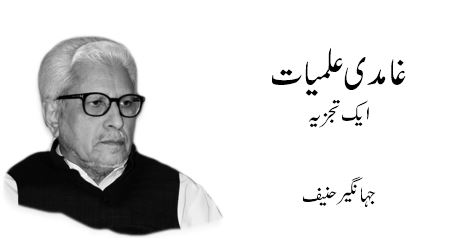



کمنت کیجے