ریاست کی “اعتباری شخصیت” کی حقیقت اور ہمارے بعض مفتیانِ کرام کی غلط فہمیاں :
پہلے قانون میں “شخص” اور “شخصیت” کے مفہوم پر غور کریں۔ جان سالمنڈ کی اس تعریف کو بالعموم قانون دانوں نے قبول کیا ہوا ہے:
A person is any being whom the law attributes a capability of interests and, therefore, of rights.
(شخص کوئی بھی ایسا وجود ہے جسے قانون مفادات کی ، اور اسی بنا پر، حقوق کی اہلیت عطا کرے۔)
مشہور قانونی فلسفی Dias نے ذرا زیادہ بہتر قانونی ترکیب استعمال کی تو یہ تعریف پیش کی:
Person means a unit of jural relations.
(شخص سے مراد حقوق و فرائض سے متعلق امور کی اکائی ہے۔)
اس تعریف میں jural relations (حقوق و فرائض سے متعلق امور )سے مراد ہے:
A multitude of claims, duties, powers, liberties and immunities treated as a single unit.
(دعاوی، فرائض، اختیارات، آزادیوں اور استثناءات کے مجموعے کو جب ایک اکائی کے طور پر مانا جائے۔)
اسی jural relations کو قانون کی زبان میں personality (شخصیت) کہتے ہیں۔
قانون کی نظر میں “شخص” دو طرح کے ہیں: انسان ،جسے natural person (قدرتی شخص) کہا جاتا ہے؛ اور fictitious person، (اعتباری شخص) جیسے کارپوریشن، ریاست اور اس طرح کے دیگر فرضی وجود۔
اس fictitious person یا شخص اعتباری کے لیے قانون درج ذیل عناصر ضروری سمجھتا ہے:
1۔ کوئی وجود ( corpus)؛ لیکن ہر corpus شخص نہیں ہوسکتا، جیسے پارٹنر شپ فرم، جب تک دیگر عناصر بھی اس کے ساتھ شامل نہ ہوں؛
2۔ اس وجود کے انتظام کے لیے “ذہن” (mind)، جیسے کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز؛
3۔ اس corpus اور mind کو تب تک شخص نہیں مانا جاسکتا جب تک قانون اسے “شخصیت” عطا نہ کردے۔
یہ شخصیت عطا کرنا، یا نہ کرنا، قانون کا مطلق اختیار ہے۔ قانون چاہے تو انسان سے شخصیت چھین لے، جیسے رومن لا میں غلام کو شخص (person) کے بجاے مال (property) سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح قانون چاہے تو کسی غیر انسانی وجود، بلکہ فرضی وجود، کو شخصیت عطا کردے، جیسے کمپنی۔
قانون نے عموماً تین طرح کے “غیر انسانی وجود” کو شخصیت عطا کی ہے:
1۔ کارپوریشن؛
2۔ ادارہ، جیسے یونی ورسٹی؛ اور
3۔ فنڈ۔
کارپوریشن کی طرف آئیے تو اس کی دو قسمیں ہیں:
Corporation Sole: اس سے مراد ایک فرد کے بعد اس کی جگہ لینے والے افراد کو ایک ہی شخص تصور کرنا ہے، جیسے انگریزی دستوری نظام میں کہا جاتا ہے
The king is dead; long live the king!
(بادشاہ مرچکا؛ بادشاہ زندہ باد!)
اس تصور کےتین بڑے فوائد ذکر کیے جاتے ہیں:
1۔ عہدے اور اس کے قانونی اثرات کا تسلسل؛
2۔ پچھلے فرد کے فیصلوں کا بعد کے افراد پر نفاذ؛ اور
3۔ عہدے کی ملکیت اور فیصلوں کا امتیاز ذاتی ملکیت اور فیصلوں سے۔
کارپوریشن کی دوسری قسم Corporation Aggregate کہلاتی ہے جس کے ذریعے کئی افراد کے مجموعے کو ایک شخص فرض کرلیا جاتا ہے۔ کمپنی اسی قسم کی مثال ہے۔
اس تصور کے بھی کئی فوائد ذکر کیے جاتے ہیں، جیسے:
1۔ ایک گروہ کے تمام افرادکو ایک اکائی ماننا ایک قدرتی بات ہے؛
2۔ گروپ/اکائی کی شناخت کو افراد کی شناخت سے ممیز رکھنا مفید ہوتا ہے؛
3 ۔ اس طرح بے تحاشا transaction costs (تصرفات پر اٹھنے والے اخراجات) میں کمی آجاتی ہے؛ یہی اس تصور کا سب سے بڑا فائدہ سمجھا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس تصور کو جدید دنیا کے لیے ناگزیر قرار دیا جاتا ہے؛
4۔ اس کے نتیجے میں بہ آسانی “محدود ذمہ داری” (Limited Liability) وجود میں آجاتی ہے!
5۔ ٹیکس کی مد میں کارپوریشن/کمپنی کو بعض وہ فوائد مل جاتے ہیں جو پارٹنرشپ فرم کو میسر نہیں ہوتے۔
شخص اور شخصیت کا مفہوم سمجھ میں آگیا ہو، تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس Corporation aggregate کےلیے اسلامی قانون کے جو نظائر پیش کیے جاتے ہیں کیا وہ واقعی اس تصور کے نظائر ہیں یا وہ اس سے یکسر مختلف ہیں؟
بیت المال کو “شخص اعتباری” کہنا قطعی غلط ہے
بیت المال کو شخص اعتباری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والے نے نہ تو شخصِ اعتباری کا مفہوم درست سمجھا ہے، نہ ہی بیت المال یا وقف کے احکام کی درست تطبیق کی ہے۔
قانون میں “شخصیت” کے تصور کی تفصیل پچھلی پوسٹ میں دی گئی۔ اس تصور کا اسلامی اصولوں کے ساتھ موازنہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اصول فقہ میں اس کے قریب ترین تصور “ذمۃ ” کا ہے۔
ذمہ سے مراد وہ عہد ہے جو انسانوں نے اپنے پروردگار سے کیا ہے۔ اسی عہد کی بنیاد پر اسلامی قانون نے انسان کو خطابِ شارع کا مستحق قرار دیا ہے اور پھر اسی خطابِ شارع کے نتیجے میں اس کو مکلف مانا ہے۔
بہ الفاظِ دیگر، اس عہد کے نتیجے میں انسان کو “اہلیت” حاصل ہوگئی۔ یہ اہلیت، جیسا کہ معروف ہے، دو طرح کی ہے: اہلیتِ وجوب، جس کے نتیجے میں انسان کو حقوق و فرائض حاصل ہوتے ہیں؛ اور اہلیتِ ادا، جس کےنتیجے میں وہ ان حقوق و فرائض کی ادائیگی کا اہل ہوجاتا ہے۔
اہلیتِ وجوب کے لیے مناط، یعنی بنیاد، “انسان ہونا ” ہے؛ جبکہ اہلیتِ ادا کے لیے مناط “عقل ” ہے۔ پس غیر انسان کے لیے نہ ذمہ ہے، نہ اہلیتِ وجوب۔
اسی لیے اصولیین بتاتے ہیں کہ اگر کسی مادی وجود کے لیے فرض بھی کیا جائے کہ وہ عقل رکھتی ہے، تب بھی اس کے لیے ذمہ تسلیم نہیں کیاجاسکتا۔
یہ وہ قانونی تصور ہے جو فقہاے اسلام نے قرآن و سنت پر غور و فکر کے بعد بہت تفصیل کے ساتھ وضع کیا ہے۔ اس تصور میں اعتباری شخصیت کے لیے کوئی گنجایش نہیں ہے۔
جو مفتیانِ کرام وقف یا بیت المال کو شخص اعتباری کی نظیر کے طور پر پیش کررہے ہیں، انھی سے پوچھیے کہ کیا فقہائے کرام نے کہیں بیت المال کے لیے “ذمہ ” مانا ہے؟ جن حقوق اور فرائض کو بعض اوقات بظاہر بیت المال کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، دراصل وہ تمام مسلمانوں کے حقوق و فرائض ہوتے ہیں اور چونکہ بیت المال پر تمام مسلمانوں کی ملک مشترک ہوتی ہے، اس لیے ان حقوق کی ادائیگی کے لیے بیت المال کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔
مثال کے طور پر کسی شخص نے قتلِ خطا کیا اور اس کی عاقلہ نہیں ہے، تو دیت کی ادائیگی کے لیے بیت المال کی طرف رجوع کیا جائے گا کیونکہ تمام مسلمان اس شخص کا عاقلہ ہیں۔
اسی طرح کسی شخص کا کوئی وارث نہیں ہے، تو تمام مسلمان اس کے وارث ہیں اور اس لیے اس کا ترکہ بیت المال میں جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام “ریاست” نامی فرضی شخصیت کے بجائے “حکمران ” کی بات کرتے ہیں۔ ریاست، جسے بین الاقوامی قانون نے شخص مانا ہے، تمام وسائل کی مالک ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اسلامی قانون کی رو سے تمام وسائل پر مسلمانوں کی ملکِ مشترک (co-ownership) ہوتی ہے اور حکمران ان co-owners کے وکیل (agent)کے طور پر ان وسائل میں تصرف کرتا ہے۔ یوں یہ دو یکسر الگ نظام بن جاتے ہیں۔
مثلاً اگر ریاست کو اعتباری شخص مانا جائے تو پھر جو حدیث میں آیا ہے کہ لوگ تین چیزوں میں شریک ہیں، اس کی کوئی گنجایش باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح “سرکاری خزانہ” ریاست کی ملکیت ہوگی جس کی وجہ سے “شبھۃ الملک ” کی بنا پر “بیت المال ” سے چوری پر حد کی سزا ساقط ہونے کا جزئیہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ مزید برآں، دفینہ یا دیگر وسائل اگر کسی فرد کی ذاتی ملکیت میں بھی دریافت ہوجائیں، تو وہ ریاست نامی شخص کی ملکیت ہوتے ہیں اور اسی لیے معادن اور رکاز میں خمس کے متعلق تمام جزئیات بھی دریابرد کرنی پڑیں گی۔ اسی طرح کسی شخص کی دیت بھی سرکاری خزانے سے ادا نہیں کی جائے گی کیونکہ سرکاری خزانے کو تمام مسلمانوں کی نہیں، بلکہ ریاست نامی شخص کی ملکیت تصور کیا جائے گا اور اس شخص کا پہلے شخص سے جب تک موالات کا عقد نہ کیا جائے تب تک اس کے مال سے اس کے جرم کی دیت ادا نہیں کی جاسکے گی۔ اسی طرح کسی لاوارث شخص کا ترکہ سرکاری خزانے میں کیوں جائے گا؟
مزید آگے بڑھیے۔ پھر ہم ریاست نامی شخص کو ٹیکس کیوں ادا کریں؟ یہ ٹیکس تو بھتہ ہوجائے گا جب تک اس شخص کے ساتھ ہم کوئی باقاعدہ معاہدہ نہ کریں جس کی رو سے ہم اسے ٹیکس دینے کے پابند ہوں اور وہ بھی جواب میں ہمارے لیے کچھ کرنے کا پابند نہ ہو۔ اسی لیے بعض لوگوں نے ریاست کے وجود میں آنے سے قبل ایک “عمرانی معاہدہ” بھی فرض کیا ہے، یعنی مکھیوں پر مکھیاں مارتے جائیں، ایک مفروضے کے پیچھے ایک اور مفروضہ اور پھر ایک اور مفروضہ۔
بیت المال اور وقف کو “شخص اعتباری” کہنا کیوں غلط ہے؟
ممتاز عرب عالم الخیاط نے وقف کو شخص اعتباری ماننے کے لیے سب سے مضبوط کیس بنایا۔ بعد کے لوگوں نے انھی کے دلائل کو اپنے الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔
خیاط کے موقف کا خلاصہ یہ ہےکہ وقف کا ناظر (caretaker/administrator) وقف کے لیے دَین لے سکتا ہے جو وقف کے فوائد (جنھیں اصطلاحاً “غلۃ” کہا جاتا ہے ) سے ادا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر یہ ناظر تبدیل کیا جائے اور اس کی جگہ کسی اور شخص کو ناظر مقرر کیا جائے، تو دَین کا مطالبہ پچھلے ناظر کے بجاے نئے ناظر سے کیا جائے گا جو اسے وقف کے غلہ سے ادا کرے گا۔ اس سے خیاط نے یہ استنباط کیا کہ گویا حقوق اور فرائض وقف کے ہی ہیں اور اس طرح وقف ایک “شخصِ اعتباری ” ہوگیا!
یہ موقف کئی غلط مفروضات پر قائم ہے، نہ صرف وقف کے متعلق بلکہ شخص اعتباری کے تصور کے متعلق بھی!
پہلے وقف کی طرف آئیے۔
وقف ہے کیا چیز؟ لغوی طور پر تو وقف کا مطلب ہے “روک دینا”، لیکن یہاں کیا روکنا مراد ہے؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ “عین کو واقف (وقف وجود میں لانے والے) کی ملکیت پر روک دیا جائے” (حبس العین علی ملک الواقف)۔ صاحبین کا موقف اس کے برعکس یہ ہے کہ “عین کو حکماً اللہ تعالیٰ کی ملکیت پر روک دیا جاتا ہے” ( حبس العین علی حکم ملک اللہ)۔
اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ملکیت کا روک دینا، کہ آگے اس کی منتقلی کسی صورت نہ ہو، جیسا کہ وقف کی جانے والی عین کے بارے میں قاعدہ ہے کہ: لا تباع، و لا توھب، و لا تورث (نہ اسے بیچا جاسکتا ہے، نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے، نہ ہی وہ کسی کو میراث میں مل سکتی ہے)، تو یہ شریعت کے عام قواعد کے خلاف ہوا۔ عین کی ملکیت کی آگے منتقلی ہی اصل قاعدہ ہے۔ اسی لیے وقف کو “خلاف القیاس” کہا جاتا ہے۔
دوسری بات یہ ہےکہ وقف کے فوائد جن لوگوں کو ملیں گے، یعنی “موقوف لھم” (beneficiaries)، ان فوائد کے بدلے ان پر اس وقف کو پہنچنے والے نقصانات کی ذمہ داری اٹھانے کا فریضہ بھی عائد ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ فائدہ اٹھائیں اور نقصان کے لیے ذمہ دار نہ ہوں تو یہ فائدہ ربا ہوجائے گا! قاعدہ یہی ہے کہ: الخراج بالضمان(کسی مال سے آپ تبھی فائدہ اٹھاسکتے ہیں جب اس کو پہنچ سکنے والے نقصان کی ذمہ داری بھی آپ اٹھائیں)۔ چنانچہ جس طرح آپ کا خادم یا غلام آپ کو فائدہ دیتا ہے، تو اس خادم یا غلام کا خرچہ بھی آپ کو اٹھانا پڑتا ہے، اسی طرح موقوف لھم جب وقف سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو عین موقوفہ کا خرچہ اور عین موقوفہ کو پہنچنے والے نقصان کی ذمہ داری اٹھانے کا فریضہ بھی ان پر عائد ہوتا ہے۔ (والعین بمنزلۃ الخادم والعبد، لان الخراج بالضمان، وصار کنفقۃ العبد۔)
تیسری بات یہ ہے کہ ناظر کی حیثیت موقوف لھم کے وکیل (agent) کی ہے۔ اب وکالت کے متعلق حنفی فقہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وکیل جب کوئی چیز خریدتا یا فروخت کرتا ہے، تو تیسرا فریق براہ راست اصیل (principal)سے مطالبہ نہیں کرسکتا، نہ ہی اصیل براہ راست تیسرے فریق سے مطالبہ کرسکتا ہے، بلکہ تیسرا فریق بھی وکیل سے اور اصیل بھی وکیل سے مطالبہ کرے گا، اگر چہ ملکیت تیسرے فریق سے اصیل کو اور اصیل سے تیسرے فریق کو منتقل ہوجاتی ہے۔ اسے عقد کے “حقوق” اور “حکم ” میں فرق کہتے ہیں۔ یہاں حکم سے مراد ملکیت کی منتقلی ہے اور حقوق سے مراد عقد پر عمل درآمد (performance) ہے۔ چنانچہ تیسرا فریق خواہ مطالبہ وکیل سے کرے لیکن اصل ذمہ دار اصیل ہی ہوتاہے، اور وکیل ادائیگی اصیل کے مال سے ہی کرے گا۔ پس یہاں بھی اگر عین موقوفہ پر کوئی دَین لیا گیا ہے، تو خواہ مطالبہ ناظر سے کیا جائے، ادائیگی موقوف لھم کے مال، یعنی عین موقوفہ کے غلہ، سے ہی کی جائے گی (واقرب اموالھم ھذہ الغلۃ)۔ توجہ رہے: “موقوف لھم کے مال، یعنی عین موقوفہ کے غلہ سے”، نہ کہ وقف نامی کسی شخص اعتباری کے مال سے!
چوتھی بات یہ ہے کہ غلہ جس سے یہ نقصان پورا کیا جاتا ہے، موقوف لھم کی ملکیت ہوتا ہے اور عین موقوفہ یا وقف کا جزو نہیں ہوتا۔
پانچویں بات یہ ہے کہ نئے ناظر سے مطالبہ عقدِ حوالہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور دَین پہلے ناظر سے دوسرے ناظر کی طرف منتقل ہوجاتا ہے۔
آخری بات یہ ہے کہ متقدمین فقہائے کرام تو کیا، متاخرین نے بھی تصریح کی ہے کہ وقف کا ذمہ نہیں ہوتا!
“وقف کا ذمہ نہیں ہوتا “کا مطلب آسان الفاظ میں یہ ہے کہ وقف کے پاس قانونی شخصیت نہیں ہوتی؛ وقف شخص نہیں ہے!
لیجیے، علامہ شامی سے سن لیجیے:
اما الوقف، فلا ذمۃ لہ؛ والفقراء، و ان کانت لھم ذمۃ، لکن لکثرتھم لا تتصور مطالبتھم؛ فلا یثبت الا علی القیم۔
(جہاں تک وقف کا تعلق ہے، تو اس کا ذمہ نہیں ہوتا؛ جن فقرا کے فائدے کےلیے مال کو وقف کیا گیا ہے ان کا ذمہ ہوتا ہے، لیکن ان کی کثرت کی وجہ سے ان سے مطالبے کا تصور نہیں کیا جاسکتا؛ اس لیے دین صرف قیم (ناظر) پر ہی ثابت ہوتا ہے۔)
مجھے معلوم نہیں کہ اس تصریح کے بعد کیسے یہ دعوی کیا جاسکتا ہے کہ فقہائے کرام کے ہاں وقف کو شخص اعتباری مانا گیا ہے!
باقی رہی یہ بات کہ خیاط اور دیگر علماے کرام جو وقف کو شخص اعتباری سمجھتے ہیں وہ شخص اعتباری کے تصور کو ہی غلط سمجھ رہے ہیں، تو اس کی وضاحت کئی دفعہ کی گئی کہ شخص اعتباری اسے نہیں کہتے کہ حسابات میں آسانی کی خاطر آپ تین افراد کو ایک تصور کرلیں؛ بلکہ اسے کہتے ہیں کہ ایک وجود کو وہ صلاحیت مل جاتی ہے جس کی رو سے اس وجود کو قانونی حقوق مل جاتے ہیں اور اس پر قانونی فرائض عائد ہوجاتے ہیں۔ اس مفہوم میں وقف کو کبھی شخص اعتباری نہیں کہا جاسکتا، نہ ہی اسلامی فقہ و اصول کے تراث میں اس تصور کی کوئی اور مثال پائی جاتی ہے۔
ھذا ما عندی، والعلم عند اللہ۔
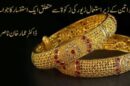
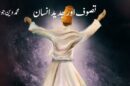
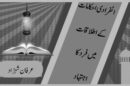
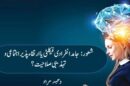















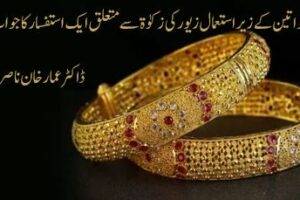
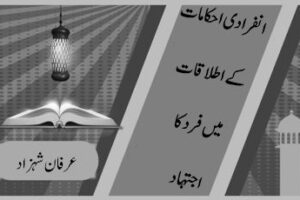
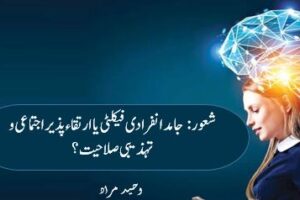
کمنت کیجے