میں جناب وحید مراد کا ازحد ممنون ہوں کہ انھوں نے تعلیم پر میری مختصر تحریر کو موضوع بنایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ”تاہم ان کے طرزِ مکالمہ میں ایک پہلو قابلِ غور ہے کہ وہ اکثر اپنی پوسٹس پر ہونے والے تبصروں یا سوالات پر گفتگو نہیں فرماتے۔ یہ طرزِ عمل علمی مکالمے کے فروغ میں رکاوٹ بنتا ہے کیونکہ جب فکر سوال اور تنقید سے محروم ہو جائے تو وہ مکالمہ نہیں رہتی، بیانیہ بن جاتی ہے“۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ ”ایک اور پہلو یہ ہے کہ ان کے نقطۂ نظر کو مزید واضح انداز میں سامنے آنا چاہیے۔ وہ کن مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ ان کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اور ان کے ممکنہ حل کی سمت کیا ہو سکتی ہے؟ ان کی اکثر تحریریں ان سوالات کو ابھارتی ضرور ہیں مگر ان کے جوابات فراہم نہیں کرتیں۔ قاری جب فکری ابہام کے ساتھ متن سے باہر نکلتا ہے تو مکالمہ ادھورا رہ جاتا ہے۔“
جناب وحید مراد نے اپنی تحریر میں بے شمار اور بہت اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ مجھ میں ان سوالات کا بیک آن جواب دینے کی سکت اور استعداد نہیں ہے۔ میں نے ان سوالات کی فہرست بنا لی ہے اور آئندہ کئی ہفتوں کی عرضِ تمنا کا سامان ہو گیا ہے۔ اصل میں مکالمہ مابینی ہوتا ہے اور فیس بک پر ہر مکالمہ چومکھی ہو جاتا ہے۔ چومکھی مکالمے کے لیے گتکا آزما ہونا ضروری ہے جو میں نہیں ہوں۔ بہرحال میں ممدوح محترم کے سوالات کا جواب دینے کی بساط بھر کوشش کروں گا۔ اگر بیچ میں احباب میں سے کسی کا کوئی استفسار ہوا تو اسے بھی شامل کر لوں گا۔ لیکن اب ناک کی سیدھ چل کر ہی ان سوالات کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ میں کسی بحث میں پڑے بغیر ان کے ارشاد کے بالمقابل اپنی رائے عرض کر دوں گا۔
جناب وحید مراد کا یہ گلہ بھی بالکل بجا ہے کہ میں مکالمے میں شریک نہیں ہو پاتا۔ اس کی وجہ نخوت و اعراض وغیرہ نہیں ہے بلکہ میرے نجی حالات ہیں جن کا بار بار ذکر کرنا مجھے بدمذاقی معلوم ہوتا ہے۔ یعنی یہ کوتاہی کسی صائب عذر کے سبب ہے۔ اس کے علاوہ اس کی قطعی کوئی دوسری وجہ نہیں ہے، اور الطافِ کریمانہ کے ہاں عذر ہمیشہ قابل قبول ہوتا ہے۔ ارشادِ مزید میں انھوں نے جو فرمایا ہے میں اس سے بھی متفق ہوں۔ اس حوالے سے میری تحریروں میں جو مسائل ہیں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ میری رائے میں ہر گفتگو اور تحریر ادھوری ہوتی ہے اور ہر آدمی اپنی مختصر تحریر میں صرف ایک آدھ بات ہی بیان کر سکتا ہے اور اس سے جڑی بہت سی باتیں ان کہی رہ جاتی ہیں جو کسی دوسرے وقت میں کسی اور تحریر میں اظہار پاتی ہیں۔ اپنی بات کے مکمل اظہار کے لیے کتاب لکھنی پڑتی ہے جس کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔
ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اردو کے پورے کلچر میں متن سازی اور متن خواندگی کے جو اسالیب رائج ہیں میں اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے ان سے بخوبی واقف ہوں، اور مجھے ان سے سخت وحشت ہے اور میں بساط بھر ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تحریروں کو ہست و باید (is and ought) کے دو بڑے زمروں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ اردو کی زیادہ تر تحریریں باید (ought) کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہاں ہر آدمی ناصح، مصلح، مفکر، مسیحا اور بعض اوقات مداری (جہلم کی اقلیم علم کو یاد کریں) وغیرہ بن کر گفتگو کرتا ہے۔ میں ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں اور نہ مجھے ان سے کوئی نسبت ہے۔ اٹھارھویں صدی کے بعد سے ہمارے سب مفکرین و مصلحین باید کے لاؤڈ اسپیکر لیے چنگھاڑ رہے ہیں یہاں تک کہ گوشِ نصیحت نیوش ہی جاتا رہا ہے۔ یہ لوگ اب تک اتنے حل پیش کر چکے ہیں کہ ان کا ہمالیہ سا اٹھ آیا ہے، اور جو ہماری تدمیر میں کام آیا ہے۔ باید کی تحریریں تذکیر، وعظ اور تواصی وغیرہ سے متعلق ہوتی ہیں اور فرد کی اصلاح کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ حالات کی بھینس پر اس بین کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مجھے فی الحال ہست (is) میں دلچسپی ہے، کیونکہ نئی تاریخ کے ہست نے ہمارے باید کو ہمارے معاشروں اور شعور سے بے دخل کر دیا ہے۔ جب دوست بہت زور دیتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر وہ میرے باید کو جاننا چاہتے ہیں تو مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم الاسلام دیکھ لیں۔ وہ میرے اس باید کا بیان ہے جسے نئی تاریخ نے بالفعل بے دخل کر دیا ہے۔ باید کے بارے میں میرا موقف یہ ہے کہ نامعلوم ہے اور نہ گمشدہ ہے۔ میرا مسئلہ نئی تاریخ کے ہست سے ہے تاکہ اپنے باید کے لیے جگہ بنانے اور اس جگہ بنانے کے اسالیب جان سکوں۔ مجھے حیرت ہے کہ احباب یہ سادہ سی بات کیوں نہیں جان پاتے کہ ہر تجزیۂ ہست کی قوت محرکہ کسی نہ کسی باید سے وابستگی ہی سے فراہم ہوتی ہے اور جس کو چلا چلا کر بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ پھر یہ جاننا بھی اہم ہے کہ باید ہدایت کا اعلان ہے جبکہ ہست خاص الخاص فکر و علم اور تجزیے کا موضوع ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں ہم نے گزشتہ تین سو سال میں جو علوم پیدا کیے ہیں انھوں نے ہمارے ہست کو نابود اور ہمارے باید کو شاید کر دیا ہے۔ جب تک ہم علوم میں ہست و باید کی تمیز متعارف نہیں کراتے، اندھیرے چھٹنے والے نہیں ہیں۔
جناب وحید مراد ارتقا وغیرہ کی بات بھی کرتے ہیں جو تاریخ اور فطرت میں کارفرما ایک اضطراری عمل ہے جس کو مغرب نے telos دینے کی کوشش بھی کی ہے۔ میں تاریخ اور فطرت کے اس اضطراری عمل کو موضوع نہیں بنانا چاہتا اور نہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی ہے۔ میں خالص سائنسی اور حیاتیاتی بنیادوں پر ارتقا کو رد کرتا ہوں، اور نظریۂ ترقی کو مغرب کا عقیدہ خیال کرتا ہوں۔ میں فی الحال اس فضول بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں تاریخ میں مسلم ایجنسی کے احوال کو جاننے کی تگ و دو میں ہوں۔ میں صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر مسلمان اپنے باید کے ساتھ جدید انسان سے ہم کلام ہونا چاہے تو اس کے اسالیب کیا ہو سکتے ہیں اور اگر وہ جدید تاریخ کے ہست کا سامنا کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ میرا ایجنڈا بہت محدود ہے اور میں اسی میں رہ کر ہی کوئی گزارش کر سکتا ہوں۔
جناب وحید مراد فرماتے ہیں ”حالیہ تحریر میں یہ واضح نہیں کہ علم کی سماجی تنظیم کس بنیاد پر قائم ہو گی؟ اگر تعلیم کو انڈسٹری کے بجائے سماجی خدمت بنایا جائے تو اس کا معاشی ماڈل کیا ہو گا؟ کیا تعلیم ریاست کے بغیر بھی مؤثر رہ سکتی ہے؟ حقیقی تعلیم کی اخلاقی اور روحانی تشکیل کس طرح ممکن ہے؟ اور کیا موجودہ نظامِ تعلیم صرف ریاستی کنٹرول کا نتیجہ ہے یا انسانی سماج کے فطری ارتقاء کا حصہ؟“
گزارش ہے کہ کسی موضوع پر عدمِ کلام سے کوئی چیز واضح نہیں ہوتی، صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ عدمِ کلام ہے۔ اگر میری گزارش میں ”علم کی سماجی تنظیم“ زیر بحث ہی نہیں تو اس عدمِ کلام سے وضاحت کا مطالبہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے لیکن مذکورہ تحریر سے خارج ہے۔ مکالمہ اسی وقت مفید اور پیداکار (productive) ہوتا ہے جب ایک موضوع پر رہا جائے اور اس کو پھیلانے کی جستجو کی جائے۔ بنیادی موضوع تعلیم عامہ کا ہست ہے، اور ہست کا بھی صرف ایک پہلو۔ یعنی تعلیم عامہ کی isness پر بات ہو رہی ہے کہ تعلیم عامہ خواہ مذہبی ہو یا سیکولر، وہ ریاست کے اختیار اور legal regime سے باہر سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اور اسی پہلو سے تعلیم عامہ کی ساخت اور معنویت متعین ہوتی ہے۔ اگر کوئی شاعر کسی شاگرد کو اصلاح دے رہا ہے یا علم عروض کے نکات سمجھا رہا ہے یا کہیں وعظ ہو رہا ہے یا کہیں پاس انفاس جاری ہے تو وہ بھی میرے موضوع سے خارج ہیں کیونکہ وہ تعلیم عامہ سے فی الوقت غیرمتعلق ہیں۔ بار بار یہ بھی عرض کرنا پڑتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غیر اہم ہیں بلکہ صرف یہ کہ اس وقت زیر بحث نہیں ہیں۔ اگر ”علم کی سماجی تنظیم“ پر بات ہونی ہے تو ضرور ہونی چاہیے۔ لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ فی الوقت یہ زیر بحث نہیں، اس لیے خلط مبحث ہے۔
اہم بات یہ ہے کہ تعلیم عامہ کے بارے میں میری گزارش درست ہے یا غلط ہے۔ میں تعلیم عامہ یا ریاست پر کوئی ججمنٹ بھی نہیں دے رہا۔ میں تو صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تعلیم عامہ واقعاتی طور پر کیا ہے؟ اس کے اچھے برے ہونے پر اور ریاست پر ہزاروں ججمنٹیں دی جا سکتی ہیں اور ہزاروں ہزار مقالے بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن وہ باید کا مسئلہ ہیں اور فی الوقت وہ بھی میرے موضوع سے خارج ہیں۔ میری گزارش کے درست یا غلط ہونے سے تعلیم کے بارے میں بنیادی ترین بات معلوم ہو جائے گی، پھر اس میں بندہ اپنی مرضی سے چاہے جتنی مرضی ضمنیاں ڈال لے۔ اگر بنیادی بات پر ابہام ہے تو میری رائے میں ساری بحث لاحاصل رہتی ہے۔ اب یہ سوالات ہو سکتے ہیں کہ تعلیم عامہ میں اخلاق کیسے جاری ہو سکتا ہے؟ تعلیم عامہ میں روحانیت کی کیا حیثیت ہے؟ تعلیم عامہ میں رٹہ کلچر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تعلیم عامہ میں علم کی سماجی تنظیم کے اصول کیا ہیں؟ تعلیم عامہ میں استاد کی ایجنسی کیونکر بحال ہو سکتی ہے؟ علیٰ ہذا القیاس۔
ہست پر گفتگو کا اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ اخلاقی اور نظریاتی ججمنٹ کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ بار بار یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کا مطلب ان کا غیراہم ہونا نہیں ہے۔ ہست پر گفتگو کے بغیر اخلاقی اور نظریاتی وعظ قطعی تضیع اوقات ہے اور ایک لغو مشغلہ ہے۔ اگر تعلیم عامہ کے ہست پر گفتگو کے ذریعے بنیادی بات طے ہو جائے تو ایک جہان معنی کا در وا ہو جاتا ہے۔ اگر تعلیم عامہ کی واقعاتی صورت حال وہی ہے جو میں نے عرض کی ہے تو پھر یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ تعلیم عامہ میں تبدیلی بھی سیاسی ذرائع سے ہی لائی جا سکتی ہے جس میں ہم اپنے باید کی رعایت رکھتے ہوئے تعلیم عامہ کی ریاستی ساخت کو متعین کر سکتے ہیں۔ مثلاً جناب وحید مراد سوال اٹھاتے ہیں کہ ”اگر تعلیم کو انڈسٹری کے بجائے سماجی خدمت بنایا جائے تو اس کا معاشی ماڈل کیا ہو گا؟“ اس سوال کا جواب بھی پہلے سوال سے جڑا ہوا ہے۔ ان کا یہ سوال کہ ”کیا تعلیم ریاست کے بغیر بھی مؤثر رہ سکتی ہے؟“ سادہ خیالی پر مبنی ہے۔ اگر تعلیم عامہ ریاست سے مشروط ہے تو یہ سوال ہی بامعنی نہیں ہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ ”حقیقی تعلیم کی اخلاقی اور روحانی تشکیل کس طرح ممکن ہے؟“ موجودہ تعلیم عامہ بھی ”حقیقی“ یعنی actual اور real ہے، یعنی واقعاتی طور پر موجود ہے، کوئی افسانوی یا طلسماتی چیز نہیں ہے۔ پوری قوم ریاست کے متعین کردہ اس فعل اور عمل میں ہمہ وقت شریک ہے۔ اگر ریاست چاہتی ہے کہ تعلیم عامہ کی اخلاقی اور روحانی تشکیل ضروری ہے تو وہ مجاز ہے اور ایک سیاسی فیصلے سے ایسا کر سکتی ہے اگر اس کو دستیاب علم اس کا کوئی راستہ سجھا دیتا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن صرف یہ عرض ہے کہ تعلیم عامہ صرف اس صورت میں اخلاقی اور روحانی ہو سکتی ہے جب اس کی ایجنسی استاد ہو۔ ادارہ جاتی تعلیم عامہ میں یہ عناصر داخل نہیں کیے جا سکتے۔
جناب وحید مراد کا یہ سوال مجھے بہت دلچسپ لگا کہ ”کیا موجودہ نظامِ تعلیم صرف ریاستی کنٹرول کا نتیجہ ہے یا انسانی سماج کے فطری ارتقاء کا حصہ؟“ جدید جامعات میں ایسے ایسے انہونے موضوعات پر ڈاکٹریاں کرائی جاتی ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ڈاکٹری کرانے کے لیے اچھا موضوع ہے۔ اس طرح کے سوال پیدا ہی اس وقت ہوتے ہیں جب ہم حاضر و موجود سے، جو ہمارا ہست ہے، اس سے تعرض کرنے سے انکار کر دیں۔ اصل مسئلہ چور پکڑنا ہے۔ یہ تفصیلات کہ وہ کہاں رہتا ہے، کل شام اس نے کیا کھایا اور پہنا تھا، اس کو اپنی والدہ محترمہ سے ملے ہوئے کتنے دن گزر گئے تھے، اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، اس کا بچپن کہاں کہاں گزرا، اگر والدین نے اس کے ختنے کرائے تھے تو یونیورسٹی کو اسے ڈاکٹری کرانی چاہیے تھی تاکہ وہ فطرت میں نقب لگا کر سائنسی راز سامنے لاتا اور معاشرے کا ایک مفید کارکن بنتا، اس بات کا کتنا امکان ہے کہ اس کی اپنی بیوی سے لڑائی نے چوری کے فعل میں فیصلہ کن کردار کیا ہو، کیا اس کی بیوی پر فیمی نسٹوں کے اثرات ہیں یا نہیں، چور کی نانی اماں کا انتقال اگر صرف ساڑھے تین سال تاخیر سے ہوتا تو چوری کے امکانات پر کیا اثرات مرتب ہوتے، کیا چور ناظرہ پڑھا ہوا تھا یا نہیں، اس بات کا کتنا امکان ہے کہ مولوی صاحب کی شفقت میں کمی کی وجہ سے وہ چور بن گیا ہو، کیا وہ تعلیم عامہ کے سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا یا نجی سکول میں، ہو سکتا ہے استاد صاحب کے ڈنڈوں نے اس کو چوری کی طرف مائل کیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ چور کے بارے میں اس طرح کے سیکڑوں سوالات ہیں جن سے ایک پوری کتاب مرتب ہو سکتی ہے اور ان سوالات کے جواب پر اگر ڈاکٹریاں کرائی جائیں تو ایک پوری لائبریری بھی بن سکتی ہے۔ میں یہ انکار نہیں کر رہا کہ یہ سوالات بہت اہم ہیں۔ یہ سوالات ڈاکٹریوں کے لیے نہایت مفید ہیں، اور ان کا جواب دینے سے بہت سے وجودی اور تہذیبی سوالات کا جواب مل سکتا ہے۔ لیکن مجھے فی الحال ان میں ذرہ بھر دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے صرف یہ دلچسپی ہے کہ تعلیم عامہ کے عمل کو سمجھنے میں غلطی سے بچا جائے تاکہ اس عمل کو اپنے باید کے مطابق بنانے کی جدوجہد کا آغاز کیا جا سکے۔
جناب وحید مراد کے خیال میں ”یہ بات درست ہے کہ تعلیم ریاستی اور سیاسی فیصلوں سے متاثر ہوتی ہے مگر اسے صرف “ریاستی آلہ” قرار دینا اس کے وسیع تر سماجی و تہذیبی پہلو کو محدود کر دیتا ہے۔ تعلیم صرف قانون یا سرمایہ نہیں یہ سماجی شعور، ثقافتی اظہار اور انسانی ارتقاء کا عمل بھی ہے۔ ریاست اس کا نظم فراہم کرتی ہے مگر علم کی تخلیق انسان کے باطن سے جنم لیتی ہے اور انسانی سوال کسی سیاسی فیصلے کا تابع نہیں ہو سکتا۔“
تعلیم اور تعلیم عامہ دو قطعی مختلف چیزیں ہیں اور ان کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کی جا سکتی ہے، ایسی رائے جو عقل اور تجزیے کے تابع ہو اور امر واقعہ کو ظاہر کرتی ہو، ایسی رائے جو پسند نا پسند پر بنیاد رکھتی ہو، ایسی رائے جو آدمی کے ثقافتی، معاشی اور سماجی حالات سے پیدا ہوئی ہو، ایسی رائے جو آدمی کے مزاج اور مفاد کی رعایت سے قائم کی گئی ہو، ایسی رائے جو مزعوماً کسی مذہبی تعلیم کے موافق ہو وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب آرا کسی نہ کسی درجے میں درست ہوں گی۔ لیکن جب ہم تعلیم عامہ کے ہست کو زیربحث لا رہے ہیں تو محولہ بالا آرا ممکن نہیں رہتیں۔ اب ہمیں ایک ”صورت حال“ درپیش ہے جو میری رائے یا عدم رائے سے قطعی غیرمتعلق اور آزادانہ موجود ہے۔ اول ضرورت اس کو معروضی طور پر سمجھنا ہے۔ یعنی یہ اپنی یا کسی کی رائے کے اظہار کا موقع ہے ہی نہیں۔ لیکن اس واقعاتی صورت حال کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ اس صورت حال میں اپنے عمل اور حصولِ عمل کو بہتر بنایا جا سکے یا اگر اس صورت حال کو تبدیل کرنا ضروری ہو تو اس میں اپنے باید کے مطابق کوئی تبدیلی لائی جا سکے۔
میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ ریاست تعلیمِ عامہ کی وجودیات کی معرّف (definer) ہے۔ ریاستی فیصلے سے باہر کسی قسم کی کوئی تعلیم عامہ کوئی وجود ہی نہیں رکھتی۔ جب میں وجودیات کہتا ہوں تو اس سے مراد اس تعلیم عامہ کا پورا فلسفہ اور تصور، اس کا واقعاتی نظام، اس نظام کو چلانے والا مکمل legal regime، اس نظام میں سامنے آنے والا عمل، اس پورے نظام کے مقاصد، اور اس میں واقع ہونے والے ہر عمل کا استناد، اس نظام میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کام کرنے والے افراد اور ان کی معیشت وغیرہ سب ریاست کے فیصلے کے نتیجے میں وجود پاتے ہیں۔ تعلیم عامہ کی گاڑی جس لائن پر سفر کرتی ہے وہ ریاست کی ہی بچھائی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں تعلیم اور تعلیم عامہ کا ہر پہلو جیسا ہے ویسا اس لیے ہے کہ اس کی وجودیات ریاست کے فیصلے نے متعین کی ہے اور تعلیم عامہ کی تمام سماجی، ثقافتی اور علمی حرکیات (dynamics) اسی کے اندر رہتے ہوئے سامنے آتی ہے۔
میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تعلیم عامہ ریاست کے فیصلوں سے متاثر ہوتی ہے۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ تعلیم عامہ مکمل طور پر ریاست کا بنا کردہ، پیدا کردہ فعل و عمل ہے۔ یہ اپنے تصور، وجود اور عمل میں مکمل طور پر ریاست کی طے کردہ ہے۔ تعلیم عامہ جدید ریاست کے فلسفۂ انسان، اس کے سیاسی اور معاشی ایجنڈے اور اس کی تیارکردہ پالیسی کی پیداوار ہے۔ تعلیم عامہ کا ”ریاستی آلہ“ ہونا اس کے وسیع تر سماجی اور تہذیبی پہلو کو محدود نہیں کرتا بلکہ ریاست کا ایجنڈا اور پالیسی اس کی تحدیدات قائم کرنے ہی کا نام ہے۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ”تعلیم سماجی شعور، ثقافتی اظہار اور انسانی ارتقا کا عمل بھی ہے“۔ لیکن یہ شعور، یہ ثقافت اور یہ ارتقا جدید ریاست کے سیاسی فیصلے کی نمود ہے اور تعلیم عامہ میں اسی قدر موجود ہو سکتے ہیں جس قدر جدید ریاست ان کی اجازت دیتی ہے اور ان کی منصوبہ بندی کرتی ہے۔
یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ ”ریاست اس [تعلیم عامہ] کا نظم فراہم کرتی ہے۔“ کیونکہ تعلیم عامہ ریاستی فیصلے سے قائم ہونے والے ایک وسیع تر نظم ہی کا نام ہے۔ تعلیم عامہ اور جدید ریاست کی واقعاتی مابینی نسبتوں کا ادراک اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس elaborate legal regime کو نہ دیکھ لیا جائے جو جنگ آزادی سنہ ۱۸۵۷ء کے بعد تشکیل پانا شروع ہوا اور اب تک توسیع پذیر ہے۔ میں تصور تعلیم، تعلیمی کمیشن، کریکیولم، نصاب، پیڈاگاجی، آموزش، امتحان اور استناد سے سیکڑوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں جو بلاشک و شبہ یہ بات ثابت کر دیتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ہجے بھی ریاستی ترجیحات سے ہٹ کر نہیں پڑھا سکتے۔ ابھی گزشتہ دنوں ریاست نے طے کیا کہ سرکاری سکولوں کے پرنسپل صاحبان کسی سے گلدستہ وصول نہیں کر سکتے۔ اب یہ کتنی معمولی بات ہے لیکن ریاست ساورن مجاز ہے کہ وہ تعلیم عامہ کے اندر بننے والی معاشرت پر بھی قانون سازی کرے۔ میں یہ تو بات ہی نہیں کر رہا کہ یہ درست ہے یا غلط۔
جناب وحید مراد فرماتے ہیں ”مگر علم کی تخلیق انسان کے باطن سے جنم لیتی ہے اور انسانی سوال کسی سیاسی فیصلے کا تابع نہیں ہو سکتا۔“ ہو سکتا ہے ”انسان کے باطن سے تخلیق“ پانے والے کوئی کشفی یا عرفانی علوم ہوں جن کی طرف محترم ممدوح اشارہ فرما رہے ہیں۔ میں دانستاً موجودہ بحث کے فکری اور فلسفیانہ پہلوؤں سے گریز اپنائے ہوئے ہوں۔ ہمارے ہاں قائم تعلیم کی ادنیٰ درجے میں بھی کوئی تفہیم پیدا نہیں ہو سکتی اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ تعلیم عامہ کا پورا طلسم جدید ریاست کا شعبدہ ہے۔ ممدوح محترم جس ”باطن“ کا ذکر فرما رہے ہیں، جدید ریاست کے نزدیک وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، یعنی اخلاق اور روحانیت سے سینچے جانے والا کوئی انسانی باطن ریاستی پالیسی اور منصوبے کے ریگزاروں میں سرے سے قابل ادراک اور قابل اظہار ہی نہیں ہے۔ ہاں نفسیاتی معنوں میں، جدید ریاست انسان میں ایک غبار نما داخلیت (subjectivity) ضرور ڈھونڈ لیتی ہے جو سر تا سر ایک plasticity کی حامل ہے، اور جدید ریاست اپنے آموزشی اور استنادی وسائل سے اس داخلیت کو مکمل طور پر اپنی مادی ترجیحات پر ڈھالنے کا کام کرتی ہے۔
مجبوراً عرض کر رہا ہوں کہ اگر تعلیمی نفسیات کی وضع کردہ بلوم اور سولو ٹیکسانومی کا ”درست تناظر“ میں مطالعہ کر لیا جائے تو اس طرح کے غیرمتعلق سوالات سے آدمی بچ جاتا ہے۔ ٹیکسانومی بنیادی طور پر تو زمرہ بندی کا نام ہے لیکن تعلیمی نفسیات میں یہ انسان کی ذہنی اور نفسی داخلیت کی تعیین اور ان کی تشکیل نو کے وسائل کو زیر بحث لاتی ہے۔ یہ ٹیکسانومی ایک خاص تصور انسان کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ تعلیمی نفسیات کی وضع کردہ ٹیکسانومی اصلاً انسان کی داخلیت کو ہی موضوع بناتی ہے اور تدریس اور آموزش کے نئے وسائل سے اس داخلیت کے ساتھ efficient اور workable نسبتوں کو قائم کرتی ہے۔ ”تصدیق بالقلب“ جس انسانی باطن یا قلب میں واقع ہوتا ہے وہ ٹیکسانومی کا موضوع نہیں ہے۔ ٹیکسانومی کا موضوع وہ داخلیت ہے جسے آرگنائزیشن کے مادی ذرائع سے ایک خاص سانچے میں ڈھالا جا سکے۔
انسانی انفس کے پانچ بڑے اجزا ہیں جن کو جدید داخلیت کے تصورات کے بالمقابل جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ حافظاتی، نفسی، وقوفی، خیالی اور روحانی ہیں۔ تعلیمی ٹیکسانومی نفسی اور وقوفی داخلیت کو زیر بحث لاتی ہے۔ پوری ٹیکسانومی حافظے کی شدت سے مخالفت کرتی ہے، اور تعلیمی عمل کو اس پر مرکوز کرنے کے خلاف ہے اور اسے رٹا سسٹم قرار دیتی ہے۔ جدید ریاست زبان، عدد اور تخلیق کے تدریسی وسائل سے نفسی اور وقوفی داخلیت کی مادی تشکیل پر مکمل قادر ہو چکی ہے۔ سادہ لفظوں میں، حافظہ یادوں کا گھر ہے اور انفس میں اس کی حیثیت وہی ہے جو معاشرے میں تاریخی عمل سے بننے والے اجتماعی حافظے کی ہے جسے روایت کہتے ہیں۔ تعلیم عامہ تخلیق کی آڑ میں انسانی حافظے کو فنا کر چکی ہے، اور جدید انسان اپنے انفس کے ریگزار میں گم ہو کر شدید نفسیاتی بحران کا شکار ہو گیا ہے۔ فی زمانہ نفسیاتی مسائل کی بڑی وجہ جدید انسان کے حافظے کی تدمیر ہے۔ انفس کا نفسی منطقہ psychic ہوتا ہے اور جذبے، اخلاق اور معنی کے حضور کی آماج گاہ ہے، جبکہ وقوف عقلی کارگزاری کا محل ہے۔ جدید تعلیم معنی کے حضور کا خاتمہ کر کے، اسے ایک ہیئت بنا کر ذہن میں منتقل کر دیتی ہے۔ انسانی انفس میں سب سے زیادہ plasticity رکھنے والا منطقہ نفس ہے اور اخلاقی خودی کی تشکیل اور تزکیے کا ایک محل ہے۔ تنظیمی اتھارٹی کے ذریعے جس ڈسپلن کو نافذ العمل بنایا جاتا ہے وہ انسان کی نئی نفسی تشکیل ہی کا نام ہے جو مکمل طور پر disciplinary اور مادی ہے۔ انفس انسانی میں وقوف کی اہمیت مرکزی ہے، اور جدید تدریسی اور آموزشی وسائل کے ذریعے عقل انسانی کی قدر سے نسبتوں کا مکمل انقطاع واقعاتی طور پر قائم کر دیا جاتا ہے۔ تعلیم عامہ کی پیدا کردہ عقل مکمل طور مفاد اور تکاثر کے تابع ہوتی ہے۔ خیال ایمان کا محاط ہے، اور روحانی منطقہ معنوی اور کشفی تجلی کا محل ہے۔ جدید تعلیمی اور ٹیکنالوجیائی وسائل کی آندھی سے خیال (imagination) مکمل طور پر اٹ جاتا ہے اور ایمانیات کا محل بننے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ جدید تعلیم کی لائی ہوئی خیال کی dehumanization سے جلد یا بدیر آرٹ اور مذہب کا ویسے ہی خاتمہ ہو جاتا ہے۔
جدید تعلیمی ٹیکسانومی کے نزدیک طبعی فطرت کی طرح، انسانی داخلیت بھی ایک ایسا طبعی resource ہے جسے quantify کیا جا سکتا ہے اور تدریس اور آموزش کے ٹیکنیکل وسائل کے ذریعے سیاسی طاقت اور سرمائے کے لیے مفید مطلب بنایا جا سکتا ہے۔ تعلیم عامہ یہی کام کرتی ہے۔ یہاں ایسے کسی باطن کا سراغ نہیں ملتا جو کسی علم کے حصول اور تخلیق پر قادر ہے۔ جدید تعلیم انسان میں نفسی آٹونومی کا بھی مکمل خاتمہ کر دیتی ہے۔ جدید انسان کا پیدا کردہ علم ویسا ہی ہے جیسا کہ چیٹ جی پی ٹی پیدا کر رہی ہے۔
جناب وحید مراد فرماتے ہیں ”طاقت کے زاویے سے یہ تجزیہ اپنی جگہ درست ہے مگر اس میں تعلیم کے مثبت پہلو مثلاً مقصد، اخلاق، تخلیق اور حریت فکر کی وضاحت نہیں کی گئی۔ تعلیم عامہ کا اصل ہدف کیا ہے؟“
گزارش ہے کہ نہایت مختصر تحریر میں تو صرف ایک آدھ بات ہی کہی جا سکتی تھی جو میں نے عرض کی تھی۔ تعلیم اور تعلیم عامہ سے جڑے ہوئے سیکڑوں ایسے سوالات ہیں جن کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ تعلیم عامہ کے اصل ہدف اور اس میں مقصد، اخلاق، تخلیق اور حریتِ فکر کی حیثیت کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس مقصد کے لیے بشمول پاکستان دنیا کے کسی بھی ملک کی وضع کردہ تعلیم عامہ کی پالیسی اور منصوبے کو دیکھ لینا کافی ہے کیونکہ دنیا بھر میں تعلیم عامہ کا طریقہ ایک ہی ہے۔ یہ کوئی خفیہ چیز تو ہے نہیں۔ جناب وحید مراد ارتقا کو کافی پسند کرتے ہیں اور برصغیر پاک و ہند میں انیسویں صدی کے آغاز سے تعلیم عامہ کا قیام اور ”ارتقا“ جاری ہے اور اس کے مقاصد، طریقۂ کار اور اہداف سب بیان کر دیے گئے ہیں، اور یہ کسی خفیہ ایجنسی کی فائلوں میں تو موجود نہیں، بلکہ تعلیم عامہ پر کتابوں سے لائبریریاں بھری پڑی ہیں۔ تعلیم عامہ پر سب باتیں وہاں بیان کر دی گئی ہیں۔ اس وقت بھی ہمارا ہر ادارہ اپنی وجودیات اور حرکیات میں مکمل ترین استعماری افکار و اعمال پر قائم ہے اور کام کر رہا ہے اور ہم سب اسی کی پیداوار ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہاں تعلیم عامہ کی بحث ہے ہی نہیں کیونکہ اس کے لیے موضوع پر رہتے ہوئے گفتگو کو مکمل کرنا پڑتا ہے۔ میری رائے میں اصل سوال صرف یہ طے کرنا ہے کہ تعلیم عامہ ایک سیاسی فیصلہ ہے۔ اگر وہ سیاسی فیصلہ ہے تو گفتگو کا تناظر اور ہو گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو گفتگو کا تناظر بدل جائے گا۔ باقی ہر سوال اس بنیادی سوال سے جڑا ہوا ہے۔ جس طریقے سے جناب وحید مراد سوال در سوال لکھ رہے ہیں میرے نزدیک بنیادی سوال طے کیے بغیر ان کی کوئی خاص افادیت نہیں ہے۔
جناب وحید مراد بات جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تعلیم عامہ ”انسان کو آزاد کرتی ہے یا محض نظم و ضبط کے تابع رکھتی ہے؟ کیا تعلیم عامہ ریاست کی خدمت کے لیے ہے یا انسان کی تکمیل کے لیے؟“ میرے رائے میں یہ اہم ترین سوالات ہیں۔ لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ عقلِ انسانی شاید ان کا جواب تلاش نہیں کر سکتی۔ ان کے جوابات حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ استخارہ کیا جائے۔ اس طریقے سے مسائل کا شاندار حل مل جاتا ہے اور انھیں زیر بحث لانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، کیونکہ ہماری عقل استعمال کرنے سے گھس کر کم ہو جاتی ہے۔ استخاراتی حل تلاش کرنے سے انشاء اللہ ثواب اور علم دونوں بیک وقت حاصل ہو جاتے ہیں۔
جناب وحید مراد مزید فرماتے ہیں ”اسی طرح تحریر میں یہ بھی بیان نہیں کیا گیا کہ جدید تعلیم اپنے موجودہ مقام تک کیسے پہنچی؟ یہ دراصل ایک طویل تاریخی و تہذیبی ارتقا تھا جس میں صنعتی انقلاب، سائنسی شعور اور معاشی تبدیلیوں نے کردار ادا کیا۔ ریاست نے تعلیم کو ایجاد نہیں کیا بلکہ اسے ایک منظم اور نگران ادارے کی شکل دی۔ جب یہ تاریخی فرق واضح نہ کیا جائے تو تجزیہ فکری طور پر نامکمل رہ جاتا ہے۔“ اپنی تحریر کی نارسائی کا اعتذار بار بار ہے کیونکہ مختصر اور یک موضوع تھی۔ میں یہ بھی بیان نہیں کر سکا کہ جدید تعلیم اپنے موجودہ مقام تک کیسے پہنچی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا مرْکباتِ تاریخ کا علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ بعض اوقات مجھے ایسا لگتا ہے کہ آقائے سرسید کے بعد تعلیم عامہ بھول کر ہانپتے ہانپتے ہمارے وطن پہنچ گئی ہے اور اب یہ عالم نزع میں ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ سکرات میں اسے کوئی سٹیرائڈ لگانے کی سبیل کرنا مناسب رہے گا یا نہیں۔ تعلیم عامہ جس طرح بانٹی جا رہی ہے پتہ نہیں پیچھے کچھ بچتا بھی ہے یا نہیں۔ میرے لیے جدید مسلم ذہن میں association of ideas کا عمل ہمیشہ نہایت حیرت انگیز رہا ہے۔ میری گزارش ہے کہ تعلیم عامہ کے تجزیے کو فکری طور پر مکمل کرنے کے لیے امیزون جنگلات کے اوپر آکسیجن کے تناسب کو زیر بحث لانا بھی ضروری ہے کیونکہ جدید میڈیکل سائنس کے مطابق اس کا انسان کے نظام تنفس سے براہ راست اور بہت گہرا تعلق ہے، اور نظام تنفس دماغ کو آکسیجن سپلائی کرتا ہے۔ تجزیہ چونکہ دماغ سے کیا جاتا ہے اس لیے جب تک امیزون سے حاصل شدہ منقی آکسیجن مالکیولوں کا تناسب پاکستانی فضا میں معلوم نہیں ہو گا، درست تجزیہ نہیں کیا جا سکتا۔ جناب وحید مراد نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ”ریاست نے تعلیم کو ایجاد نہیں کیا بلکہ اسے ایک منظم اور نگران ادارے کی شکل دی۔“ میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تعلیم تو ایجاد نہیں ہے لیکن تعلیم عامہ ایک ایجاد اور نئی ٹکنالوجی ہے کیونکہ اس کا mode of production تنظیمی ہے اور آرگنائزیشن ایک نئی ایجاد ہی ہے۔ جدید عہد میں آرگنائزیشن طاقت اور سرمائے کا واحد mode of production ہے، اور تعلیم عامہ کا واحد ذریعہ بھی آرگنائزیشنل ہی ہے۔
جناب وحید مراد کے بقول ”موجودہ نظامِ تعلیم کو “آلاتی، ریاستی یا سیکولر” کہہ کر مسترد تو کیا جا سکتا ہے مگر اس کے بعد پیدا ہونے والے فکری خلا کو پر کرنے کے لیے متبادل کی کوئی واضح صورت پیش کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ریاستی نظامِ تعلیم ناقص ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کی جگہ کون سا ڈھانچہ لایا جائے؟ کیا تعلیم کو ریاست کے دائرۂ اثر سے بالکل آزاد کر دینا ممکن یا مطلوب ہے؟ یا پھر ایسا راستہ اپنانا چاہیے جس میں ریاستی نظم کے ساتھ فکری خودمختاری و روحانی توازن بھی برقرار رہے اور علم اپنی روح میں آزاد مگر نظم میں اجتماعی رہے؟“ عرض ہے کہ کسی موقف کو قبول یا رد کرنے سے کوئی خلا پیدا نہیں ہوا کرتا اور اگر زیر بحث کوئی صورت حال ہے تو اس پر بنائے گئے کسی موقف کو رد یا قبول کرنے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس وقت پڑتا ہے جب آپ صورت حال کو کسی خاص رخ پر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور جو ایک سیاسی فیصلہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی گفتگو سیاسی فیصلے میں ایک input کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب ہست درست طور پر معلوم ہو جائے تو باید کی تیاری کرنا اور اس کے لیے درست اقدام اٹھانا آسان ہو جاتا ہے۔ میں جناب وحید مراد کو یقین دلاتا ہوں کہ فکری تجزیے یا علمی گفتگو سے کوئی خلا پیدا نہیں ہو گا۔ خلا و ملا سے آزاد ہو کر فوری مسئلہ ہست کو سمجھنے کا ہے۔ یہ صورت حال ہمارے ہاں گزشتہ دو صدیوں سے قائم ہے، اور ہمارے اہل علم نے اس کو سمجھنے کی بنیادی ذمہ داری بھی ادا نہیں کی۔ اس وقت قومی تعلیم عامہ کی حالت ایک آفت زدہ منطقے کی سی ہے اور اس کی تمام تر ذمہ داری ریاست یا اولی الامر پر نہیں ڈالی جا سکتی کیونکہ ہمارے اہلِ علم کے پاس ہست و باید پر کہنے کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تعلیم عامہ پر ہمارے اہل علم کے ارشادات پڑھ کر مستقبل سے مایوسی بڑھ جاتی ہے۔ ایک استاد کی حیثیت سے ہمیں اس صورت حال کو سمجھنے اور اس میں بہتری لانے کی ہر کوشش کا حصہ بننا چاہیے۔


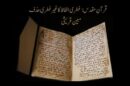















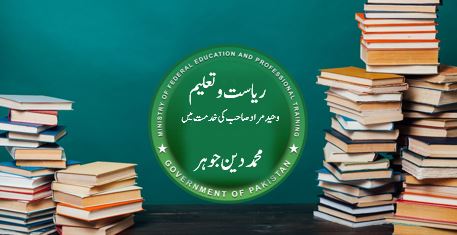



کمنت کیجے