کتاب محل لاہور نے ڈاکٹر اکرم رانا کے پوسٹ ڈاکٹریٹ آرٹیکلز کا اردو ترجمہ “استشراق اور شریعت” کے نام سے شائع کیا ہے۔اس کا پیش لفظ حافظ نعیم صاحب نے لکھا ہے۔ اس میں انھوں نے انتہائی اختصار سے استشراق کی تحریک کی تاریخ کا جائزہ لیا ہے۔جو لوگ اس موضوع پر علم رکھتے ہیں وہ تو تاریخ سے واقف ھیں لیکن میرے لیے یہ میدان ہی نیا ہے اس لیے حافظ صاحب کے پیش لفظ سے کچھ اہم باتیں جو میں نے نوٹ کی ہیں ان کو بیان کر رہا ہوں اور اس سلسلے میں وہ لوگ جو جاننا چاہتے ہیں ان کو کچھ واقفیت حاصل ہو جائے۔
اسلام اور عیسائیت کا تعارف میدان جنگ میں ہوا ہے،جس کی وجہ سے شروع ہی سے عیسائی مبلغین کا رویہ اسلام کے بارے میں منفی رہا،جس کے نتیجے میں دونوں مذاہب میں اختلافات کی خلیج وسیع ہو گئی،صلیبی جنگیں بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔عیسائی مبلغین،راہبوں اور قصہ گو پادریوں نے آپ ﷺ کی ذات پاک پر گھٹیا حملے کیے اور اس قدر دروغ گوئی سے کام لیا گیا کہ جھوٹ بھی شرمندہ ہو جائے۔ اس میں سب سے نمایاں کردار جان آف دمشق کا تھا جو کہ آٹھویں صدی عیسوی کا ایک شخص ہے۔اس نے کہا کہ اسلام میں آپ ﷺ کی پوجا کی جاتی ہے،نیز اس نے آپ ﷺ کی ازدواجی زندگی پر بھی مغلظات بکیں،یہی باتیں بعد کے مغربی سکالرز کی تحقیق کا موضوع بن گئی۔اسکے بعد صلیبی جنگوں کا زمانہ آیا جس میں عسکری میدان میں یورپ کو اسلام سے شکست کھانی پڑی۔اس وقت مسلمان نہ صرف عسکری بلکہ علمی، معاشرتی ،سماجی و ثقافتی لحاظ سے بھی یورپ پر برتری رکھتے تھے۔مساوات اور عدل و انصاف کے جو اصول مسلمانوں کے ہاں رائج تھے، یورپی معاشرہ اس سے محروم تھا۔
عسکری میدان میں شکست کے بعد مغرب نے سنجیدگی سے اسلام سے نبٹنے کا فیصلہ کیا جن میں مختلف تجاویز پر غور کیا گیا جیسے کہ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے اس کے فلسفے پر مکمل عبور رکھنا ۔قرآن پاک کا دقیق مطالعہ کرکے اس کی خامیوں کا تلاش کرنا اور پھر ان پر عیسائی فلسفے کی روشنی میں بہتر نظریہ پیش کرنا تاکہ لوگ اسلام سے بدظن ہو کر عیسائیت میں داخل ہوجائیں ۔لہذا فیصلہ کیا گیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ اب عسکری کی بجائے فکری میدان میں کیا جائے تاکہ اسلام پر تنقید کا راستہ کھولا جا سکے اس کے لیے اسلام کا مطالعہ بہت ضروری تھا اور دوسری طرف مسلم سلطنت میں کمزوریاں آنا شروع ہوگئیں تھیں جو کہ استشراقی تحریک کے فروغ میں مزید معاون ثابت ہوئیں۔اب اسلام ،آپ ﷺ کی ذات پاک،قرآن و حدیث اور مسلم تاریخ و تہذیب مستشرقین کی توجہ کا مرکز ٹھہری جس میں مصادر اسلامی کو مشکوک و لغو قرار دیا گیا۔آپ ﷺ کی نبوت کو بھی مشکوک بنایا گیا اور اس کو یہودیت و عیسائیت سے ماخوذ قرار دیا گیا،۔آپ ﷺ کے غزوات و سرایا کو بھی ہدف تنقید بنایا گیا اور کہا گیا کہ ان کے مقاصد معاشی تھے۔عہد وسطی کا یورپ ان ہی خیالات میں کھویا رہا، پھر سولھویں صدی سے لے کر اٹھارویں صدی تک عیسائی دنیا کے خیالات میں بتدریج آپ ﷺ کی بابت بہتری آئی اور پہلے کی نسبت انصاف پسندی سے کام لیا گیا اور آپ ﷺ کی تعریف و مدح میں بخل سے کام نہیں لیا گیا۔ نیز اس دوران ان کے کام میں معروضیت نظر آتی ہے مگر اس سے پہلے کے پھیلائی ہوئی منفیت و تعصب نے کئی صحت مند اذہان جو کہ غیر متعصب ہو کر لکھنا چاھتے تھے پر بھی اپنے اثرات قائم رکھے اور وہ لوگ بھی جب موقع ملتا اپنے تعصب کا اظہار ضرور کرتے۔
مستشرقین کی تاریخ صدیوں پر مشتمل ہے۔ جان آف دمشق سے لے کر ولیم میور تک اور آج تک ایک لمبی فہرست ہے جس میں لوگوں نے اپنی صلاحیتیں اسلام اور سیرت طیبہ ﷺ کے موضوع پر صرف کیں۔مسیحی دنیا اسلام اور آپ ﷺ کی مخالفت میں اس حد تک اندھی ہو گئی تھی کہ اس نے اسلام اور آپ ﷺ کی سیرت طیبہ کے بارئے میں بنیادی ماخذ جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔اس سلسے میں ہر رطب و یابس جس سے ان کا مقصد پورا ہوتا تھا انھوں نے قبول کیا۔ اس سلسلے میں مستند،غیر مستند،بنیادی و ثانوی،ناقص و غیر ناقص میں کوئی فرق نہیں برتا گیا۔ اگر حدیث یا آپ ﷺ کے بارئے میں علامہ الدمیریؒ کی کتاب “کتاب الحیوان” سے کوئی بات اپنے مطلب کی ملتی وہ قبول کی جاتی لیکن اگر اس کے برعکس بات امام مالکؒ کی موطاؑ میں ملتی تو اس کو رد کر دیا جاتا۔ماخذ کی اس کمزوری پر بھی متاخر مستشرقین نے توجہ دلائی اور ان کی تحقیق کی کمزوری کا اعتراف کیا ۔مستشرقین میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے خالص علم کی خاطر نیک نیتی سے اپنی زندگیاں تحقیق کے میدان میں صرف کیں۔ ان کی علمی خدمات کا اعتراف نہ کرنا ان کے ساتھ زیادتی ہو گی اور ان ہی مستشرقین کی وجہ سے مسلمانوں کے کئی علمی مصادر محفوظ ہیں اور اب بھی مسلمانوں نے جو کچھ بھی اس سلسلے میں کیا ہے، ان مستشرقین کا مقابلہ مقدار اور معیار کے مجموعی میدان میں نہیں کرسکتے۔اور انھیں تصنیفات کی اشاعت سے اسلام کی مخالفت میں کمی آئی۔پیر کرم شاہ نے ضیاء النبی میں ان مصادر کی فہرست بھی دی ہے جو کہ مستشرقین کے ہاتھوں تحقیق وترتیب کے بعد شائع ہوئے۔مولانا شبلی نعمانی نے بھی مستشرقین کی خدمات کا اعتراف کیا ہے۔پیر کرم شاہ نے تو مستشرقین کے میلانات و رجحانات کے حوالے سے ان کو یوں تقسیم کیا ہے۔
1 خالص علم کے شیدائی
2۔متعصب یہودی اور عیسائی مستشرقین
3. ملحد مستشرقین
4. علم کو پیشہ بنانے والے
5.انصاف پسند مستشرقین اور
6. وہ لوگ جو مستشرقین تھے لیکن حق کا نور دیکھ کر اس کے حلقے میں آ گئے۔
یہ حافظ نعیم صاحب کے پیش لفظ کا خلاصہ ہے۔ اس سے استشراق کی تاریخ اور ان کے اسلام اور آپ ﷺ کی بابت رویہ اور اس میں آنے والی تبدیلی اور پھر ان کی اسلامی مصادر کے بارے میں تحقیقات کا پتہ چلتا ہے۔ امید ہے جیسے جیسے مغرب اسلام کے بنیادی عقائد، قرآن مجید اور آپ ﷺ کے لیے حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرتا جائے گا ان پر آپ ﷺ کی عظمت اور اسلام کی حقانیت واضح ہوتی جائے گی اور ایک بہترین علمی مواد بھی ان سے میسر ہوگا۔مسلم دنیا کے اہل علم کو بھی اس بارے میں خصوصی توجہ کی ضرورت ہے تاکہ اگر کوئی بھی اعتراض چاہے وہ علمی ہو یا بد نیتی پر مبنی ہو اس کا تحقیقی اور تفصیلی جواب دیا جا سکے۔
ڈاکٹر اکرام رانا صاحب کا پہلا مقالہ “استشراقیت:نوعیت اور ارتقاء” کے نام سے ہے۔استشراقیت کی اصطلاح کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مبہم اور غیر واضح ہے،فلسطینی نژاد امریکی محقق ایڈورڈ سعید نے ایک کتاب لکھی جو کہ بے شمار مصنفین کی توجہ کا مرکز بنی۔ایسے ہی برنارڈ لئیوس اس کے ناقابل فراموش ناقدین میں سے ہے۔آگے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ استشراقیت کی اصطلاح تین مختلف مفاہیم میں استعمال ہوتی ہے۔ اول تعلیمی مفہوم بمعنی مطالعہ مشرقیت ،دوسرا مشرقیت اور مغربیت میں امتیاز پر مبنی انداز فکر اور تیسرا مشرقیت کی تشریح میں سماجی رویہ۔ڈاکٹر اکرام رانا نے اس کے علمی پہلو پر بات کی ہے ۔اس حوالے سے وہ بتاتے ہیں کہ 1973 میں پیرس میں مستشرقین کی ایک کانگریس کے دوران مستشرقین کی اصطلاح کو ختم کرنے کی بات کی گئی مگر یہ علمی اور عملی طور پر اب بھی موجود ہیں۔ مغربی مستشرقین نے عربی اور اسلامی تعلیمات کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور اس میں کئی گراں قدر تصانیف بھی منظر عام پر آئیں۔کئی نسلوں نے اس پر غیر معمولی محنت کی ہے اور اس کے نتائج بھی ان کو ملے ہیں۔مسلسل کام کی وجہ سے استشراقیت ایک نظام علم بن گیا۔
ایڈورڈ سعید کے مطابق استشراقیت کا آغاز 18ویں صدی سے شروع ہوا جبکہ ڈاکٹر اکرام رانا صاحب کہتے ہیں کہ استشراقیت کا آغاز ساتویں صدی عیسوی میں ہو گیا تھا۔ جب اسلام عرب سے نکل کر باقی دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا تھا، تب عیسائیت نے اسے اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے اس کا تدارک کرنے کی کوشش کی۔امریکی فلسفی نارمن ڈئنیل کہتے ہیں کہ عیسائی اسلام کی کچھ باتیں مانتے تھے لیکن فقط اتنی جتنی وہ ماننا چاہتے تھے۔ ویسے مجموعی طور پر اسلام سے اپنی ناپسندیدگی وہ چھپا نہیں پائے، اس لیے جب بھی عیسائیوں نے اسلام کو پیش کیا، حلیہ بگاڑ کر پیش کیا۔از منہ وسطیٰ میں عیسائی اسلام سے اس درجہ لاعلم تھے کہ انھوں نے کہا کہ آپ ﷺ مسلمانوں کے معبود ہیں اور یہ نظریہ 1700ء تک مبہم انداز میں موجود رہا۔ جان آف دمشق جو کہ بنو امیہ کی حکومت میں سرکاری ملازم تھا اس نے اسلام کا مطالعہ کیا،پھر اس نے ملازمت ترک کی اور فلسطین کے ایک گرجے میں بیٹھ کر اسلام مخالف کتابیں لکھنے لگا۔ اس کی وفات 749 عیسوی کی ہے اور اسی کی کوششوں سے استشراق کی تحریک نے جنم لیا۔
فرانسیسی مورخ میکسم روڈنسن اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ 14 ویں صدی عیسوی تک لاطینی مصنفین نے آپ ﷺ کی حیات طیبہ پر درست تفصیلات کو نظر انداز کیا۔اس سلسلے میں پیٹر جو کہ اسی زمانے کا شخص تھا اس نے اسلام کے بارئے میں ٹھوس شواہد اکٹھے کرکے ان کی اشاعت کی۔ پھر 1143 عیسوی میں رابرٹ کیتانی نے قرآن پاک کا لاطینی زبان میں مکمل ترجمہ کیا اور اس کے پیچھے غرض یہ تھی کہ قرآن کریم کی خامیوں کو تلاش کرکے عوام کے سامنے لایا جائے تاکہ لوگ اسلام سے تائب ہو کر عیسائیت کی طرف آئیں مگر یہ ان کے مقاصد کے حصول میں ناکام رہا۔بارہویں صدی عیسوی میں ایک محقق ولیم نے قدرے غیر جانبداری سے کام کیا اور اس نے کہا کہ مسلمان آپ ﷺ کو معبود نہیں بلکہ نبی مانتے ہیں۔اس یہ پتہ چلتا ہے کہ اس عرصہ میں یورپ میں اسلام کے حوالے سے منطقی نظریات بھی سامنے آ رہے تھے۔آپ ﷺ اور قرآن پاک کے بعد ان لوگوں نے مسلمان اہل فلسفہ جیسے کہ ابن رشد،امام غزالی،بو علی سینا اور الفارابی کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا۔اس وقت ان لوگوں کے مطابق اسلام بہت محدود اور آہستگی سے پھیل رہا تھا تو اس پر کئی عیسائی علماء اسلام کے مکمل فنا ہونے کا انتظار کرنے لگے۔
پھر کچھ عرصے بعد 1312ء ویانا میں عیسائی علماء کا ایک اجلاس ہوا اور اس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے جن میں عربی زبان سیکھنے کی منظوری تھی تاکہ مسلمانوں سے براہ راست بات چیت کی جا سکے اور ان تک کیتھولک عقیدے کو پہنچایا جا سکے اور اسلامی عقاید کی تردید کی جا سکے۔پھر پندرہویں صدی میں Segovia کے جان نے قرآن پاک کا نیا ترجمہ کیا اس نے پہلے ترجمے میں کئی خامیاں دیکھیں جس کو اس میں دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب ان کا ایک مقصد اور بھی تھا کہ یہ ثابت کیا جائے کے قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ۔پھر جب 1586 میں چھاپہ خانہ کی ایجاد ہوئی تو ان لوگوں کی تحقیقات عربی زبان میں چھپیں اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی کتابیں جو سائنس کے موضوعات پر تھیں مغرب کے پاس پہنچ گئیں۔روڈنسن کے مطابق یہ مواد ایک تبدیلی لایا۔ اسلام کو اب مسحیت مخالف نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یوں اسلام کے بارے میں معروضی طرز فکر کو فروغ ملا۔اب کئی لوگوں نے تسلیم کرنا شروع کردیا کہ آپ ﷺ ایک نبی تھے اور مسلمانوں کی رواداری کی بھی تعریف کی گئی۔
G.Sale نے قرآن کا انگریزی ترجمہ کیا جو کہ روایتی استشراقیت کی بنیاد سمجھا جاتا ھے ۔اٹھارویں صدی میں سلویسٹر ڈیساسی Silvester Desacy جو کہ فرانسیسی تھے کا نام قابل ذکر ہے۔ اس کو یورپ میں “جدید اسلامی تعلیمات” کا بانی کہا جاتا ہے۔ یہ زیرک،نکتہ سنج اور ماہر زبان تھا۔ یہ نتائج کے حوالے سے بہت محتاط رہتا تھا اور ایسی کوئی چیز پیش نہیں کرتا تھا جو متن میں واضح طور پر موجود نہ ہو۔اسلام پر اب تک ہونے والا کام بے ربط اور غیرمنضبط تھا، اس کام کو منظم و مرتب سلویسٹر ڈیساسی نے کیا۔ استشراقیت کی تاریخ میں Renan بھی ایک قابل ذکر شخصیت ہے۔ اس نے کہا کہ اسلام جدید دور سے ہم آہنگ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر یہ نظریہ سید جمال الدین افغانی کے رد کے بعد قبولیت عامہ حاصل نہ کر سکا۔ایک اور اہم نام ولیم میور کا ہے جس نے آپ ﷺ کی حیات طیبہ پر کتاب لکھی جس کو کئی سال تک یورپ میں معیار تسلیم کیا گیا۔ اس میں ولیم میور نے کہا کہ اسلام نے اپنی تعلیمات عیسائیت و یہودیت سے مستعار لی ہیں اور ان کو نئی شکل میں ڈھالا ہے۔ نیز اس نے آپ ﷺ کے نسب اور دیگر معاملات پر سولات اٹھائے جن کا جواب سرسیداحمد خان نے خطبات احمدیہ میں دیا۔ ایسے ہی کارلائل نے آپ ﷺ کو نبی تسلیم کیا مگر نبی کی ایک اپنی تعریف وضع کی ۔
مغرب میں یہودی گولڈ زیہر کو اسلامی قانون پر اتھارٹی سمجھا جاتا ہے۔ گولڈ زیہر سلویسٹر دیساسی کا ہم سبق تھا۔ اس کے اسلامی قانون پر نظریات کو Joseph Schacht نے پھیلایا۔ پھر ان تحریروں کو سکاٹ لینڈ کے جان برٹن نے اپنی کتاب The Collection of Quran میں آگے بڑھایا۔ اس نے احادیث اور ناسخ اور منسوخ کے فلسفے کے مطالعے کے بعد یہ دعوی کیا کہ معاذاللہ قرآن ایک نامکمل کتاب ہے کیونکہ اس میں چند آیات شامل نہیں ہیں۔نیز اس نے احادیث کی استناد کو بھی مشکوک قرار دیا۔ ایک اور مستشرق Guillaume نے بھی اس نظریے کا پرچار کیا اور کہا کہ احادیث کا زیادہ تر متن یہودیت و عیسائیت سے مستعار لیا گیا ہے۔ احادیث کے بارے میں یہی نظریات عیسائی مبلغ D.B Macdonald اور Gibb کے ہیں۔ گب نے قرآن کو آپ ﷺ کی گفتگو قرار دیا ۔امریکہ میں بھی گب اور میکڈونلڈ کے خیالات کو پزیرائی ملی۔امریکی مستشرقین میں برنارڈ لئیوس کا نام قابل ذکر ہے۔ اس نے بھی یورپی تعصب کو بیان کیا کہ اسلام عیسائیت و یہودیت سے متاثر ہے ۔ڈاکٹر صاحب پھر آخر میں اس بحث پر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ مغربی علما نے پہلے آپ ﷺ اور قرآن کو موضوع مطالعہ بنایا،پھر مسلم فلسفیوں کے افکار کا مطالعہ کیا، پھر زبانوں پر توجہ مرکوز کی،پھر19 ویں صدی کے نصف تک مغرب نے اسلامی قانون اور اصولوں کو نہیں پڑھا تھا جس پر انھوں نے بعد میں زور دیا۔
یہ ڈاکٹر اکرام رانا صاحب کے پہلے مقالے میں میری نظر میں آئے، اہم نکات ہیں جن کو میں نے یکجا کردیا ہے۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے وقت کے ساتھ ساتھ مستشرقین کا رویہ بدلتا گیا اور اسلام کے بارے میں کئی غلط فہمیوں کی تردید خود انھیں کی صف میں موجود لوگوں نے کیں اور اپنے پیشروؤں کے تعصب اور غلطی کا اعتراف کیا۔
دوسرے مقالے میں مستشرقین کی تعریف میں ایڈورڈ سعید کا سہارا لیا ہے جس کے مطابق ہر وہ شخص جو مشرق کے بارے میں پڑھتا اور لکھتا ہے، چاہے اس کا تعلق عمرانیات سے ہو یا بشریات سے۔اس تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ استشراق کا ہدف صرف اسلام نہیں بلکہ پورا مشرق اور مشرقی علوم ہیں۔مگر اس کتاب میں خصوصیت سے شریعت کے بارے میں استشراق کے رویے اور تحقیق کی ہے۔ لہذا ہم بھی اس تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے۔مستشرقین میں گولڈ زیہر کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اسے مغرب میں اسلامی علوم کا بانی کہا جاتا ہے۔ فقہ اور شریعت میں فرق بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ
” شریعت کا دائرہ کار کا تعین اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے کیا۔ فقہ کی عمارت سعی انسانی پر استوار ہوتی ہے۔ گویا اس کا زیادہ تر انحصار قرآن وسنت کی تشریح پر ہے۔” (ص-44)
گولڈ زیہر جو کہ ہنگری کا یہودی تھا وہ اسلام کو خالص مذہب نہیں سمجھتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ اسلام یہودیت سے مستعار ہے۔ پھر یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ مدینہ منورہ کی ریاست میں آپ ﷺ نے وراثت اورجائیداد کے قانون کا نفاذ کیا جن کی روشنی میں اسلامی فقہ کی قانون سازی ممکن ہوئی۔بعد میں بنوامیہ کے دور میں پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے عدالتی فیصلوں میں عقل و دانش کا سہارا لیا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہودیت کی طرح اسلام میں بھی قرآن کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو کہ شرعی طور پر تقدس کی حامل ھے یعنی کہ سنت۔پھر احادیت کے بارے میں گولڈ زیہر کا خیال ہے کہ اس میں بڑے پیمانے پر ردوبدل ہوا اور ہر مسلک نے اپنی تائید میں احادیث گھڑی جس کو محدثین نے بھی محسوس کیا جس کے لیے انھوں نے بہت عرق ریزی سے مستند احادیث کو مشکوک سے علیحدہ کیا۔گولڈ زہیر خود بھی احادیث کا وسیع مطالعہ کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چھ مجموعوں میں سے صرف دو مستند ہیں۔یعنی کہ وہ کچھ احادیث کی استناد کو تسلیم کرتا ہے۔اسلامی فقہ کو رومی قانون سے متاثر قرار دیتا ہے۔ اس بات کا جواب ڈاکٹر حمیداللہ اور ڈاکٹر محمود غازی نے اپنے خطبات میں دیا ہے اور اس بات کو غلط ثابت کیا ہے کہ اسلامہ فقہ رومن لاء سے متاثر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالفرض فقہ رومن لاء سے مطابقت رکھتی ھے تو بھی کوئی برائی نہیں۔ بطور قانون کسی بھی چیز سے استفادہ کیا جا سکتا ہے جو آپ کے اپنے اصولوں کے خلاف نہ ہو۔اجماع کے بارے میں گولڈ زیہر کہتا ہے کہ یہ پہلے معاشرے کا اجماع تھا بعد میں اسے فقط علماء کے کے اتفاق تک محدود کرلیا گیا۔
ایک اور اہم مستشرق جس کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے میکڈونلڈ جو کہ گولڈ زیہر کا ہم عصر تھا۔ اس نے بھی اسلامی فقہ اور اس کی نشوو نما پر بحث کی ہے۔ اس کے نزدیک اسلامی فقہ کا دائرہ بہت وسیع ہے۔وہ اعتراف کرتا ہے کہ آپ ﷺ انصاف پر مبنی فیصلے کرتے تھے اور آپ ﷺ کی ہدایت کا منبع وحی الہی تھی اور جہاں رواجی قانون موزوں ہوتا آپ ﷺ اس کے مطابق فیصلہ فرماتے ۔میکڈونلڈ بنو امیہ کو الزام دیتا ہے کہ انھوں نے سیاسی مقاصد کے لیے احادیث گھڑیں۔ وہ تمام کی تمام احادیث کو وضعی کہتا ہے ۔ ایسے ہی قیاس (رائے) کی دلیل حدیث معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی وہ گھڑی ہوئی کہتا ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ رومی قانون قدرت ہے جس کو اسلام نے استحسان اور استصلاح کی اصطلاح سے یاد کیا جاتا ہے۔قرآن کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ یہ آپ ﷺ کے روحانی حالات کا مجموعہ ہے۔
تیسرا اہم مستشرق گب (Gibb) ہے جس کا ڈاکٹر اکرام رانا صاحب نے ذکر کیا ہے۔یہ اسکندریہ میں پیدا ہوا، تعلیم ایڈنبرا میں حاصل کی۔اس کے بعد پہلے آکسفورڈ اور پھر ہاورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا۔یہ اسلامی تہذیب اور قانون کا مداح تھا۔ساتھ یہ بھی خیال کرتا تھا کہ اسلامی قانون رومن قانون سے مستعار لیا گیا ہے مگر یہ رومی قانون سے زیادہ جاندار ہے ۔قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ آپ ﷺ کے بیس سال میں دئیے گئے خطبات کا مجموعہ ہے۔ سنت کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ یہ گھڑی ہوئی ہے،ظاہر بات ہے ان باتوں سے اس کی کسی صورت اتفاق نہیں کیا جا سکتا ۔اجماع علماء کو بھی وہ مسلمہ حیثیت نہیں دیتا جبکہ عوامی خواہشات کو اہمیت دیتا ہے۔وہ اجماع کو اجتہاد کا حصہ سمجھتا ہے۔ وہ اس کا مطلب سوچ کی آزادی نہیں لیتا۔ اس کے نزدیک اس کا معنی مخصوص صورتحال میں قرآن و سنت کی نص کی صحیح معنویت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ اس سادہ اور بین سچائی سے انحراف نہ ہو۔
چوتھا مستشرق شاخت (J.Schacht) ہے جس کا مقالہ گولڈ زیہر کی طرح مغرب کے لیے گائیڈ لائن ثابت ہوا،اس کے ساتھ امریکہ میں بھی اس یہ گائیڈ لائن ثابت ہوا۔شاخت اسلامی قانون کو اسلامی سوچ کا خلاصہ کہتا ہے۔ اسے اسلامی عملی زندگی کی ایک واضح مثال کہنے کے باوجود کہتا ہے کہ اسلامی قانون کا ماخذ قرآن نہیں بلکہ بنو امیہ میں ہونےوالے انتظامی اور مقبول فیصلوں کے ذریعہ عمل پزیر ہوا۔آپ ﷺ کے قانونی اختیار کا بھی قائل نہیں تھا۔ کہتا تھا کہ آپ ﷺ کو صرف مذہبی اور سیاسی اختیارات حاصل تھے،یہ بات اس کی سراسر خلاف حقیقت ہے۔ خیال ہوتا ہے کہ یہ صیحح طرح اسلام کے تصور رسالت سے واقف نہیں تھا ورنہ ایسی بے بنیاد اور لغو بات نہ کہتا۔قیاس،استصلاح اور استصحاب کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی بنیادیں رومن یونانی نوعیت کی ہیں۔اجماع کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اگر معاشرے کا ہو تو یہ بیرونی اثر سے آزاد ہوتا ہے، لیکن اگر یہ علماء کے مابین ہو تو اس پر بیرونی اثر نظر آتا ہے۔ احادیث کے بارے میں بھی اس کی رائے باقی مستشرقین سے ملتی ہے کہ ان کو مستند ماننا مشکل نظر آتا ہے۔شاخت کے اس نظریے کو بعد میں پاورز (Powers) اور کولسن (Coulson) نے مسترد کر دیا کہ قرآن اور اسلامی قانون کی ساخت میں عدم تسلسل ملتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ گب اور میکڈونلڈ سنت کے تواتر کو تو مانتے ہیں مگر اس میں وضع اور تضاد کے سختی سے قائل ہیں۔ انھوں نے خود اس موضوع پر کام نہیں کیا بلکہ اپنے ہمعصر لوگوں کے خیالات اپنا لیے اور میکڈونلد نے تو واضح طور پر گولڈ زیہر کے خیالات اپنا لیے کہ بنو امیہ نے حدیث میں جعلسازی کی۔ان چاروں مستشرقین کا خیال تھا کہ اسلامی قانون پر رومن لاء کے اثرات ہیں اور یہ ان سے مستعار لیا گیا ہے جبکہ ایک اور مستشرق فٹزجیرالڈ (Fitzgerald) نے ان کی تردید کی اور کہا کہ مغرب کے رومن لاء کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اسلامی قانون کی تشکیل میں کوئی اثر ڈالے۔محسوس ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ جیسے جیسے علم اور تحقیق میں اضافہ ہوتا رہا، مستشرقین کے تعصب کا جذبہ بھی مانند پڑتا گیا اور ان میں حقیقت پسندی کا رجحان بڑھتا رہا۔
امریکہ میں اصول فقہ کا تعارف دو ذرائع سے ہوا۔ ایک مشرق قریب کے لوگوں سے جیسے کہ فلپ کے ہیٹی،فرحت جے زیدہ اور جارج مکدیسی دوسری یورپی مستشرقین جیسے کہ گولڈ زیہر،میکڈونلڈ،گب اور شاخت وغیرہ۔ فلپ کے ہٹی پرنسٹن یونیورسٹی میں سامی ادبیات کا تاحیات پروفیسر رہا۔ مغرب میں اس کی شہرت ماہر اسلامیات کی رہی ہے۔ یہ اسلام کی بابت اس حد تک متعصب اور جانبدار یا پھر لاعلم تھا کہ قرآن پاک اس کے مطابق عیسائیت،یہودیت اور بت پرست عرب کلچر سے تشکیل پایا (العیاذ باللہ)۔سنت اور اجماع کو اسلامی قانون کا دوسرا اور تیسرا ماخذ گوکہ یہ تسلیم کرتا ہے مگر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ اختراعی ہیں تاکہ عبادات کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ وہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ بعض احادیث کی تعلیمات اور معجزات جو آپ ﷺ سے منسوب ہیں بالکل وہی ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کیے جاتے ہیں۔فرحت جے زیدہ پرنسٹن یونیورسٹی میں ہٹی کے ماتحت عربی معلم تھا،وہ ماہر قانون اور ماہر گرائمر بھی تھا۔ اس نے اسلامی قانون کا مطالعہ کیا اور اس پر لکھا۔اس نے مثالوں سے ثابت کیا کہ “عرف” فقہ کے ابتدائی فیصلوں پر اثرانداز ہوا۔ شریعت اسلامیہ کے دیگر نظام پر غالب آنے کے بارے میں وہ تحفظات رکھتا تھا۔
جارج مقدسی بھی ایک اہم شخصیت ہے جس نے مسلم قانونی نظام کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ اس نے پینسلوانیا یونیورسٹی میں پڑھایا۔ اس کے مطابق مسلم ہیومنزم اور علم کلام کے اوپر یونانی فلسفے کا اثر ہے۔اصول فقہ کی اصطلاح کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کے ہر دور میں وہ معنی نہیں تھے جو بعد میں اس سے منسوب ہوئے۔دسویں صدی میں اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ اس کا معنی و مفہوم اس طرح کیا گیا کہ نہ صرف مادی مسائل کے علم کی وضاحت کرے بلکہ سنجیدہ اور اہم قانونی معاملات کی شرح بھی اس کے مفہوم میں شامل کرلی گئی۔مغربی علماء میں ہرگرونجے کی اہمیت گولڈ زہیر سے کم نہیں۔ ہرگرونجے کو ہالینڈ میں اسلام کے قانونی مطالعہ کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ انڈونیشیا میں سامراجی آبادکار کے طور پر گزرا۔اس کے نزدیک قرآن محض خدا کا کلام ہے البتہ سنت اس کی نزدیک الہامی نہیں، یہ بعد میں پروان چڑھی۔اجماع کو یہ قانونی ڈھانچے کے لیے اہم کہتا ہے۔یہ کہتا ہے کہ اجتہاد کا سلسلہ عملی طور پر بند نہیں ہوا کیونکہ کئی علماء نے اندھی تقلید کی مخالفت کی۔
ایک اور مستشرق اینڈرسن کے مطابق اسلامی قانون الہامی اور غیر متبدل سمجھا جاتا ہے۔ تاہم وہ یہ بھی دعوی کرتا ھے کہ اسلامی قانون اپنی روح کے لحاظ سے سخت بے لچک ہے۔اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کولسن کا ذکر کیا ھے جس نے شکاگو یونیورسٹی میں فکر اسلامی پر خطبات دیے۔ اس نے کہا کہ اسلامی قانون معاشرے سے دور اور تخیلات پر مبنی ہے۔اسے مغربی قانون اور اسلامی قانون کے فرق کا پتہ تھا۔ مغربی قانون معاشرے کے تابع ہے جبکہ اسلامی قانون کا مقصد معاشرے کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔امریکہ میں اسلامی قانون سے دلچسپی 1948 میں پیدا ہوئی اس کی ضرورت معاشی تعلقات کی وجہ سے پیش آئی۔
ایک اہم شخصیت چالس کٹلر ٹوری کی ہے۔ اس نے تھیوڈور نولڈیکے سے تعلیم و تربیت حاصل کی۔یہ کہتا ہے کہ اسلامی قانون یہودی کتب سے اخذ کیا گیا ہے مگر یہ اپنے اس دعوی کی مثالیں دینے سے قاصر رہا۔ بعد میں یہ عرب جاہلیت سے مثالیں تلاش کرنے لگا مگر یہ اسلامی قانون پر مسیحی اثرات کا انکار کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ آپ ﷺ عیسائیوں کے بارے میں بہت کم جانتے تھے اور ایسا ہی معاملہ عیسائی کتب کے بارے میں تھا۔
اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ڈیوڈ ایس پاورز کو امریکی دانشوروں میں نمایاں حیثیت کا حامل بتایا ہے جس کو قرآن اور حدیث میں دلچسپی تھی۔اس نے کہا کہ مسلم معاشرے کے پاس بہت سی قرآنی آیات اور احادیث اصل حالت میں نہیں اور ایسے ہی بہت سی آیات و احادیث کے صیحح مفہوم سے نا آشنا ہے۔اس نے کہا کہ کچھ لوگوں نے قابل اعتراض آیات کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش میں قرآن کے متن میں تبدیلیاں کردیں (العیاذباللہ)۔یہ یقیناً اسلام کے قانون ناسخ و منسوخ سے ناواقف تھا ورنہ ایسی بے بنیاد اور بے تکی رائے ہرگز قائم نہ کرتا۔۔ڈیوڈ فورٹ نے شاخت کی حمایت جبکہ کولسن کے نظریہ کی مخالفت کی اس نے کہا کہ زمانہ قبل اسلام کا عربی قانون وہ لوح ہے جس پر قرآن نے زیادہ ترقی یافتہ اخلاقی اور قانونی اصول تحریر کیے۔
آگے ڈاکٹر صاحب نے ایک اور شخصیت ڈینی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ مستشرقین کے ناقص فہم سے واقف تھا اس لیے اس نے اعتراف کیا کہ قرآن معتبر اور آپ ﷺ کے منہ سے ادا شدہ ہے۔ قرآن تاریخی ریکارڈ یا خود نوشت نہیں ہے۔اس کا یہ اعتراف حق لائق تحسین ہے لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ڈینی کی علوم اسلامیہ پر کتب انڈر گریجوٹ طلباء کے لیے لکھی گئی تھیں۔اسلامی فقہ پر وائس کا کام بھی مغربی زبان میں ہونے والا سب سے جامع کام ہے۔ وہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کو اسلام کی نظریاتی فقہ کی سب سے بڑی ہستی تسلیم کرتا ہے۔اس کے خیال میں شریعت کے ذریعہ ہی انسان کو دانش حاصل ہوتی ہے۔ حنفی فقہاء کی فہرست میں امام الشاشیؒ،امام الکرخیؒ، امام ابوبکر الجصاصؒ اور امام بزدویؒ کو بیان کرتا ہے اور امام بزدویؒ کے کام کو آنے والی نسلوں کے لیے معیار قرار دیتا ہے۔ اس سے ڈاکٹر اکرم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس نے امام جصاص کا مطالعہ نہیں کیا، اس میں وائس کا اپنا قصور نہیں بلکہ اس نے فقہ کی نظری روایت کا مطالعہ علامہ آمدی کو مد نظر رکھ کر کیا۔وائس نے امام غزالیؒ کے نظریہ تواتر پر بھی گفتگو کی ہے۔ آخر میں اعتراف کرتا ھے اسلامی وحی کی بنیاد ناقابل تسخیر ہے۔ایک اور مصنفہ جینٹ ویکن نے امام ابن قدامہ حنبلیؒ کی کتاب کے ترجمے پر کام کیا ہے اور بتاتی ہے کہ کس طرح کوئی خدائی حکم فرض،واجب،مستحب یا مندوب کا درجہ حاصل کرتا ہے۔
اس مقالے کے آخر میں خلاصہ بحث میں ڈاکٹر صاحب یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ مغربی علماء اس نظریے کے حامی ہیں کہ اسلامی قانون خارجی عناصر سے متاثر ہے۔ وہ قرآن کو الہامی تسلیم کرنے کو تیار ہیں مگرحدیث کو نہیں ،اجماع سے مراد وہ معاشرے کا اجماع مراد لیتے ہیں نہ کہ علماء اسلام کا۔ ان دونوں مستشرقین کا شمار ان چند سکالرز میں ہوتا ہے جنہوں نے فقہ اسلامی پر کام کیا ہے۔فقہ اسلامی سے مستشرقین کی دلچسپی کی وجہ اس ضابطہ حیات ہونا ہے جو کہ پیدائش سے مرنے تک راہنمائی کرتی ہے۔جیمز کولسن لندن یونیورسٹی میں مشرقی قوانین کا پروفیسر تھا،وہ شہری قانون میں مہارت رکھتا تھا،اس کی کتابیں اور مقالات تقابلی مطالعے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔اس کی تحریروں میں مذہبی تعصب اور اسلام دشمنی دیگر مستشرقین کے مقابلے میں کم نظر آتی ھے۔وہ اسلامی قانون کا مطالعہ ایک زندہ قانونی نظام کے طور پر کرتا ھے،اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آپ ﷺ کے وصال کے بعد جب وحی کا سلسلہ رک گیا تو اسلامی شریعت جس اعلیٰ معیار تک پہنچ گئی تھی وہ قائم رہی اس میں تغیر و تبدل کی گنجائش نہ تھی۔اسلامی قانون سازی کے دائرے میں قرآن کریم کے کردار کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ اسلامی اخلاق کے اصولوں کی تعبیر و ترجمانی کے سوا کچھ نہیں،وہاں وہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ اسلامی قانون ان قواعد کا مجموعہ ہےجو اللہ کی طرف سے وحی کردہ ہیں،ڈاکٹر اکرم صاحب کے نزدیک قرآن کریم کے قانون سازی میں کردار کے بارے اس کے نتائج تضاد کا شکار تھے۔
احادیث کے میدان میں کولسن کا موقف کافی دلچسپ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ ﷺ کو مدینہ میں حکومت کے دوران بہت سے قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑا خصوصاً ایسے مسائل جن کو قرآنی احکام کی روح چھیڑتی ہے، یعنی کے وحی کے امین اور قرآن کے عام اور مجمل نصوص کی تفسیر کرنے والے کی حیثیت سے۔پھر کہتا ہے کہ دوسری صدی ہجری میں سنت سے مراد فقہی آراء کے وہ مجموعے مراد ہوتے تھے جن پر کسی خاصی فقہی مکتب کے علماء کا اتفاق ہوتا تھا۔وہ احادیث کے وضعی ہونے کا قائل تھا کہ محدثین نے اپنے مسلک کی تائید میں انھیں گھڑا،لیکن اس کو اپنے دعوی کی کمزوری کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ تسلیم کرتا ہے کہ احکام کے متعلق احادیث کا ایک حصہ تو ان افعال و کلمات کی اصل کے عین مطابق ہے جو آپ ﷺ سے صادر ہوئے،مگر اس محفوظ حصہ کو گھڑے ہوئے اقوال کے مرکب نے ڈھانک دیا تھا۔ڈاکٹر اکرم رانا صاحب کہتے ہیں کہ کولسن کے نظریات اکابر مستشرقین سے انوکھے تو نہیں مگر قرآن و حدیث کے کئی پہلووں پر وہ نئی توجیہات کا اظہار ضرور کرتا ہے۔
پروفیسر اینڈرسن قانون شہادت پر بین الاقوامی شہرت کا حامل سکالر تھا،اسلامی قانون پر مغرب میں اسے اتھارٹی تسلیم کیا جاتا ہے۔وہ کہتا ہے کہ اسلامی قانون کی فطرت کو سمجھنا بہت ضروری ہےجو کہ مغربی قانون سے مختلف ہے۔مغربی قانون کی بنیاد مذہب پر نہیں جبکہ اسلامی قانون کی بنیاد مذہب پر ہے۔اینڈرسن کے نزدیک یورپی قانون رومن لاء سے اخذ ہوا ہے جس کو وقت کے ساتھ ڈھالا جا سکتا ہے،جبکہ مسلمانوں کے سامنے فیصلہ کرنے سے پہلے برائی اور اچھائی رکھ دی گئی ہے جس سے وہ اپنے پسند سے محروم کردیے گئے ہیں۔پھر ان دونوں قوانین میں دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ مغربی قانون چیزوں کو عارضی طور پر پرکھنے کے لیے ہے،یہ مسائل کا عارضی حل نکالتا ہے ،جب کہ اسلامی قانون میں چاہے وہ عبادات ہوں یا معاملات ان میں انسانی زندگی کا ہر پہلو موجود ہے،اس کے نزدیک اسلامی قانون،قانون کم اور فرائض کا مجموعہ زیادہ ہے۔ تیسرا بڑا فرق مغربی قانون آہستہ آہستہ وجود میں آیا اس قانون نے رسم و رواج سے جنم لیا جبکہ اسلامی قانون خدا کی طرف سے نافذ کیا گیا، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔
اینڈرسن کے بیان کردہ فرق بہت واضح ہے مگر حیرت ہے مغرب کے ان لوگوں پر جو اتنے بنیادی فرق کے باوجود فقہ اسلامی کو رومن لاء سے ماخوذ مانتے ہیں۔ اینڈرسن اسلامی قانون کو جدید دور کے تناظر میں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مسلمانوں کی بیویوں کے پاس شادی ختم کرنے کا کوئی قانونی طریقہ نہیں ہے، یہ حق صرف مرد کے پاس ہے۔جب شوہر کو کوئی بیماری یا پاگل پن وغیرہ ہو تو بیوی آزاد ہو سکتی ہے ورنہ نہیں۔1915 میں مالکی فقہاء سے استفادہ کرتے ہوئے قانون سازی کی گئی اور بیویوں کو طلاق کا حق دیا گیا جبکہ حنفی فقہاء اس کے مخالف ہیں۔
ڈاکٹر اکرم اسلامی قانون کی بابت بہت ایک عمدہ بات کرتے ہیں کہ اس کے مزاج میں بیک وقت دو متضاد خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف یہ غیر متغیر اور ثابت شدہ قانون ہے، زمان و مکان یا انسانی معاشرے کی کوئی تبدیلی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی لیکن زندگی کے بدلتے حالات کی تنظیم کے لیے یہ اپنے اندر کافی لچک اور وسعت بھی رکھتا ہے ۔انسانی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کھانے پینے کا ہے۔ اسلام نے اس میں بہت دخل دیا ہے مگر اس دخل کی نوعیت بھی جدا ہے۔اسلام نے چند حرام اشیاء متعین کردی ہیں، اس کے علاوہ سب حلال ہیں،جب تک کہ ان کی حرمت نص سے ثابت نہ ہو جائے۔ایسے ہی سیاسی زندگی کی بابت اسلام بنیادی اصول طے کردیتا ہے کہ حاکمیت رب کریم کو حاصل ہوگی،قانون کا ماخذ شریعت ہوگی اور کاروبار حکومت چلانے والے اہل تقوی اور امین ہوں،جہاں شریعت الہی کی کوئی واضح ہدایت موجود نہ ہو وہاں سارے معاملات شوری کے ذریعے طے کئے جائیں۔
ایک مستشرق جان برٹن جو کہ برطانیہ کی ایک یونیورسٹی کا پروفیسر تھا،اس نے قرآن کی تدوین اور حفاظت پر ایک کتاب لکھی۔ وہ بہت زیرک اور چالاک انسان تھا،اس نے اپنے کام کو جوزف شاخت کے کام کا تسلسل بتایا حالانکہ شاخت کا کام حدیث پر اور اس کا کام قرآن کے اوپر تھا۔اس نے قرآن کریم کی ناسخ و منسوخ کے نظریے کو بنیاد بنایا اور کہا کہ قرآن کریم کی تدوین میں مصحف میں کچھ آیات جمع ہونے سے رہ گئی۔اس نے نسخ القرآن کی تین اقسام بیان کی ہیں۔
1. نسخ الحکم دون التلاوۃ: یعنی قرآن کریم میں کچھ آیات ایسی نازل ہوئی ہیں جن کا حکم منسوخ ہے مگر تلاوت باقی ہے۔ یہاں پر ایک بات ڈاکٹر اکرم رانا صاحب نے شاہ ولی اللہؒ کی الفوز الکبیر کے حوالے سے لکھی ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک آیات منسوخہ کی تعداد 500 ہے جبکہ شاہ صاحب کی اپنی تحقیق کے مطابق آیات منسوخہ کی تعداد 5 ہے۔
2. دوسری قسم “نسخ التلاوۃ دون الحکم” اس سے مراد ایسی آیت ہے جس کی تلاوت منسوخ ہے مگر حکم باقی ہے جیسے کہ رجم کے بارے میں آیات۔
3. نسخ الحکم و التلاوۃ : وہ آیات جن کی تلاوت اور احکام دونوں منسوخ ہیں۔ایسی آیات کا تعین کرنا بھی مشکل ہے، اس لیے ڈاکٹر اکرم رانا نے اس کی تفصیل نہیں بتائی۔
قرآن کی قراءت کے اختلاف پر آسٹریلوی مستشرق آرتھر جیفری نے کام کیا جس کا جائزہ ڈاکٹر اکرم چوہدری صاحب نے لیا ہے۔وہ لکھتے ہیں کہ جیفری کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اسلام قرآن کے بغیر قطعی طور پر زندہ نہیں رہ سکتا،اس کے برعکس عیسائیت بائیبل کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے۔شاید اس وجہ سے اس نے قرآن کی قراءت کے اختلاف پر خصوصی طور پر کام کیا۔
آخری مضمون اسماعیل ابراہیم نواب صاحب کا ہے جس میں استشراق کی تاریخ کا جائزہ لیا ہے،وہ لکھتے ہیں کہ 16ویں صدی میں چرچ کی داخلی لڑائی پر فریقین اپنے خبث باطن کی وجہ سے اسلام کو بیچ میں گھسیٹ لائے۔17 ویں صدی میں Henry Stubbe جیسے چند اہل علم نے جرات کا مظاہرہ کیا،انھوں نے اسلام اور آپ ﷺ کے بارے میں بے لاگ تحریریں رقم کیں مگر وہ ان کو شائع کرنے کی ہمت نہیں کرسکے۔ خود Stubbe کی تصنیفات 20ویں صدی سے پہلے منظر عام پر نہ آسکیں۔روشن خیالی نے مغرب میں بے شمار لوگوں کو مذہبی تعصب توڑنے پر آمادہ کیا اور انھوں نے اسلام اور آپ ﷺ کے بارے میں معروضیت اور احترام کے ساتھ مطالعے کا آغاز کیا۔ایسے میں کچھ لوگ ایسے میں تھے جو محض اہل کلیسا کو چڑانے کے لیے اسلام اور آپ ﷺ کی تعریف کرتےتھے۔پھر کچھ مستشرقین اسلام کے مطالعے کی وجہ سے مسلمان بھی ہوئے جیسے کہ مارٹن لنگس،تھامس ارونگ وغیرہ۔ کئی مستشرقین نے مسلم عیسائیت تعلقات خراب کرنے میں پورا کردار ادا کیا اور اپنے تخریبی مواد سے اس خلیج کو مزید وسیع کیا۔مگر مغرب میں بھی سنجیدہ اور مخلص لوگ موجود ہیں جن میں سب سے بڑی مثال Karen Armstrong ہے جو کہ ایک صاف ذہن (صاحب مضمون کے مطابق، ورنہ یہ درست نہیں) اور صاحب مطالعہ شخصیت ہیں۔مستشرقین اسلام یا آپ ﷺ کے بارے میں کوئی بھی رائے اپنے ثقافتی،مذہبی اور تاریخی پس منظر کے تحت لکھتے ہیں، اس لیے اس کا ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے۔
اگر کوئی شخص استشراق پر معلومات حاصل کرنا چاہے تو یہ کتاب کافی معاون ثابت ہوسکتی ہے حالانکہ اس میں صرف ایک پہلو “شریعت” کے بارے میں ہے لیکن مجھے اس سے کافی معلومات ملیں۔




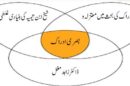
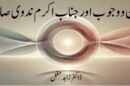












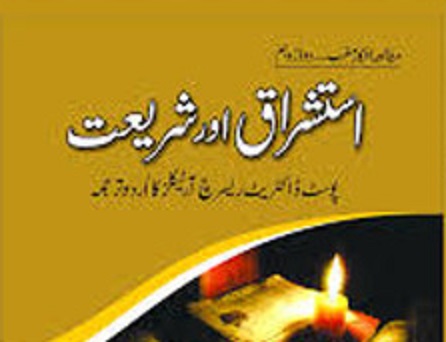
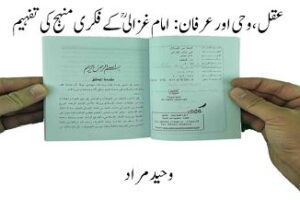
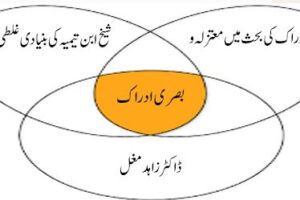
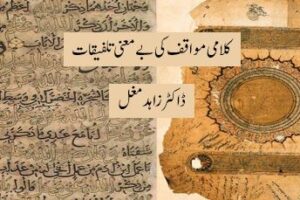
کمنت کیجے