خدا کی اس دنیا میں کچھ ایسے انسان بھی جنم لیتے ہیں جن کے وجود میں بصیرت کی ضیا، فکر میں تدبر کی گونج، اور بیان میں معانی کی تابندگی ازل سے پیوست ہوتی ہے۔ وہ علم کو تراشتے، اس میں نئی روح پھونکتے، اور اُسے شعور و آگہی کی ایک زندہ علامت بنا دیتے ہیں۔ ان کی فکر میں دریافت کی تڑپ، جستجو میں تلاش کی لے، اور پیشکش میں نئی پہچان تخلیق کرنے کا وہ ملکہ ہوتا ہے جو ماضی کو منفرد زاویے عطا کرتا، نظریات کو تجدید کا رخ دکھاتا، اور روایت کی سوئی ہوئی رگوں میں بیداری کی ایک تازہ سانس دوڑا دیتا ہے۔
علم ان کے نزدیک معلومات کا کوئی بے روح انبار نہیں ہوتا، نہ ہی حافظے کی کوئی ساکت میراث ہوتا ہے؛ اُن کے نزدیک علم ایک ایسا زندہ، بیدار اور متحرک شعور ہوتا ہے جو انسانی عقل کی تہوں میں اترے، جامد افکار کو جنبش دے، اور فہم کی بند راہوں کو ادراک کی روشنی سے منور کر دے۔ وہ صرف سوچنے والے نہیں ہوتے، بلکہ سوچ کو برت کر ایک تخلیقی اظہار میں ڈھالتے ہیں۔ اور جب وہ علمی روایت کا حصہ بنتے ہیں، تو اس میں محض اضافہ نہیں کرتے، بلکہ اس کی تشکیلِ نو کر دیتے ہیں۔
ایسے عبقری، نابغۂ اور غیر معمولی اذہان روز روز پیدا نہیں ہوتے، صدیاں اُن کے انتظار میں کھڑی رہتی ہیں۔ لیکن جب وہ نمودار ہوتے ہیں تو فکر و دانش کی تاریخ کا دھارا بدل دیتے ہیں۔ اور جب یہی فکری رفعت، اجتہادی بصیرت اور تخلیقی قوت کسی ایک ہستی میں یکجا ہو جائے، تو وہ محض ایک عالم نہیں رہتا، وہ خود ایک دور کی فکری تشکیل کا محور بن جاتا ہے۔
مسلمانوں کی علمی روایت میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ ایسی ہی ایک ہمہ جہت شخصیت تھے، جن کی ذات میں یہ تمام جہات اس طرح سمٹ آئیں کہ وہ بیسویں صدی کے افق پر ایک مستقل مکتبِ فکر کی صورت میں جلوہ گر ہوئے۔
اُن کی یہ غیر معمولی حیثیت محض کوئی جذباتی اعتراف یا وقتی شہرت کا حاصل نہ تھی، بلکہ ایک ایسی اصولی، متعین اور قابلِ تصدیق عظمت تھی جسے دین کی فکری روایت کے مسلمہ معیارات کی روشنی میں پرکھا جا سکتا ہے۔
اس روایت میں کسی مفکر کے مقامِ علم و اثر کو جانچنے کے لیے چار بنیادی معیار ہیں:
پہلا دائرہ اُن علما پر مشتمل ہے جنھوں نے اسلامی علوم کی بنیاد رکھنے کے لیے وہ فنون مرتب کیے جو فہمِ دین، اس کی تعبیر اور مؤثر ابلاغ کے لیے ناگزیر تھے۔ یہ وہ تمام لسانی و عقلی علوم تھے جن کے ذریعے الفاظ کی دلالت، جملوں کی ساخت اور معانی کی تعیین کی جاتی ہے،یعنی نحو، صرف، لغت، علمِ معانی، بیان، بدیع، اور منطق جیسے فنون۔ ان علوم کی نوعیت اصولی اور آفاقی تھی، جو صرف دینی متون ہی نہیں بلکہ ہر نوع کے فکری و ادبی نصوص کی تحلیل کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ ان علوم نے بعد ازاں اطلاقی صورتیں بھی اختیار کیں ، جیسے علمِ جرح و تعدیل یا مصطلحات حدیث اور دیگر ایسے فنون جن میں انہی آلات کو مخصوص دینی مقاصد پر منطبق کیا گیا۔ ان علوم نے اسلامی روایت کو ایک ایسی فکری و لسانی بنیاد عطا کی جس کے سہارے نہ صرف نصوص کو سمجھا گیا، بلکہ دین کے ماخذ کی ترسیل، تدریس اور حفاظت کے باقاعدہ اسالیب بھی وضع ہوئے۔ ان علوم کی تدوین میں جن جلیل القدر اہلِ علم نے حصہ لیا، وہ دراصل اس علمی عمارت کے معمار تھے جس پر پوری اسلامی روایت استوار ہے۔ خلیل بن احمد، سیبویہ، عبد القاہر جرجانی، خطیب بغدادی،زمخشری اور ابن حجر جیسے اکابر اسی دائرے کی نمایندہ شخصیات ہیں۔وہ مفکرین جنھوں نے زبان و بیان کے وسائل کو وضع کیا، فہمِ نص کے ذرائع فراہم کیے، اور علمی روایت کی اساس بننے والے علوم کو منقح و منظم کیا۔
دوسرا دائرہ اُن اصحابِ علم پر مشتمل ہے جنھوں نے انھی فنی اور لسانی علوم میں اختصاص پیدا کر کے دین کی شرح، تعبیر اور استدلال کا ایک منظم، مربوط اور اصولی نظام وضع کیا۔ ان علما نے صرف نصوص کو سمجھنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اُنھیں ایک علمی فریم ورک میں ڈھال کر فقہ، کلام اور تفسیر جیسے فنون کی تشکیل کی۔وہ اصولی و اجتہادی علوم جن کے ذریعے دینی فکر کو استدلالی قوت، منطقی ربط اور فقہی نظم حاصل ہوا۔ اس عمل نے اسلامی فکر کو ایک مستقل مکتبِ نظر عطا کیا، جو علمی قواعد پر استوار تھا اور جس میں مذہبی روایت کی تعبیر باقاعدہ ضوابط کے تحت انجام پانے لگی۔
شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، احمد بن حنبل، رازی اور دیگر جلیل القدر علما اسی دائرے کی شخصیات ہیں،وہ مفکرین جنھوں نے دینی فکر کو مجرد ثبوت سے نکال کر ایک ہم آہنگ، قابلِ استدلال اور اصولی و منضبط علمی روایت میں ڈھالا۔ انھی کے ذریعے فقہ کے اصول مرتب ہوئے،علم کلام کی صورت میں عقائد کا دفاع منظم ہوا، اور نصوص کی تشریح میں تفسیر کا علم کی ایک باقاعدہ جہت بن گیا۔ یوں یہ دائرہ اسلامی فکر کی داخلی ترتیب، نظریاتی گہرائی، اور استدلالی پختگی کی علامت بن کر ابھرا۔
تیسرا دائرہ اُن مفکرین پر مشتمل ہے جنھوں نے روایت کو محض قائم شدہ نظریات کی صورت میں قبول کرنے کے بجائے اس کا گہرا مطالعہ کیا، اس کی تہوں میں اترے، اور اس کا تنقیدی جائزہ لیا۔ انھوں نے روایت کو ازسرِ نو علم و عقل کی کسوٹی پر پرکھا، اور نئی فکری جہات کی روشنی میں اسے سمجھنے کی سعی کی۔
یہ وہ اذہان تھے جنھوں نے روایت کے ظاہری جلال و جمال سے مرعوب ہونے کے بجائے اس کی داخلی ساخت، فکری منطق، اور استدلالی بنیادوں کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔انھوں نے اُن پہلوؤں کو نمایاں کیا جہاں روایت، وقت کے دھارے کے ساتھ، فکری جمود، سطحی تعبیرات، اور بعض متضاد مفروضات کا شکار ہو گئی تھی۔ ان کی تنقیدی سوچ نے روایت کو محض ماضی پرست ورثہ نہیں رہنے دیا، بلکہ ایک اور تازہ فکر میں ڈھال کر نئی نسلوں کے سامنے رکھا۔ ابن ،رشد،ابن خلدون،ابن قیم ،اقبال و رشید رضا جیسے مفکرین اسی دائرے کی نمایندہ شخصیات ہیں۔
چوتھا اور آخری دائرہ اُن مجتہدین پر مشتمل ہے جنھوں نے تدوین، تنقید اور روایت ان تینوں بنیادوں کو ہم آہنگ کر کے، ایک ایسی جامع تعبیرِ دین پیش کی جو نہ صرف ماضی سے جڑی ہوئی تھی بلکہ حال اور مستقبل سے بھی ہم کلام تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں علم محض تصنیف یا تنقید نہیں رہتا، بلکہ اصول سے اطلاق تک ایک نئی روح، ایک زندہ تجربہ، اور ایک منظم نظامِ فکر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ابن تیمیہ، غزالی، شاہ ولی اللہ ، اور فراہی اسی دائرے کے نمایندہ مفکرین ہیں۔
وہ اہلِ فکر جنھوں نے دین کو ایک مکمل نظامِ حیات کی صورت میں نئے فکری قالب میں ڈھالا، ایسا قالب جو روایت سے بھی پیوستہ ہو، اور جدید انسانی شعور سے بھی ہم آہنگ ۔ ان کے ذریعے دینی فکر نہ صرف اپنی اساس پر قائم رہی، بلکہ استدلالی طاقت فکری پختگی، اخلاقی تازگی، اور تمدنی رہنمائی کے نئے امکانات سے بھی آشنا ہوئی۔گویا دین اپنے مقصد سے جڑ کر ایک عظیم بیانیہ بن گیا۔
جب ہم مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ جیسے مفکر کی علمی خدمات کا سنجیدہ جائزہ لیتے ہیں، تو سوال یہ نہیں رہتا کہ آیا وہ ایک جلیل القدر عالم تھے یا نہیں؛ اصل سوال یہ ابھرتا ہے کہ کیا اُنھوں نے اسلامی فکر کی اُس روایت میں ایسا اصولی، تخلیقی اور پائیدار اضافہ کیا ہے جو کسی عالم کو اُس روایت میں ایک بڑے آدمی کا درجہ دے دیتا ہے؟ کیا اُن کی تحریریں صرف روایت کی بازگشت تھیں، یا اُنھوں نے دین کو ایک ایسے منظم فکری نظام میں ڈھالنے کی سعی کی جو علمی تدوین، فکری تنظیم، تنقیدی بصیرت اور تعبیرِ نو،ان سب کے امتزاج سے ماضی کی روح سے پیوستہ بھی ہو، اور عصرِ حاضر کے سوالات سے بامعنی مکالمہ بھی کر سکے؟ اُن کے علمی کام کا جائزہ انہی چار فکری جہات کے زاویے سے لینا ناگزیر ہے۔
چنانچہ مولانا کی علمی عظمت کا پہلا مظہر فہمِ دین کے اُن لسانی و عقلی ذرائع میں نمایاں ہوتا ہے جن میں زبان، اصطلاحات، دلالت اور بیان شامل ہیں اور جن کی اصولی ترتیب اور فکری تجدید مولانا کی تحریروں کا امتیازی وصف ہے۔ یہ وہ دائرہ ہے جہاں مولانا کی تحریریں محض فصاحتِ بیان یا ادبی جمالیات کا مظہر نہیں، بلکہ اسلامی فکر کی مفہوم سازی اور اس کی کلیدی اصطلاحات کی ازسرِنو تشکیل کا عملی اظہار ہیں۔ اُنھوں نے اردو زبان کو صرف دینی ابلاغ کا وسیلہ نہیں سمجھا، بلکہ اسے ایک باقاعدہ علمی و فکری زبان کا درجہ دیا،ایسی زبان جو دین کے اساسی تصورات کو گہرائی، وضاحت، اور فکری ربط کے ساتھ پیش کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہو۔اس جدوجہد کی سب سے نمایاں جہت دینی اصطلاحات کی نئی فکری تعبیر ہے۔
مولانا نے “رب”، “الٰہ”، “دین”، “عبادت”، “اطاعت”، “شریعت”، “نظامِ زندگی”، “قانونِ الٰہی”، “اتمامِ حجت” اور” طاغوت”جیسے بنیادی تصورات کو ان کے روایتی لغوی یا رسمی معانی سے نکال کر ایک منضبط اور مربوط نظریاتی نظام کے اجزاء میں ڈھال دیا۔
ان کے نزدیک “رب” محض خالق یا رازق نہیں، بلکہ وہ مقتدر و مربی ہستی ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو پر اپنی حکمت، تربیت، اور قانون سازی کے ساتھ محیط ہے۔ “الٰہ” صرف رسمی معبود نہیں، بلکہ وہ واحد مقتدر ذات ہے جس کی اطاعت اور وفاداری، مکمل اور بلا شرکتِ غیرے، شعوری التزام کے ساتھ مطلوب ہے۔ “دین” کوئی مجرد روحانی تجربہ یا انفرادی اخلاقی ضابطہ نہیں، بلکہ ایک ہمہ گیر تہذیبی اور تمدنی نظام ہے۔ “عبادت” صرف مخصوص اعمال کا نام نہیں، بلکہ شعوری اطاعت، نظریاتی وفاداری اور ہمہ جہت بندگی کا جامع مظہر ہے۔ “اطاعت” کوئی وقتی یا جزوی رویہ نہیں، بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں استقامت اور طرزِ وفاداری کا نام ہے۔ “اتمامِ حجت” محض تبلیغی فریضہ نہیں، بلکہ دعوت، ابلاغ، اور مکانی و زمانی تناظر میں انجام پانے والا ایک ایسا کامل اخلاقی عمل ہے، جس کے بعد انسان اللہ کے عدل کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔اور”طاغوت” اُن تمام غیر الٰہی طاقتوں، نظاموں اور مقتدر قوتوں کا نمائندہ ہے جو انسان کو بندگیِ رب سے ہٹا کر اپنی اطاعت اور وفاداری کا اسیر بنانا چاہتی ہیں۔
صحیح اور غلط سے قطع نظر مولانا نے ان اصطلاحات کو فقط الگ الگ وضاحتوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ان کے مابین ایک گہرا نظریاتی اور عملی ربط قائم کیا۔ ان کی تحریروں میں یہ تمام بنیادی تصورات اس انداز سے مربوط ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ہم آہنگ، مکمل فکری نظام کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ایسا نظام جو جدید ذہن کے لیے نہ صرف قابلِ فہم ہے، بلکہ عقلی طور پر مربوط اور تہذیبی سطح پر مدلل بھی ہے۔
ان علمی خدمات کی نمایاں مثالیں اُن کی تصانیف خطبات، دینِ حق، اسلامی تہذیب کے اصول و مبادی، اور اسلام کا نظامِ حیات ہیں، جن میں ان اصطلاحات کی فکری عمق کے ساتھ وضاحت کی گئی اور اُن کی تہذیبی معنویت کو نمایاں کیا گیا۔ تاہم، ان تمام کاوشوں کا نقطۂ عروج تفہیم القرآن میں سامنے آتا ہے، جو محض ایک تفسیری کوشش نہیں بلکہ ایک مفہومی، اصطلاحی اور فکری ترجمہ ہے۔ اس تفسیر میں مولانا نے قرآنی اصطلاحات کو صرف لغوی سطح پر واضح نہیں کیا، بلکہ اُنھیں سیاق و سباق، دلالت، اور نظریاتی نظام کی روشنی میں بیان کیا۔ یہ عمل محض لسانی مہارت نہیں بلکہ ایک ہمہ گیر فکری، اصولی اور تہذیبی منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔
چنانچہ مولانا مودودیؒ علمی آلات و سائل کی تشکیل کے اس پہلے دائرے میں کسی جزوی یا اطلاقی سطح تک محدود نہیں، بلکہ ایک تجدیدی مقام رکھتے ہیں۔ اُنھوں نے نہ صرف دینی اصطلاحات کو نئی فکری معنویت دی، بلکہ ایک ایسا اصطلاحی نظام قائم کیا جو اسلامی روایت کے فکری عمارت کو جدید انسانی ذہن کے لیے نہایت وضاحت، تسلسل اور قوتِ استدلال کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ یہ کارنامہ کسی متوسط داعی، مترجم یا خطیب کا نہیں، بلکہ اُس مفکر کا ہی ہوسکتا ہے جو دین کی فکری تاسیسِ کی اہلیت بھی رکھتا ہے اور اس کے لیے وہ نئے آلات بھی فراہم کردے ۔
مولانا مودودیؒ کی علمی عظمت کے تعین کا دوسرا نمایاں میدان وہ ہے جہاں دینی افکار، احکام اور تصورات کو ایک اصولی، منضبط اور استدلالی فکری نظم میں ڈھالا جاتا ہے۔ یہ وہ دائرہ ہے جس میں دین محض جزوی احکام کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مربوط فکری ڈھانچے کی صورت اختیار کرتا ہے، جس کی ہر تعبیر، ہر دلیل، اور ہر تشریح ایک اصولی نظام کے تابع ہو۔ مولانا مودودیؒ اس دائرے میں محض کسی مسئلے کے شارح یا روایتی فقیہ نہیں بلکہ وہ مفکر ہیں جنھوں نے اسلامی فکر کو ایک استدلالی مزاج، ایک فکری وحدت، اور ایک منہجی ہم آہنگی عطا کی۔
اس دائرے میں ان کے کام کا یہ امتیازی وصف وہ کسی ایک فقہی دبستان کے پابند نہیں۔ اگرچہ ان کے علمی جھکاؤ میں حنفی مزاج کی وسعت نظر آتی ہے، لیکن وہ محض تقلید پر قناعت نہیں کرتے۔ چنانچہ جب وہ سود کے مسئلے پر لکھتے ہیں تو محض روایت کردہ فقہی اقوال پر انحصار نہیں کرتے، بلکہ قرآن کے اخلاقی تناظر، عدلِ اجتماعی کی روح، اور اقتصادی استحصال کی نفی کو بنیاد بنا کر اس کی حرمت کو اصولی اور زمانی استدلال کے ساتھ واضح کرتے ہیں۔ یہی اصولی طرز اُن کی دیگر تحریروں میں بھی نظر آتا ہے، جیسے پردہ کے معاملے میں جہاں وہ نہ صرف قرآنی آیات اور حدیث کے نصوص کا جائزہ لیتے ہیں بلکہ سیرتِ نبویؐ، سماجی تناظر، اور معاشرتی ضروریات کو ایک مربوط فکری منہاج میں سموتے ہیں۔
یہی اصولی بصیرت اُن کی اجتہادی کاوش کا جوہر ہے۔ وہ سلفی منہاج کی روایت پرستی اور فقہی منہاج کی اصولی ساخت کو ایک دوسرے کے مدِ مقابل نہیں رکھتے بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک فکری تطبیق قائم کرتے ہیں۔ ان کے یہاں نہ روایت کو مطلق مان کر عقل کی نفی کی جاتی ہے، نہ عقل کی حاکمیت میں نصوص کی تاویل کی جاتی ہے، بلکہ دونوں کو ایک توازن کے ساتھ برتا جاتا ہے۔ وہ اسلامی ریاست کے تصور میں اسی تطبیقی اصول پر عمل کرتے ہیں، جہاں وہ ایک طرف قرآن کی حاکمیت، شریعت کی بالادستی اور اطاعتِ خداوندی جیسے دینی اصولوں پر زور دیتے ہیں، اور دوسری طرف شورائی نظام، عوامی مشاورت، اور قانونی ڈھانچے کی وضاحت کرتے ہوئے جدید ریاستی تناظر کو اجتہادی اصولوں کے تحت ہم آہنگ کر دیتے ہیں۔
ان کا استدلالی منہج اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ وہ (issue-based) استدلال کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہر نیا سوال، ہر عصری مسئلہ ان کے ہاں صرف “فتویٰ طلب” نہیں ہوتا بلکہ ایک “فکر طلب” ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اختلاف کو علمی عمل کا فطری نتیجہ سمجھتے ہیں اور اسے اپناتے ہیں چاہے وہ عورت کے پردے کی نوعیت ہو، یا بینکنگ سود کی ماہیت، یا اتمامِ حجت کی قرآنی تعبیرپر ۔ اتمامِ حجت کے باب میں خصوصا وہ محض روایت پر انحصار نہیں کرتے، بلکہ قرآن کے اسلوبِ دعوت، تاریخِ انبیاء، اور انسانی فطرت کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک اجتہادی مفہوم تشکیل دیتے ہیں، جس میں عقل، نص اور تاریخ تینوں کی ایک مشترک حقیقت کے وکیل بن جاتے ہیں۔
یہی فکری ہم آہنگی اُن کی کتابوں اسلامی نظامِ حیات، اسلام کا نظریۂ سیاسی، اسلامی ریاست، رسائل و مسائل، اور تفہیم القرآن میں مسلسل جلوہ گر ہے۔ ان کی تحریروں میں محض دینی تعبیر نہیں، بلکہ استدلال کا ایک منہج، تعبیر کا ایک اصول، اور اجتہاد کی ایک فکری تحریک موجود ہے۔
یہ سب کچھ اس بات کا بیّن ثبوت ہے کہ مولانا مودودیؒ نے فہمِ دین کے اس دوسرے دائرے میں محض جزئی تشریحات نہیں کیں بلکہ استدلال، اصول اور نظمِ فکر کی سطح پر ایک ایسی تجدیدی کاوش انجام دی جس نے اسلامی فکر کو ایک نئے اجتہادی قالب میں ڈھالا۔ ان کا اجتہاد نہ روایت سے منقطع ہے نہ جدیدیت سے مرعوب؛ وہ دین کو عقل، وحی اور انسانی تجربے کے درمیان تفاعل کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور یہی کسی مفکر کے عہد ساز ہونے کی دوسری بڑی دلیل ہے۔
تیسرا دائرہ تنقیدی احتساب اور فکری بیداری کے شعور کا ہے۔یہ مودودی صاحب کی فکری عظمت کا وہ پہلو ہے جو ان کے اجتہادی اسلوب کا نہ صرف لازمی حصہ ہے بلکہ ان کی تحریروں میں ایک مستقل فکری جہت کے طور پر نمایاں ہوتا ہے۔ وہ روایت کے تقدس کے منکر نہیں، لیکن روایت کو جامد، ناقابلِ سوال یا مطلق ماننے کے قائل بھی نہیں۔ ان کے نزدیک روایت، خواہ وہ فقہی ہو یا تفسیری، حدیث و آثار پر مشتمل ہو یا تصوفیانہ افکار پر، اگر کسی مقام پر فکری جمود، طبقاتی مفادات، یا اجتہادی تعطل کو جنم دے رہی ہو تو اس کا علمی، باوقار اور مدلل احتساب فرضِ منصبی بن جاتا ہے۔
مولانا کا یہ تنقیدی رویہ ہمیں سب سے واضح صورت میں اُن کی کتاب تنقیحات اور خلافت و ملوکیت میں ملتا ہے، جہاں وہ موروثیت پر سوال اٹھاتے ہیں، جسے بعد کی اسلامی تاریخ میں سیاسی مصلحت کے نام پر ایک دینی قدر میں بدلنے کی کوشش کی گئی۔ وہ مقلدانہ فقہ کے خلاف بھی آواز اٹھاتے ہیں، جس نے فقہی اجتہاد کو محض فتاویٰ کی پیروی میں محدود کر دیا، اور دین کو نئے مسائل کے سامنے لاچار بنا دیا۔ مثال کے طور پر وہ وصیت کے حق سے متعلق احادیث کو زیرِ تنقید لاتے ہیں جنھیں بعض فقہی مکاتب نے وارثوں کے لیے وصیت کی ممانعت کے طور پر مطلق سمجھا، حالانکہ قرآن اسے ایک حق کے طور پر پیش کرتا ہے۔ مولانا یہاں محض حدیث کو رد نہیں کرتے بلکہ اس کے دائرے، نزولی سیاق، اور فقہی اطلاق پر اجتہادی غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔
اسی طرح وہ تصوف کی ہدایات، جیسے “تصور فقر” یا ” فنا فی الشیخ”، پر بھی سوال اٹھاتے ہیں، اور ان کی تعبیرات کو قرآن و سنت کی روشنی میں فکری چھان بین کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ تصورات اگر انسان کی آزادی، اخلاقی خودی، اور توحیدیل کے شعور کو مجروح کرتے ہیں، تو ان پر تنقید واجب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کئی احادیث کے بارے میں بھی علمی توقف سے کام لیتے ہیں، مثلاً وہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے جیسی حدیث کو اس کے ظاہری مفہوم میں لینے کے بجائے اس کی روحانی معنویت، زمانی سیاق، میں سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں۔
یہی تنقیدی جرأت انھیں اسلامی شریعت کے طبقاتی اطلاقات پر بھی اظہارِ رائے کا حوصلہ دیتی ہے۔ ان کے نزدیک شریعت کے بعض اطلاقات، جیسے زنا میں گواہی کے سخت ترین ضوابط یا حدود کے نفاذ میں دگنی شہادت کا تصور، اگر معاشرتی انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنیں، تو ان کی فقہی حکمت اور معاشرتی افادیت پر دوبارہ غور کیا جانا چاہیے، نہ کہ انہیں جامد قانون مان کر نافذ کر دیا جائے۔
مولانا کی یہ تنقید صرف مسلم روایت تک محدود نہیں بلکہ وہ مغربی فکر کے ان اثرات پر بھی علمی نقد کرتے ہیں جو سیکیولرزم، نیشنلزم، اور سائنسی مادّیت کے نام پر انسانی خودی، اخلاق، اور وحی کی بالادستی کو چیلنج کرتے ہیں۔ ان کی کتاب اسلام اور جدید ذہن کے اشکالات میں اسی احتسابی شعور کی توسیع ہے، جہاں وہ نہ صرف مغربی فکر کے علمی ابہام کو بے نقاب کرتے ہیں بلکہ اسلامی فکر کی خودمختار حیثیت کو بھی بازیافت کرتے ہیں۔
یہ تمام تنقیدی پہلو نہ کسی تخریبی ذہنیت کی پیداوار ہیں، نہ ضد اور انکار کے جذباتی ردعمل کا نتیجہ۔ مولانا مودودیؒ کی تنقید علمی ذہانت، اجتہادی دیانت اور تہذیبی شعور کا مظہر ہے، جو نہ صرف روایت کے مہیب سناٹے میں ایک اجتہادی صدا ہے بلکہ فکرِ اسلامی کے احیا کی شرطِ اوّل بھی۔ یہی وہ تنقیدی بصیرت ہے جس نے تقلید کی فصیلوں میں اجتہاد کی کھڑکیاں کھولیں، اور اسلامی روایت کو نئے دور کے سوالات سے مکالمہ کرنے کا حوصلہ دیا۔
فکری خدمات کے ان تینوں دائروں میں نمایاں خدمات کے بعد مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کا سب سے بڑا اور ہمہ گیر کارنامہ اُس سطح پر نمایاں ہوتا ہے جہاں وہ محض اصولوں کی توضیح یا مفروضات کی تحلیل پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ دین کو ایک ہمہ جہت، جامع اور مربوط نظامِ زندگی کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں اُن کا علمی و اجتہادی شعور ایک تہذیبی وژن میں ڈھل جاتا ہے، اور وہ محض ایک مفسر یا مفکر نہیں بلکہ ایک نئی تعبیر کے بانی اور منفرد فکر کے معمار طور پر سامنے آتے ہیں
یہ چوتھا اور سب سے جامع دائرہ وہ ہے جہاں مولانا مودودیؒ کی فکری، اجتہادی اور تجدیدی کوششیں ایک مکمل، مربوط اور عہد ساز تعبیرِ دین کی صورت اختیار کرتی ہیں۔ یہ وہ سطح ہے جہاں علم محض اصولوں کی تدوین یا روایت کی تنقید پر موقوف نہیں رہتا، بلکہ ایک نیا فکری اور تمدنی نظام تشکیل پاتا ہے ایسا نظام جو ماضی سے پیوست، حال سے ہم آہنگ، اور مستقبل کی راہیں روشن کرنے والا ہو۔
مولانا مودودیؒ نے دین کی فکری سمت کو ایک نئی جہت عطا کی۔ انھوں نے دین کی ایسی تعبیر پیش کی جسے بجا طور پر دین کی سیاسی تعبیر کہا جا سکتا ہے۔ یعنی دین کو محض انفرادی نجات، خانقاہی اخلاقیات یا عباداتی معمولات کے دائرے میں محدود رکھنے کے بجائے، ریاست کو نفاذِ دین کا مرکزی ادارہ قرار دے دیا گیا۔ ان کے نزدیک دین ایک ہمہ گیر ضابطۂ حیات ہے جو معاشرت، معیشت، قانون، سیاست، علم، اور تہذیب سمیت زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دین کی اس تعبیر کے بانی تصور کیے جا سکتے ہیں،ایسی تعبیر جس نے دین کو محض خطبہ و فتویٰ سے نہیں بلکہ ایک تمدنی، معاشرتی اور ریاستی نظام میں ڈھال دیا۔ اس زاویے سے دیکھیں تو مولانا نے پورے دین کو ایک نئی تہذیبی اور عملی جہت عطا کی۔
ان کی کتاب چار بنیادی اصطلاحات اسی تعبیری نظام کی فکری بنیاد ہے، جس میں قرآنی تصورات کو نئی معنوی گہرائی اور فکری وسعت دی گئی۔ وہ “اسلام” اور “جاہلیت” کے درمیان ایک نظریاتی لکیر کھینچتے ہیں، اور جدید مغربی تمدن کو “جاہلیتِ جدیدہ” کے طور پر متعارف کراتے ہیں۔ اس کے مقابل وہ ایک ایسا اسلامی نظام پیش کرتے ہیں جو روحانی، اخلاقی، قانونی اور سیاسی سطح پر انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔
اسی طرح اُن کی تحریریں جیسے تحریک اسلامی کا آئندہ لائحہ عمل، اسلامی دستور، ریاست کیا ہے؟ اور اسلامی معیشت کے بنیادی مسائل،یہ سب محض اصلاحی تجاویز نہیں بلکہ ایک جامع فکری و تمدنی وژن کی تشکیل ہیں۔ ان میں دین کو ایک باقاعدہ ریاستی و سماجی ماڈل کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، جس میں قانون، طاقت، اخلاق اور دعوت سب ایک مرکز کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
مولانا کی یہ تعبیر محض ایک فلسفیانہ موقف نہیں، بلکہ تحریکی شعور، فکری چیلنج، اور اجتہادی جرات کا ایک زندہ امتزاج ہے۔ اُنھوں نے دین کو محض کلامی اصطلاحات یا شخصی نجات کی سطح پر محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے تمدنی شعور اور عملی سیاست کی زبان میں ڈھالا۔ انھوں نے دین کے متفرق اجزا کو جوڑ کر ایک ایسا فکری نظام قائم کیا جو انسان، معاشرہ، اقتدار، علم، قانون اور اخلاق کو اندرونی ہم آہنگی کے ساتھ یکجا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو کسی بھی مفکر کو صرف عالم نہیں بلکہ ایک دورس، عہد ساز مفکر بنا دیتا ہے۔
یہی وہ مقام ہے جہاں مولانا کی شخصیت ایک مفسر، فقیہ یا مبلغ کی سطح سے بلند ہو کر ایک تہذیبی معمار، تحریکی مفکر اور اسلامی روایت کے مجدد کے طور پر ابھرتی ہے۔ایسا مفکر جو نہ صرف روایت کا امین ہے، بلکہ اس کا ناقد، مجدد، اور معمار بھی ہے۔
اصولی تدوین، فکری تنظیم ، تنقیدی احتساب، اور جامع تعبیر ان تمام میدانوں میں مولانا مودودیؒ کی آرا سے اختلاف ممکن ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود تاریخِ اسلام کا کوئی سنجیدہ قاری اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ مولانا مودودیؒ اس روایت کے ایک عظیم آدمی تھے۔ایسے مفکر جو اپنے عہد میں اسلامی فکر کو نئی سمت، نئی زبان، اور نئی قوت دینے والے فردِ واحد کی حیثیت رکھتے ہیں۔
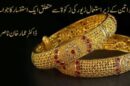
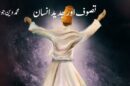
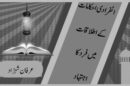
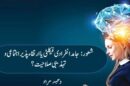














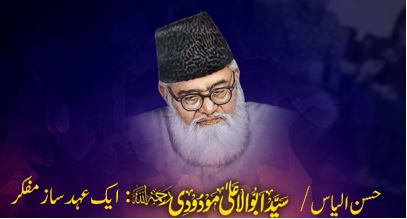



کمنت کیجے