ڈاکٹر محمد رضا کاظمی پاکستان کی تاریخ و سیاست اور بانیان پاکستان پر متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ پاکستان کی تاریخ پر ڈاکٹر کاظمی کی ایک کتاب A Concise History of Pakistan کو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کی ہے۔
ڈاکٹر کاظمی صاحب نے اس کتاب میں ایک جلد کے اندر پاکستان کی تاریخ کو قدیم ہندوستان سے لیکر پرویز مشرف کے دور تک ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں فقط سیاسی تاریخ کو ذکر نہیں کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ثقافتی ، معاشی اور علمی و ادبی تاریخ کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کاظمی صاحب کی اس کتاب کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تاریخ پاکستان کی مختلف جہات کو جامعیت سے ایک ہی والیم میں انہوں نے پیش کیا ہے۔
ڈاکٹر کاظمی صاحب نے اس کتاب کو دس حصوں اور چھیالیس ابواب میں تقسیم کیا ہے۔
پہلا حصے میں ابتدائیہ اور چار ابواب ہیں۔
جس میں عہد قدیم اور متوسط دور کے ہندوستان کیا تاریخ کو ذکر کیا ہے۔
ابتدائیہ میں آریاؤں کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ جس سے مقامی طور پر دریائے سندھ کی تہذیب میں بڑا بدلاؤ آیا۔ آریاؤں کی آمد اور قدیم ہند کی تہذیب کے زوال کے بارے میں زیادہ معلومات تو فراہم نہیں کیں مگر بتایا ہے کہ دریائے سندھ کی قدیم تہذیب کی تباہی پر حتمی طور پر کوئی اتفاقی مؤقف نہیں پایا جاتا کچھ لوگوں کے نزدیک یہ تہذیب قدرتی آفات کا شکار ہو کر ختم ہوئی تو کسی نے نزدیک آریا نسل نے آ کر اس تہذیب کو تباہ کیا۔
آریاؤں کی آمد سے ہند میں ایک بڑی تبدیلی آئی وہ مذہب کی تھی۔ ہندومت کا ارتقاء اور اس خطے کا غالب مذہب ان کی وجہ سے بنا۔ ڈاکٹر کاظمی نے ہندوؤں کی مقدس کتاب وید اور پھر چاروں وید یعنی رگ وید، سام وید، یجر وید اور اتھر وید کے مابین فرق کو مختصراً ذکر کیا ہے۔ وید کے ساتھ برہما ، اپنشد وغیرہ بھی ہندوؤں کے مقدس صحائف بھی قدیم ہند کی دستاویزات میں مشہور ہوتی ہیں۔ پھر ہندومت کے اندر سے ہی دو مزید مذاہب جین مت اور بدھ مت نے جنم لیا۔ یہ ہندؤ مت میں جاری نسلی امتیاز کے خلاف ایک ردعمل کے طور پر وجود میں ائے۔ جین مت تو زیادہ تر برصغیر میں ہی محدود رہا جبکہ بدھ مت برصغیر کے باہر بھی پھیلا۔ اس کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔
ہم کہہ سکتے ہے کہ مذہبی طور پر برصغیر ہندو مت کا راج تھا اور اس نے ہند کی تہذیب کی تشکیل میں بنیادی حصہ ڈالا۔
پہلے باب میں مسلمانوں کی برصغیر کی آمد کا ذکر ہے۔ ڈاکٹر کاظمی صاحب نے بتایا ہے کہ عرب ہند میں پہلے بطور تاجر آ کر بسے۔ مسلمان بھی ہند کے مغربی کنارے پر فتح سندھ سے پہلے آباد ہوئے۔ عرب اور ہند کی تجارت یکطرفہ تھی کیونکہ ہندی باشندے عرب نہیں جاتے تھے صرف عرب یہاں آتے تھے۔ جو عرب مغربی ہند کی طرف آباد ہوئے ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ کئی پانڈیا راجاؤں نے اپنے دربار میں جین مت اور بودھ مت کے ماننے والوں پر ان کو ترجیح دیکر اپنا وزیر بھی بنایا۔
عربوں کی سندھ فتح بارے میں مصنف کا کہنا ہے کہ یہ کسی ایک خاص واقعہ کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس وقت کی عرب فتوحات جو باقی دنیا میں جاری تھیں ان کی ایک کڑی تھی۔ سمندری قزاقوں والی بات بھی درست مانی جا سکتی ہے مگر اس پر راجا داہر بھی صیح تھا کیونکہ سمندری قزاق اس کی دست رست سے باہر تھے۔ لہٰذا یہ فتح کسی ایک خاص واقعہ کی وجہ سے نہیں تھی۔ سندھ کی فتح سے ہند کے اندر اسلام کا تعارف زیادہ بڑے پیمانے پر ہوا کیونکہ اب یہ فاتحین کا مذہب بھی تھا۔
مسلمانوں نے برصغیر پر کافی عرصے حکومت کی اس کے کچھ خطوں میں اسلام بھی پھیلا مگر پھر بھی ہندؤ ہمیشہ اکثریت میں رہے۔ حالانکہ بڑی تعداد میں ہندوؤں نے اسلام بھی قبول کیا مگر اکثریتی مذہب ہندومت ہی رہا۔
ہندوؤں کے اسلام کو اپنانے میں ایک نظریہ تو یہ پایا جاتا ہے کہ اسلام میں چونکہ ذات پات کا کوئی تصور نہیں تو نچلی ذات کے ہندوؤں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا لیکن اس پر ڈاکٹر کاظمی صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ اگر یہ بات درست ہے تو ہندوؤں کے لیے جین مت یا بدھ مت کو اختیار کرنا زیادہ آسان تھا کیونکہ وہاں بھی ذات پات نہیں پائی جاتی باقی عقائد میں تو وہ ہندوؤں کے نزدیک ہیں۔ یہ درست بات ہے ممکن ہے ذات پات کی وجہ سے بڑی تعداد ہندؤ مت سے اسلام میں داخل ہوئی ہو مگر یہ کوئی زیادہ ٹھوس وجہ نہیں ہے یہاں پر لوگوں کے مسلمان ہونے کی۔اس کی مزید بھی وجوہات ہیں
دوسرے باب میں ڈاکٹر کاظمی صاحب نے ہندؤ اور مسلم سوسائٹی کے فرق کو بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک اہم نکتہ بیان کیا ہے ہندؤ مت میں ذات پات کے تصور کی وجہ سے ایک طبقہ ہمیشہ سے بالاتر رہا جبکہ اسلام میں فضلیت کا معیار تقوی ٹھہرا ۔ لہذا مسلمان کسی نچلے طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود یہ فضیلت پا سکتا تھا۔ گوکہ مسلمانوں میں بھی طبقاتی تقسیم موجود تھی لیکن ایک فرق تھا کہ مسلمانوں کی یہ تقسیم نظام کی وجہ سے تھی جبکہ ہندوؤں میں یہ تقسیم مذہب کی وجہ سے تھی۔
یہاں پر مسلمانوں کے راگ اور ہندؤوں کے راگ میں بھی فرق کو ڈاکٹر کاظمی صاحب نے ذکر کیا اور بتایا ہے کہ خواجہ امیر خسرو مسلمانوں میں پہلے شخص تھے جنہوں نے ہندؤ راگ کو بھی اہمیت دی۔
موسیقی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں اور ہندوؤں کے آرٹ ، پینٹنگ ، ادب اور طرزِ تعمیر میں بھی فرق تھا۔ یہاں پر کچھ تحریکیں چلی جس میں ہندؤوں اور مسلمانوں کو ملانے کی کوشش کی گئی۔ وحدت ادیان کے حوالے سے بھی کوششیں ہوئیں مگر اسلام اور ہندومت میں ایک بنیادی فرق جس سے یہ کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتیں وہ توحید اور شرک عقیدہ ہے۔ اس پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتہ ممکن نہیں۔ اس لیے وحدت ادیان والی یا دونوں مذاہب کو ملانے والی تحریکیں کوئی زیادہ اثر نہ ڈال سکیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ یہ بے اثر رہیں ، انہوں نے اپنا اثر بھی چھوڑا۔ اکبر کے عہد کا دین الہی اس کی ایک شکل تھی۔ پھر وحدت الوجود کی ایسی تعریف جو اس کے لیے معاون ہو رہی تھیں یہ سب اس کے ہی اثرات تھے۔ ایسے ہی مصنف نے بتایا کہ اسلام کے اثرات ہندؤ معاشرت پر بھی پڑے جس کا کئی ہندؤ مصنفین نے ذکر بھی کیا ہے۔
تیسرے باب میں علماء اور صوفیاء کے کردار پر ہے۔ مصنف نے بتایا کہ علماء زیادہ تر بادشاہ کے دربار سے وابستہ ہوتے تھے جبکہ صوفیاء کا زیادہ واسطہ عام لوگوں سے ہوتا تھا۔ صوفیاء کی سادہ زندگی اور وسیع المشربی کے باعث عام آدمی کا تعلق ان کے ساتھ اور خانقاہوں کے ساتھ جڑا۔ مصنف نے برصغیر کے چند مشہور صوفیاء حضرت علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ، خواجہ بہاؤ الدین زکریا کا ذکر کیا اور بتایا کہ جیسے یہ لوگ عام عوام سے جڑے ہوئے تھے تو اس کے ساتھ بادشاہ وقت کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خواہ دوستانہ ہو یا مخالفت پر مبنی چلتے رہتے تھے۔ ایک اور اہم نام حضرت مجدد الف ثانی کا ہیں جنہوں نے براہ راست بادشاہت سے ٹکر لی اور اکبر کے دین الٰہی کے خلاف آواز بلند کی۔ ڈاکٹر کاظمی صاحب نے شیخ مجدد کے نظریات اور دعوؤں کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ مصنف نے ان کے نظریہ قیومیت پر سوال اُٹھایا ہے۔ نیز لکھا کہ یہ بات بھی کافی مشکوک ہے کہ ان کو سزا جہانگیر کے آگے جھکنے کے انکار کی وجہ سے ہوئی کیونکہ بادشاہوں کو سجدہ تعظیمی کرنے کی روایت مغلوں نے نہیں بلکہ غیاث الدین بلبن کے دور سے چلی آ رہی تھی۔ پھر چشتی مشائخ بھی سجدہ تعظیمی کرتے تھے۔
ڈاکٹر کاظمی نے ایک اور تاثر کی نفی کی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر شیخ مجدد کی تعلیمات سے متاثر تھا بلکہ درحقیقت اورنگزیب نے ان کی کتابوں پر پابندی لگائی جبکہ اس کے برعکس داراشکوہ شیخ مجدد کا عقیدت مند تھا۔
شیخ مجدد کی شخصیت برصغیر کی مسلم تاریخ میں ایک اہم شخصیت ہے۔ انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کے مذہبی میلاپ کی تمام سابقہ کوششوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ اس کا اعتراف ڈاکٹر کاظمی صاحب کو بھی ہے، حالانکہ انہوں نے شیخ مجدد الف ثانی کا تعارف کوئی زیادہ مثبت انداز میں نہیں کرایا۔ انہوں نے ایک اور دلچسپ بات لکھی کہ شیخ مجدد کا قائد اعظم محمد علی جناح پر ذرا اثر نہیں جبکہ ان کے مخالف مولانا ابوالکلام آزاد پر بہت زیادہ اثر تھا۔۔ شیخ مجدد الف ثانی کے ساتھ ساتھ اس باب میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی ہے۔
چوتھے باب میں مسلمانوں کے زوال اور برطانیہ کی برصغیر پر حکومت کا ذکر ہے۔ مغلوں کے زوال پر ڈاکٹر کاظمی صاحب نے روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ اورنگزیب کے بعد کے حکمرانوں میں امور سلطنت چلانے کی صلاحیت نہیں تھی۔ لیکن مغلیہ سلطنت کا زوال اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا۔ اورنگزیب کے دور میں ہی ہونے والی جنگوں سے سلطنت کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر مغلوں کے مابین ہونے والی خانہ جنگیاں بھی اس زوال کے بڑے اسباب تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مغلیہ سلطنت کی فوج اپنے ذیلی علاقوں کے رؤسا کی مرہونِ منت تھے۔ جب بھی ان کو جنگ کی صورتحال درپیش ہوتی تو وہ زمینداروں کو کہتے اور وہ ان کو لڑنے کے لیے لوگ دیتے۔ جنگ میں فتح کی صورت میں متعلقہ زمیندار کو رقم ملتی اور وہ فوج میں تقسیم کرتا۔ جب مغل شہزادوں کے درمیان بھی خانہ جنگی ہوتی تو بھی اپنے حمایت یافتہ امرء سے فوجی کمک حاصل کرتے ، اس دوران فاتح شہزادہ کے غضب کا نشانہ وہ امرء بھی بنتے جنہوں نے مفتوح شہزادے کی مدد ہوتی۔ وہ لوگ اپنے جاگیر اور مناصب سے محروم ہوتے۔ وقت کے ساتھ فوج کی ادائیگیوں میں بھی تاخیر ہوتی گئی جس کی وجہ فوج لڑنے کو دستیاب نہ ہوتی جبکہ دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی اپنا مال باہر بھیجتی تھی تو اس کو مالی پریشانی نہیں تھی۔ لہٰذا اس کو مقامی سطح پر فوج میسر آ گئی جس کو بروقت ادائیگی کرتے تھے اور ان کے گھوڑوں کی خوراک کا بھی انتظام کرتے تھے۔ لہٰذا انگریزوں کے پاس ایک ایسی فوج تھی جو دلجمعی سے لڑتی تھی۔ جنگ پلاسی میں سراج الدولہ کے مقابلے میں لارڈ کلائیو کی فوج مقامی لوگوں پر مشتمل تھی۔
اس کے ساتھ ایک اور بڑی وجہ جس کی وجہ سے مغلیہ سلطنت دفاعی لحاظ سے کمزور ہوئی کہ انہوں نے اپنی نیوی کو مضبوط نہیں کیا۔ جبکہ انگریزوں کی آمد کا زور اپنی مضبوط نیوی کے زور پر تھا۔
انگریزوں کے پاس مالی استحکام کے ساتھ ہتھیاروں کا معیار بھی مغلوں سے بہتر تھا۔ اس لیے بھی ان کو ہندی افواج پر برتری حاصل تھی۔ جنگ پلاسی میں تو سراج الدولہ کو غداری کا سامنا کرنا پڑا مگر جنگ بکسر میں اودھ اور مرشد آباد کے نواب کی مشترکہ فوج کو شکست ہوئی۔
مسلم زوال میں ایک بڑا کردار وہاں کے بنیوں جن کو بینکوں سے تشبیہ دی ہے۔ وہ زمینی محصولات جمع کرکے اس کو کچھ سود رکھ کر مقامی حاکموں کو دیتے تھے۔ انہوں نے اورنگزیب اور فرخ سیر کو قرضے دینے سے انکار کردیا جبکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو انہوں نے قرضے دئیے۔ اس طرح بھی مغل اقتدار زوال کی جانب بڑھا۔
ڈاکٹر کاظمی صاحب نے اکبر اور اورنگزیب کے بارے میں الگ سے بات کی ہے اور اس تاثر کی نفی کی ہے جو بالعموم پایا جاتا ہے کہ جس میں اکبر کو روادار اور اورنگزیب کو متعصب بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ اکبر نے چتور فتح کیا تو اس کو اسلام کی ہندؤ مت سے فتح قرار دیا، ایک موقع پر اکبر نے بھی بت توڑے جبکہ اورنگزیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جزیہ دوبارہ نافذ کیا جبکہ اس سے پہلے اکبر بھی یہ کام کر چکا تھا۔ اورنگزیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے باجپور اور گولکنڈہ کو اس لیے فتح کیا کیونکہ یہاں کے حاکم شیعہ تھے جبکہ اس کی اپنی فوج میں بڑی تعداد میں شیعہ کی موجود تھے۔ خود اورنگزیب نے ایک موقع پر کہا کہ امور دنیا کے ساتھ مذہب کا کیا تعلق ہے۔
اس باب میں نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے سے مرہٹوں کا اقتدار ختم ہو گیا اس سے امید تو بن گئی کہ شاید مسلم اقتدار کو سہارا ملے مگر انگریز اس سے پہلے ہی پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کو شکست دیکر اپنے قدم جما چکے تھے۔ لہذا یہ مسلم اقتدار کے خاتمے کو نہ روک سکا۔
دوسرے حصے میں مسلمانوں کی اندر احیاء کی تحریکوں کی تاریخ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس حصے میں چھے ابواب ہیں۔ جس میں شاہ ولی اللہ ، تحریک مجاہدین ، تیتو میر ، فرائضی تحریک ، جنگ آزادی کے واقعات اور پھر علمی تحریکوں کا ذکر ہے۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے میں ڈاکٹر کاظمی نے بتایا کہ وہ برصغیر کے علماء کے طبقے میں پہلے شخص تھے جنہوں نے مسلمانوں کے زوال پر غور کیا اور اس کا حل پیش کیا۔ شاہ ولی اللہ نے دولت کی مساوی تقسیم پر بات کی۔ انہوں نے کہا معاشرے کی فلاح اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس غیر مساوی تقسیم کا خاتمہ نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے شاہ صاحب کی تصانیف ازالتہ الخفاء اور حجتہ البالغہ کا ذکر کیا ہے۔
تحریک مجاہدین کے بارے میں بھی باب ہے۔ یہ تحریک عرب کی وہابی تحریک سے متاثر تھی۔ یہ سکھ سلطنت سے ٹکرائے مگر کامیاب نہ ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ناکامی کے باوجود اس تحریک کے اثرات آج تک قائم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ بات درست ہے اس تحریک کے نظری اور فکری عقائد کے ساتھ اس کا نظریہ جہاد آج بھی زندہ ہے اور موضوع بحث ہے۔
تیتو میر اور فرائضی تحریک بنگال میں چلنے والی دو تحریکیں تھیں جنہوں نے مزاحمت کا نیا روپ اختیار کیا۔ان دونوں تحریکوں کا ہدف غاصب اور قابض جاگردار اور ساتھ ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی تھی۔ ان دونوں نے مسلمانوں کے اندر بھی اصلاح کی آواز اٹھائی۔ دونوں تحریکیں تحریک مجاہدین سے متاثر تھیں لیکن تیتو میر کا زیادہ تر ہدف معاشی غارتگر تھے جبکہ فرائضی تحریک کے حاجی شریعت اللہ مسلمانوں کے ہاں رسومات بدعت کے مخالف تو تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ تقلید میں فقہ حنفی کے پیروکار تھے۔ ڈاکٹر کاظمی نے ان دونوں تحریکوں پر الگ الگ باب میں روشنی ڈالی ہے۔ اس میں تیتو میر کی مزاحمت اور جدوجہد کے بارے میں کافی مفید معلومات مل سکتی ہیں۔فرائضی تحریک کا بھی اچھا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ حاجی شریعت اللہ اور دودھو میاں نے جو خلافت کے احیاء کی کوشش کی اور برطانوی کچہریوں کا بائیکاٹ کرکے پنچائیت کے نظام کو مستحکم کرنے کی کوشش کی اور پھر نسلی امتیاز کے خلاف بھی انہوں نے آواز اٹھائی ۔ یہ اس کے مثبت پہلو ہیں گو کہ ان کے نتائج زیادہ دور رس نہ ثابت ہو سکے اور انگریزی اقتدار کو نہ روکا جا سکا۔
ایک اور باب ۱۸۵۷ کی جنگ آزادی کے واقعات کے بارے میں ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ ہندی افواج میں نظم و ضبط کا فقدان تھا۔ ان کے آپس کے درمیان روابط بھی نہیں قائم تھے۔ پھر پنجاب اور دکن میں بغاوت تو نہ ہوئی مگر جنگ میں انہوں نے شامل ہونے کی کوشش کی۔ موجودہ خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں بھی کوشش ہوئی۔ پھر جنگ لڑنے والی ہندی افواج کی جانب سے کئی جگہ انگریزوں کی عورتوں اور بچوں تک کو نشانہ بنایا گیا۔ لہذا مظالم کی داستان صرف انگریزوں نے نہیں بلکہ ہندی افواج نے بھی رقم کی۔ مصنف نے بتایا کہ جنگ آزادی میں شرکت ہندوؤں اور مسلمان دونوں نے کی مگر برطانوی حکام کے جبر کا نشانہ صرف مسلمان بنے کیونکہ اقتدار ان سے ہی انگریزوں نے چھینا تھا۔ ہندوؤں کی حیثیت تبدیل نہیں ہوئی ان کے فقط حاکم تبدیل ہوئے تھے۔
جنگ آزادی کے اسباب میں بڑا سبب اس بغاوت کا ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقامی آبادی کا معاشی استحصال تھا۔ جیسے کہ روہیل کھنڈ ، اودھ اور بہار کے عام لوگ ظالمانہ زرعی ٹیکس کے خلاف جنگ میں شامل ہوئے ۔
اس غدر یا جنگ آزادی کا بڑا اثر یہ ہوا کہ برصغیر ایسٹ انڈیا کمپنی کی بجائے براہ راست تاج برطانیہ کے زیر انتظام آ گیا۔ تاج برطانیہ کو بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے مظالم کی خبر ہوئی جس کی وجہ سے مقامی آبادی نے ہتھیار اٹھائے۔ ایک اہم بات کے مسلمان اور ہندؤ تو یہ جنگ ملکر لڑ رہے تھے مگر مرہٹوں اور سکھوں نے اس جنگ میں انگریزوں کا ساتھ دیا۔۔اس کے ساتھ نظام دکن کی افواج بھی انگریزوں کے ہم نوا تھیں۔
اس جنگ آزادی کا اہم کردار اودھ کی ملکہ حضرت محل کی انگریزوں کے خلاف مزاحمت کے بارے میں اور افتخار النساء حضرت محل کی شخصیت کے حوالے سے الگ مضمون بھی لکھا ہے جو کہ پڑھنے والے کی معلومات میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔
۱۸۵۷ کی شکست کے بعد مسلمانوں میں بالعموم طور پر یہ احساس پیدا ہوا کہ اب اسلحے کی طاقت سے انگریزوں کا مقابلہ ممکن نہیں۔ مسلمانوں نے کئی تعلیمی ادارے قائم کیے جس کا ذکر دوسرے حصے کے آخری باب میں ہے۔ اس میں ڈاکٹر کاظمی صاحب نے علی گڑھ ، دارلعلوم دیوبند ، منظر اسلام بریلی ، ندوۃ العلماء ، انجمن حمایت اسلام ، سندھ مدرستہ الاسلام اور اسلامیہ کالج پشاور کا ذکر کیا ہے۔ اس میں علی گڑھ دنیاوی تعلیم کا مرکز تھا جہاں پر جدید علوم کی طرف توجہ دی، جبکہ دیوبند اور بریلی مذہبی تعلیم کے مراکز تھے۔ ندوہ بنیادی طور پر مذہبی تعلیم کا مرکز تھا مگر اس میں بڑی تبدیلی تب آئی جب مولانا شبلی نعمانی یہاں آئے اور اس کے نصاب میں کچھ تبدیلیاں کیں۔ انجمن حمایت اسلام نے عیسائی مشنریوں اور آریا سماج کی جانب سے درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کیا۔ اس کے ساتھ اس نے سماجی ومعاشی بہبود میں اپنا کردار ادا کیا۔ سندھ مدرستہ الاسلام کے بانی حسن علی آفندی کے جذبات کے سرسید بھی معترف تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہاں سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اسلامیہ کالج پشاور نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔
سرسید احمد خان جنہوں نے علی گڑھ کی بنیاد رکھیکے سامنے پہلے ہندوؤں میں راجہ رام موہن رائے کی نظیر موجود تھی جنہوں نے ہندوؤں میں تعلیم کا جذبہ پیدا کیا۔ سرسید نے وہ ہی کچھ محسوس کیا جو راجہ رام موہن رائے پہلے محسوس کر چکے تھے۔
دارالعلوم دیوبند پر تحریک مجاہدین کا اثر تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مذہبی طبقے میں مولانا احمد رضا خان بریلوی پہلے شخص تھے جنہوں نے دو قومی نظریے پر کھل کر لکھا۔ سرسید احمد خان پہلے ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے مگر ۱۸۶۷ میں ہونے والے ہندی اُردو تنازعہ سے ان کی سوچ میں تبدیلی آئی اور وہ کھل کر دو قومی نظریہ کی بات کرنے لگے۔
تیسرے حصے میں برطانوی راج میں ہونے والی سیاسی جدوجہد کا ذکر ہےجس میں نو ابواب ہیں۔ اس میں ۱۸۵۷ کے بعد سے لیکر ۱۹۳۷ کی کانگریسی وزارتوں تک کے زمانے تک کے اہم واقعات جیسے کہ مسلم لیگ کا قیام ، تقسیم بنگال ، معاہدہ لکھنؤ ، تحریک خلافت ، دہلی مسلم تجاویز ، اقبال کا خطبہ الہ آباد ، گول میز کانفرنس اور ۱۹۳۵ کے قانون کے تحت ہونے والے انتخابات اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی کانگریسی وزارت کو الگ الگ ابواب میں ذکر کیا ہے۔
ان ابواب میں جو چیز سب سے زیادہ موضوع بحث ہے وہ ہندو مسلم کے بنتے بگڑتے تعلقات اور پھر اس کے نتیجے میں ہونے والی بڑی تبدیلیاں کیسے رونما ہوئیں۔ مسلم لیگ جو شروع میں انگریز حکومت کی وفادار تھی کانگریس کے مقابلے میں اتنی منظم جماعت نہیں تھی۔ حتی کہ ۱۹۳۷ کے انتخابات میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ امراء کی اس جماعت میں عام آدمی کی شرکت اور دلچسپی کم تھی گوکہ یہ مسلمانوں کے مفادات کی نمائندہ جماعت تصور کی جاتی تھی مگر اس کا ڈھانچہ اتنا فعال نہیں تھا۔
ہندؤ اور مسلمان برصغیر میں صدیوں سے رہ رہے تھے۔ مسلمانوں نے حکومت تو کی مگر ہندوؤں کی اکثریت کو نہیں بدلا۔ پھر جب انگریز آئے تو ان دونوں نے ملکر ان کا مقابلہ بھی کیا جس میں یہ ناکام رہے۔ انگریزی اقتدار کو ان دونوں کی تقسیم فائدہ دیتی تھی۔ گوکہ انگریز حکومت ایک سیکولر حکومت تھی اس نے اپنے مذہب کو پھیلانے میں سختی نہیں کی لیکن اس کے دور میں عیسائی مشنریوں نے یہاں پر زیادہ دھڑلے سے اپنے مذہب کی تبلیغ کی۔ مسلمان اور ہندؤ اتنے عرصے ساتھ رہنے کے باوجود مذہبی لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ اس میں مذہب کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی عوامل تھے جس میں یہ الگ الگ تھے۔ ان میں ایک زبان تھی۔ اُردو کو بالعموم مسلمانوں کی زبان باور کرایا گیا حالانکہ کئی ہندؤ ادیب اور شعراء اُردو لکھنے والے تھے۔ اردو مسلمانوں کی کوئی مذہبی زبان نہیں تھی بلکہ مسلمانوں میں کئی عرصے تک فارسی رائج رہی۔ اُردو کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین لسانی خلیج کم ہو گی۔ مگر انگریزوں نے یہاں پر بہت چالاکی سے اردو کو مسلمانوں اور ہندی کو ہندوؤں کی زبان قرار دیتے ہوئے ہندی زبان کی سرپرستی کی۔ جس سے ہندی اُردو تنازعہ نے جنم لیا اور اس کی بنیاد پر ہندو مسلم فسادات بھی ہوئے۔ اس ہندی اُردو تنازعہ سے سرسید احمد خان جیسے آدمی بھی یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کا چلنا ممکن نہیں ہے۔
۱۹۰۵ میں لارڈ کرزن نے بنگال کو تقسیم کیا تو اس پر بھی ہندؤوں اور مسلمانوں کا ردعمل الگ تھا۔ ہندوؤں کے شدید احتجاج کے بعد کچھ سالوں بعد ہی حکومت برطانیہ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور اس تقسیم کو ختم کرنا پڑا۔ ہندوؤں کا یہ احتجاج ہی بعد میں مسلم لیگ کے قیام کا محرک بنا۔ مسلم لیگ جو ابتداء میں امراء کی جماعت تھی اس کا جب کانگریس کے ساتھ معاملات ہوئے تو اس میں متعدد نشیب و فراز آئے۔ اس سے مسلم لیگ کی اپنی جماعتی حیثیت میں بھی تبدیلی آتی گئی۔ وہ جماعت جو امراء کی جماعت تھی بعد میں مسلمانانِ ہند کی سب سے توانا آواز بھی بنی مگر اس کے لیے اس کو بھی بہت سے مراحل سے گزرنا پڑا۔
کانگریس مسلم لیگ سے ناصرف عمر میں بڑی تھی اس کے ساتھ ساتھ یہ فعال بھی تھی۔ اس کا برصغیر میں تقریباً ہر جگہ وجود تھا۔ کانگریس نے کبھی خود کو ہندؤ جماعت نہیں کہا۔ اس نے بظاہر اپنے آپ کو برصغیر کے سب باشندوں کی جماعت کہا جس میں ہر مذہب کے لوگ موجود تھے۔ ڈاکٹر کاظمی کہتے ہیں کہ کانگریس میں گوپال کرشن گوکھلے کا جب تک زور تھا کانگریس نسبتاً معتدل جماعت تھی۔ گوکھلے کے مرنے کے بعد کانگریس کی قیادت سخت گیر موقف رکھنے والے لوگوں کے پاس جاتی گئی۔
گوکھلے کے علاوہ موتی لعل نہرو کی شخصیت بھی ہندؤ مسلم مسائل کے حوالے سے دانشمندانہ سوچ رکھتی تھی۔ جناح بھی گوکھلے اور موتی لعل نہرو کی بہت قدر کرتے تھے۔ ان دونوں رہنماؤں کے بعد ہندؤ مسلم قیادت میں اعتماد کا فقدان جو پہلے بھی موجود تھا وہ مزید بڑھ گیا۔ڈاکٹر کاظمی نے گوپال کرشنا گوکھلے کا شخصی تعارف بھی پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے لئے ہندوؤں پر ذمہ داری ڈالتے کیونکہ ہندو مسلمانوں سے تعداد کے ساتھ ساتھ تعلیم اور دولت میں آگے تھے لہذا یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر سے خوف کو ختم کریں۔
لکھنؤ معاہدہ میں مسلم لیگ اور کانگریس نے ملکر اور بعد میں تحریک خلافت میں ہندؤوں اور مسلمانوں نے ملکر انگریزی اقتدار کے خلاف ایک مہم شروع کی۔ معاہدہ لکھنؤ پر جناح کو مسلمانوں کی جانب سے بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا مگر اس وقت جناح ہندؤ مسلم اتحاد کے داعی تھے۔ تحریک خلافت میں بھی وہ الگ رہے جبکہ گاندھی اس کے پرجوش حمایتی تھے۔ جناح نے گاندھی کو اس دوران اس خطرے سے آگاہ کیا کہ ان کے طرز سیاست سے مذہبی جذبات کو بڑھاوا مل رہا ہے جس کے بعد میں منفی اثرات مرتب ہوں گے مگر گاندھی نہیں مانے۔جناح حکومت انگشیہ کے خلاف عدم تعاون پر بھی یقین رکھتے تھے مگر وہ معاملات کو اس حد تک نہیں لیکر جانا چاہتے تھے جہاں سے واپسی سے آزادی کے راستے مسدود ہوں۔ وہ عملی اقدامات پر یقین رکھتے تھے جبکہ گاندھی اس حوالے سے جذباتی اقدامات بھی اٹھانے سے گریز کرتے تھے۔ جناح اور گاندھی کی اس اپروچ میں فرق کو آگے بھی محسوس کیا جا سکتا ہے اور بعد میں اس سے دونوں جماعتوں کے راستے اور منزل بھی الگ الگ ہوتے گئے۔ گاندھی جس پرجوش انداز سے اس تحریک میں شامل ہوئے پھر چوری چورہ کے واقعے کے بعد اچانک سے الگ ہو گئے دوسری طرف ترکی میں بھی بڑی تبدیلی آنے سے یہ تحریک بے نتیجہ ختم ہو گئی۔
دہلی مسلم تجاویز پھر سائمن کمیشن کی آمد ، نہرو رپورٹ اور اس کے بعد جناح کے چودہ نکات پر بھی مصنف نے بات کی ہے۔
اس کے بعد خطبہ الہ آباد پر بات کرنے کے ساتھ ایک الگ مضمون میں اقبال کے تصور خودی کی بھی وضاحت کی ہے اور بتایا ہے کہ اقبال انسان کی آزادی فکر اور اس کی بے پناہ صلاحیت کی کھوج کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔
اقبال کے خطبہ الہ آباد سے پاکستان کے تصور کو نتھی کیا جاتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس وقت اقبال کے ذہن میں الگ ریاست کا تصور نہیں تھا۔اور نہ ہی اس وقت یہ عملی طور پر ممکن تھا۔ البتہ چوہدری رحمت علی نے الگ ریاست کی بات شروع کی۔ ڈاکٹر کاظمی کہتے ہیں کہ اس وقت چوہدری رحمت علی کی بات حقیقت سے دور ایک جذباتی بات تھی مگر انہیں چوہدری رحمت علی کے خلوص پر کوئی شک نہیں۔ اقبال خود بعد میں الگ وفاق کے قائل ہو گئے تھے اس بارے میں ۱۹۳۷ میں جناح کے نام لکھے خط کو ڈاکٹر کاظمی صاحب نے ذکر کیا ہے
ایک باب ۱۹۳۷ کے انتخابات کے بارے میں بھی ہے۔ اس میں مسلم لیگ کی شکست کی وجوہات پر بات کرتے ہوئے لکھا کہ خلافت تحریک کی ناکامی کے زخم ابھی تک بھرے نہیں تھے۔ اس کے ساتھ اُمیدواروں کے چناؤ میں بھی کئی غلط فیصلوں کا خواجہ ناظم الدین نے بھی اعتراف کیا۔اس کے علاوہ پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ بھی کوئی فعال نہیں تھا حتی لیاقت علی خان جو کہ اس کے سکریٹری تھے نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دیکر آزاد حیثیت میں انتخاب لڑا۔
مسلم لیگ اس امید میں تھی کہ کانگریس ان کے ساتھ اتحاد کرکے حکومت بنائے گی کیونکہ مسلم لیگ کو برطانوی حکام کی جانب سے کچھ آفرز ہوئیں کہ وہ اقلیتی جماعتوں سے ملکر حکومت تشکیل دے مگر مسلم لیگ نے انکار کر دیا کیونکہ کانگریس اکثریت میں تھی۔ لیکن حکومت ملنے کے بعد کانگریس نے لیگ کو حکومت میں شامل نہیں کیا۔ اس سے لیگ کو دھچکا لگا۔
کانگریس کے اقتدار میں مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا۔ اس سے بڑی تبدیلی مسلم کمیونٹی میں آئی کیونکہ ۱۹۳۷ کے انتخابات میں مسلمانوں کی اکثریت نے لیگ کا ساتھ نہیں دیا مگر کانگریسی وزارتوں میں ان کے ساتھ ہونے والے سلوک نے ان کی ہمدردیاں لیگ سے جوڑ دیں۔
کانگریسی وزارتوں میں ہوئے مظالم کے بارے میں کانگریس کے حامی لکھاریوں کا دعویٰ ہے کہ یہ بے بنیاد الزام ہے، اس پر ڈاکٹر کاظمی نے بتایا کہ جناح اور لیاقت علی خان کے درمیان خط و کتابت جو بعد میں شائع ہوئی اس میں یہ واضح طور پر ملتا ہے کہ شروع میں دونوں رہنما کانگریس کو مورد الزام ٹھہرانے میں محتاط تھے مگر جب ان تک واضح ثبوت پہنچے تو تب انہوں نے یہ بات کی۔
کانگریس کا یہ وازرتی دور بعد میں ہونے والی بڑی تبدیلی کا ایک محرک بنا۔ اب مسلمانوں کو احساس ہو گیا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد وہ متحدہ ہندوستان میں کانگریس کے رحم و کرم پر ہوں گے لہٰذا ان کی نجات متحدہ ہندوستان میں نہیں بلکہ منقسم ہندوستان میں ہے۔ ممکن ہے کہ لیگ یا ان کے حامیوں کے ہاں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہو مگر کانگریسی وزارتوں نے اپنے عمل سے اس تاثر کو تقویت دی کہ وہ مکمل طور پر ہندوؤں کے مفادات کی حفاظت کرنے والی جماعت ہے جس میں مسلمانوں کے حقوق کی کوئی اہمیت نہیں۔
چوتھا حصے تحریک پاکستان کے اوپر ہے جس میں پانچ ابواب ہیں۔
ان ابواب میں ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کے بننے اور تقسیم ہند کے حق میں دلائل دئیے ہیں اور بتایا ہے کہ یہ کانگریس کی قیادت کی ہٹ دھرمی تھی جس کی وجہ مسلم لیگ اور مسلمان اس فیصلے پر مجبور ہوئے۔ مسلم لیگ نے کانگریسی قیادت سے تعاون کی بھرپور کوشش کی تاکہ مستقبل میں آگے ملکر چلا جا سکے مگر کانگریسی قیادت کا غرور اور مسلم مسئلہ کو سنجیدہ نہ لینے کے سبب مسلمان اور مسلم لیگ مجبور ہوئے اور انہوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ اس حصے میں ۱۹۴۰ سے لیکر ۱۹۴۷ تک دورانیہ میں ہونے والے اہم واقعات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس دورانیے میں حکومت انگشیہ نے ہندوستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔۔ ان کے جانے کے بعد ہندوستان کا جغرافیہ کیا ہوگا اس پر مسلم لیگ اور کانگریس کے آپس میں حکومت انگشیہ کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اور ان میں اتار چڑھاؤ آیا ان سب کو اس حصے میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
۱۹۳۷ کے انتخابات کے بعد والی مسلم لیگ ایک بدلی ہوئی مسلم لیگ تھی جس نے ۳۷ کے انتخابات میں ۴۸۹ میں سے ۱۰۴ نشستیں حاصل کیں تھیں۔ ۳۷ سے ۴۲ کے دوران ہونے والے ضمنی انتخابات میں لیگ نے ۵۶ میں سے ۴۶ نشستیں حاصل کیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لیگ نے اپنی پالیسی کو۔تبدیل کیا تو وہ بھی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بن کر سامنے آئی۔
ڈاکٹر کاظمی صاحب نے بتایا ہے کہ ۱۹۴۰ کی قرارداد لاہور سے پہلے بھی کچھ مسلم رہنما و مفکرین نے الگ مسلم زون بنانے کی تجویز پیش کی اس میں علی گڑھ یونیورسٹی سے پروفیسر ظفر الحسن اور افضل قادری کا نام ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی سندھ سے سر عبداللہ ہارون نے دو وفاق کی بات کی۔
پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا اور جناح نے تقسیم سے قبل اس کا بھرپور مقدمہ بھی لڑا مگر تقسیم کے بعد انہوں نے کہا کہ ریاست کو شہریوں کے مذہب سے کوئی سروکار نہیں ۔ جناح کے ناقدین ان دونوں باتوں کو جناح کا تضاد قرار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کاظمی نے اس حوالے سے وضاحت کی اور جناح کے موقف کو درست قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ دونوں باتیں مختلف ماحول اور پس منظر میں کی گئی ہیں۔ برٹش انڈیا میں مسلمانوں کو ہندؤ اکثریت سے تحفظات تھے جبکہ پاکستان میں مسلمان اکثریت میں تھے تو اقلیتوں کے تحفظ اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے یہ ضروری تھا کہ ریاستی سطح پر اعلان کیا جائے کہ مسلمان اکثریت ریاستی طاقت سے ان کو ان کی مذہبی عبادات سے نہیں روک سکتے۔ قائد اعظم کا یہ پیغام ریاست کی جانب سے اعلان تھا کہ ان کے مذہبی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔
اس دورانیے میں مسلم لیگ، کانگریس اور انگریزوں کے درمیان مذاکرات کے کئی مراحل پیش آئے جس میں ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا۔ اس سب کی روداد مصنف نے ذکر کی ہے۔ ایک اہم بات کہ تقسیم کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بھی کانگریس کی قیادت کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی نمائندگی اور ان تحفظات کے بارے میں کبھی سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا۔۔ جناح اور مسلم لیگ نے تو کابینہ مشن پلان کو منظور کر کے بھی متحدہ ہندوستان کو ایک موقع دیا جس پر خود کانگریسی رہنما مولانا ابوالکلام آزاد کی گواہی ڈاکٹر صاحب نے نقل کی جواہر لعل نہرو کے بیان نے اس کوشش کو سبوتاژ کر دیا۔
یہ سوال کہ آخر کار کانگریس تقسیم پر کیوں راضی ہو گئی اس کی کیا وجہ تھی تو اس پر ڈاکٹر کاظمی صاحب کا تجزیہ یہ ہی ہے کہ کانگریسی قیادت پورے یقین سے یہ سمجھتی تھی کہ پاکستان کا منصوبہ ناقابلِ عمل ہے۔ بہت جلد ہی پاکستان دوبارہ متحدہ ہندوستان کا حصہ بن جائے گا۔ اس ہی سوچ کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے کابینہ مشن پلان کو مسترد کیا۔ بعد میں اثاثوں کی تقسیم ہو یا پھر سرحدی تنازعات یہ سب چیزیں اس خیال کو تقویت دیتی ہیں کہ کانگریسی قیادت یہ امید رکھتی تھی کہ پاکستان کا منصوبہ جلد ناکام ہو جائے گا۔ پاکستان جب وجود میں آیا تو جس طرح اس کے پاس وسائل کی کمی تھی تو کانگریسی قیادت کا خیال کچھ غلط بھی معلوم نہیں ہوتا۔۔ پاکستان کو ابتداء میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کا مصنف نے اگلے حصے میں ذکر کیا ہے حتی کہ دفتری امور کو سرانجام دینے کے لیے ان کے پاس فرنیچر اور سٹیشنری کی بھی کمی تھی۔
تقسیم کے حوالے سے ریڈ کلف اور ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کے ساتھ زیادتیاں کیں اور کئی مسلم اکثریتی علاقوں کو بھارت میں شامل کیا اور پھر انگریز نے کشمیر کے مسئلہ کو حل کیے بغیر یہاں بھی ہندوستان کو مدد فراہم کی۔ اس سب کو ذکر کیا گیا ہے۔ بھارت کو کشمیر تک رسائی دینے کے کانگریس کے مطالبے سے بھی کانگریس کی ذہنیت واضح ہوتی ہے کہ وہ ناصرف پاکستان کو ناقابل عمل منصوبہ سمجھتے تھے بلکہ اس کو ناقابل عمل ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری کوشش بھی کی۔
اثاثوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی پاکستان کے ساتھ ناانصافی کی گئی حتی کہ گاندھی کو بھی اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج کرنا پڑا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ گاندھی کی بھوک ہڑتال کی وجہ سے پاکستان کو کچھ رقم ملی مگر پھر بھی بڑا حصہ نہیں دیا گیا۔
پانچویں حصے میں آٹھ ابواب ہیں جس میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کو ابتداء سے لیکر ۲۰۰۷ تک ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ریاست اور حکومت کے بارے میں کچھ بنیادی تصورات کی وضاحت کی گئی ہے اور ساتھ ہی نظریہ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں دو قومی نظریہ ایک اضافی اصطلاح تھی جو کہ غیر منقسم ہندوستان میں تو relevant تھی مگر تقسیم کے بعد یہ relevant نہیں رہی۔۔
پاکستان کی تخلیق میں اسلام کے کردار پر بھی مصنف نے بحث کی ہے اور کہا کہ اس حوالے سے مسلم لیگ اور جماعت اسلامی کی سوچ میں فرق ہے۔ خود لیگ کے اندر کی قیادت میں بھی اس بارے میں مختلف آراء پائی جاتی تھیں مگر اسلام کے سماجی بہبود کے تصور پر وہ متفق تھے۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے دعویٰ کیا کہ قائد اعظم اور قائد ملت سمیت لیگ کی قیادت اسلامی سوشلزم کے بارے میں بھی متفق تھی۔ پھر انہوں نے اسلامی سوشلزم کی وضاحت کی کہ جس میں غریبوں اور ناداروں کی مدد کی جاتی اور ان کے استحصال کی تمام کوششوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ اسلام نجی جائیداد کا مخالف نہیں مگر غریبوں کے استحصال کی اجازت نہیں دیتا۔ انسانی حقوق اور معاشرتی انصاف کے حوالے سے جو اسلام کی اقدار ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اسلامی سوشلزم کو نافذ کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال سے سوشلزم کی اصطلاح کو اسلام کے ساتھ نتھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کنفیوژن پیدا کرتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بانیان پاکستان کوئی مذہبی ریاست یا تھیوکریٹک سٹیٹ قائم نہیں کرنا چاہتے تھے۔۔ یہ بات بھی درست ہے۔ جہاں تک نفاذ اسلام کی بات ہے تو ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے بھی ایک درست بات لکھی کہ اسلامی قوانین کو کسی بھی معاشرے پر اگر selectively نافذ کیا جائے تو اس کے نتائج مثبت نہیں آتے۔ جیسے کہ ہم پاکستان میں دیکھ چکے ہیں۔۔ اسلامی قوانین کو مکمل طور پر جب تک نافذ نہیں کیا جاتا اس وقت تک وہ اپنے نتائج نہیں دے سکتے۔۔پاکستان میں جو اسلامائزیشن کی کوششیں ہوئیں ہیں ان میں صاحبان اقتدار کی نیت پر سوالیہ نشان ہیں۔جیسے کہ جنرل ضیاء الحق نے حدودِ قوانین کا تو اجراء کر دیا مگر قتل کے جرم کے لیے اسلامی قوانین کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی کیونکہ اگر اس پر عمل کیا جاتا تو بھٹو کو پھانسی دینا ممکن نہ ہو پاتا۔ پھر جو ہمارے ہاں ایسی کوششیں ہوئیں ان کے منفی نتائج میں سے ایک بڑا نتیجہ ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی کی صورت میں نکلا۔
پانچویں حصے کے پہلے باب میں تقسیم کے وقت کی مشکلات جیسے کہ ہندؤ مسلم فسادات ، اثاثوں کی تقسیم ، کشمیر کا مسئلہ اور پانی کے مسائل پر بات کی ہے۔ اس کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کے دور کو بھی اس باب میں ذکر کیا ہے۔
ڈاکٹر کاظمی کہتے ہیں کہ لیگ نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان کا گورنر جنرل نہیں بننے دیا یہ درست فیصلہ تھا۔ ماؤنٹ بیٹن کا بھی خیال تھا کہ پاکستان جلد ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا لیگ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو گورنر جنرل بنا دیا ساتھ ہی گورنر جنرل کے لیے اختیارات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ یہ قائد اعظم یا پھر خواجہ ناظم الدین کی حد تک ٹھیک تھا مگر بعد میں اس کے بہت منفی نتائج مرتب ہوئے۔
جناح سب ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے حق میں تھے۔حالانکہ سویت وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان بننے پر کوئی مبارکباد کا پیغام نہیں پہنچایا مگر اس کے خلاف جناح مغرب کی کسی صف بندی میں شامل ہونے کے حق میں نہیں تھے۔ جناح نے فلسطین کاز کی حمایت کی اور انڈونیشیا کی آزادی کی بھی حمایت کی۔
لیاقت علی خان کے دور میں صنعتی ترقی کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہوئی۔ روپے کی قدر کم نہ کرنے پر ان کو بھارت کی طرف سے معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مگر کوریا کی جنگ کی وجہ سے ان کا مداوا ہو گیا۔ قائد ملت کے دور میں مرکز اور صوبوں کے درمیان کشمکش بڑھی اور ان کے دور میں آئین سازی کا کام مکمل نہ ہو سکا جس کو ان کی ناکامی کہا جا سکتا ہے۔
۱۹۵۱ تا ۱۹۵۸ تک پاکستان میں وزراء اعظم بدلتے رہے۔ اس پورے عرصے کو ایک باب میں ذکر کیا اور ہر وزیر اعظم کے دور میں ہوئے ایک دو واقعات کو ذکر کیا ہے۔ جیسے کہ خواجہ غریب ناظم الدین کے زمانے میں ملک کو غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد علی بوگرہ نے گورنر جنرل کے اختیارات کم کرنے کی کوشش کی مگر عوامی حمایت نہ ہونے کے باعث وہ کامیاب نہ ہوسکے۔ چوہدری محمد علی نے آئین سازی میں اہم کردار ادا کیا۔ جبکہ حسین شہید سہروردی ان سب وزراء اعظم میں بطور لیڈر جانے جاتے تھے جو کہ منجھے ہوئے سیاست دان بھی تھے۔ تقسیم سے پہلے وہ بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے۔ انہوں نے اس وقت کے قائد حزب اختلاف کرن شنکر رائے اور بنگالی سیاست دان سرت بوس کے ساتھ ملکر متحدہ بنگال کو الگ ملک بنانے کی تجویز پیش کی تھی جس کو جناح اور گاندھی نے بھی تسلیم کیا مگر نہرو اس پر راضی نہ ہوئے۔ تقسیم کے بعد وہ فوراً پاکستان نہیں آئے۔ سہروردی مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان ایک پل تھے جو ان دونوں بازوؤں کو جوڑے رکھ سکتے تھے۔ ان کا وزارت اعظمی کا دور کوئی اتنا کامیاب نہیں رہا سویز نہر والے مسئلہ پر انہوں نے عربوں کی مخالفت مول لی جب انہوں نے مسلم ممالک کو صفر سے تشبیہ دی۔ ابراہیم اسمعیل چندریگر بہت کم عرصے کے لیے وزیر اعظم بنے جبکہ فیروز خان نون کا سیاسی پس منظر کافی مضبوط تھا وہ پہلے مارشل لاء کے نتیجے میں وزارت اعظمی سے محروم ہوئے۔
اس دور میں جمہوریت کی ناکامی میں جہاں ملٹری اور بیوروکریسی ذمہ دار ہیں وہاں پر ڈاکٹر کاظمی نے سیاست دانوں کو بھی اس ناکامی کا ذمہ دار قرار دیا جنہوں نے بالغ نظری سے کام نہیں کیا۔ انہوں نے دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہوتا تو حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔
ایوبی مارشل لاء کے اوپر ایک باب ہے۔ گوکہ مارشل لاء کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا مگر اس مارشل لاء کا مشرقی پاکستان میں نتیجہ بھیانک نکلا۔ ایوب دور میں بی ڈی سسٹم جہاں پر بل واسطہ انتخابات کے ذریعے سربراہ مملکت کے چناؤ کی بنیاد رکھی گئی۔ ایوب کا مخالف سیاست دانوں پر پابندیاں لگانا۔ ایوب دور میں ہوئی معاشی ترقی کے بارے میں مصنف نے بتایا ہے کہ صنعتی حوالے سے تو اس کے کچھ مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ لیکن زرعی اصلاحات اپنے نتائج حاصل نہ کر سکیں۔ اس کی بڑی وجہ زمینداری نظام میں اصلاحات نہ ہونا ہے۔ گوکہ اس دور میں سبز انقلاب بھی آیا اور زراعت میں جدت بھی آئی لیکن نچلی سطح تک اس کے اثرات مرتب نہیں ہوئے۔
ایوب دور کا ایک بڑا واقعہ ۶۵ کی جنگ تھی۔ جس نے پاکستان کی سمت ہی تبدیل کر دی۔ یہ جنگ پاکستان کی جانب سے کیے گئے آپریشن کے بعد شروع ہوئی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کا خیال تھا کہ بھارتی رد عمل کشمیر تک محدود رہے گا مگر بھارت نے عالمی سرحد کی جانب سے حملہ کر دیا۔ یہ جنگ سترہ دن جاری رہی اور بے نتیجہ رہی۔ پاکستان کشمیر نہ لے سکا جبکہ بھارت لاہور پر قبضہ نہیں کر سکا۔ بھارت نے کیونکہ انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا تھا تو دنیا کے بیشتر ممالک کی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ تھیں۔ ملائیشیا کے سوا اکثر مسلم ممالک نے پاکستان کی حمایت میں بیان دئیے۔ برطانوی وزیر اعظم نے اس جنگ کی ذمہ داری بھارت پر ڈالی۔ برطانیہ کی یہ کوشش بھی تھی کہ پاکستان چین سے مدد نہ لے۔ چین نے پاکستان کی اخلاقی مدد کی اور بھارت کو خبردار کیا کہ اس کی سرحد کی خلاف ورزی نہ کی جائے جس کا بھارت نے پاس رکھا۔ یہ دراصل بلواسطہ طور پر پاکستان کی مدد تھی کہ بھارت پر چینی سرحدوں کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا۔امریکہ چینی ردعمل کے بارے میں کافی محتاط تھا کیونکہ چین کی مدد سے پاکستان جنگ کو طول دیکر بھارت کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا تھا۔
اس جنگ کے اختتام پر معاہدہ تاشقند ہوا۔ جس کے بعد بھٹو صاحب ایوب حکومت سے الگ ہوئے۔ اس جنگ سے پاکستان کی معاشی ترقی کا سفر رک گیا۔ اب ایوب خان پہلے جیسے طاقتور نہیں رہے تھے جس کو محسوس کرتے ہوئے ان کے خلاف تحریک چلی جس کے نتیجے میں ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔
یحیی خان کے اقتدار اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے حوالے سے بھی ایک باب ہے۔ جو باقی ابواب سے قدرے طویل ہے۔ اس میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر کاظمی صاحب نے کہا کہ شیخ مجیب الرحمٰن اور عوامی لیگ کے چھے نکات کی بنیاد پر آئین سازی نہیں ہو سکتی تھی۔ جس قانون کے تحت ۷۰ کے انتخابات ہوئے تھے اس کے مطابق بھی چھے نکات کی گنجائش نہیں تھی۔ لہٰذا بھٹو صاحب کا اس پر اعتراض قانونی لحاظ سے بھی درست تھا۔ بھٹو صاحب نے اس ہی معاملے پر شیخ مجیب الرحمٰن سے مذاکرات کیے جو کامیاب نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر کاظمی صاحب کی شیخ مجیب الرحمٰن کے بارے میں رائے کوئی زیادہ مثبت نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ شیخ مجیب علیحدگی کا ذہن بنا چکے تھے۔ پھر مشرقی پاکستان میں جو فوجی آپریشن ہوا وہ بھی عوامی لیگ کی جانب سے ہوئے تشدد کے ردعمل میں تھا۔ اس آپریشن میں کئی بے گناہ لوگ قتل ہوئے اس کا مصنف کو بھی اعتراف ہے۔ لیکن یہ مظالم دونوں جانب سے ہوئے۔ پاکستانی فوج کی جانب سے کئی بے گناہ بنگالیوں کا خون ہوا جس کا ذکر حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں بھی ہے تو دوسری طرف بہاریوں اور مغربی پاکستان کے باشندے جو مشرقی پاکستان میں مقیم تھے پر عوامی لیگ اور مکتی باہنی نے مظالم توڑے۔ عالمی سطح پر روس نے بھارت کا بھرپور ساتھ دیا اور سکیورٹی کونسل میں جنگ بندی کی سب کوششوں کو ویٹو کر دیا حتی کہ بھارت کی فتح یقینی ہو گئی۔ پاکستان نے مشرقی سرحد سے دباؤ کم کرنے کے لیے مغربی پاکستان سے حملہ کیا تو یہاں بھی ناکامی ہوئی۔ مشرقی پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کو کارگل سے بھی ہاتھ دھونے پڑے جو اس سے پہلے پاکستان کے پاس تھا۔
بھٹو صاحب کے دور پر ایک باب ہے جس میں صنعتوں کو قومیانے کی پالیسی پر بات کی گئی ہے۔ اس پالیسی نے ملکی معیشت پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ شروع میں بھٹو حکومت کا ہدف صنعتیں تھیں مگر بعد میں تعلیمی ادارے ، بینک اور انشورنس کمپنیوں کو بھی قومیا لیا گیا۔
ضیاء الحق کے دور میں ہونے والی افغان جنگ اور اس میں پاکستان کی شرکت کی وجہ جو معاشرتی تبدیلیاں آئیں ان کا ذکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے روسی جارحیت کے جواب میں پاکستانی ردعمل کو معقول کہا ہے اور بتایا ہے کہ جو سماجی تبدیلیاں افغان مہاجرین کی وجہ سے رونما ہوئیں وہ اس سے زیادہ بھیانک نتائج سامنے لاتیں اگر روس کے قدم گرم پانیوں تک جاتے۔ ضیاء الحق کی اسلامائزیشن پر بھی مصنف نے بات کی اور بتایا کہ اس میں ضیاء الحق نے فقط وہاں تک قدم اٹھایا جہاں تک ان کے مفادات تھے۔ جیسے کہ انہوں نے شرعی سزاؤں کا نفاذ کیا مگر قتل کے بارے میں شرعی قوانین کا پاس نہ رکھا کیونکہ اس سے بھٹو صاحب کو پھانسی دینا ممکن نہیں تھی۔ ضیاء الحق کی آمریت پر مغرب نے بھی آنکھیں بند کیے رکھیں کیونکہ یہ ان کے مفادات کا تحفظ کر رہے تھے۔ ضیاء الحق نے جمہوریت کی بحالی کے لیے بھی کچھ دکھلاوے کیے جیسے کہ ریفرنڈم اور بعد میں ۱۹۸۵ کے انتخابات ، جب خود ان کے لائے ہوئے وزیر اعظم محمد خان جونیجو نے آزاد روش اختیار کرنے کی کوشش کی تو ان کی حکومت کو چلتا کیا۔
بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کی دونوں حکومتیں جن کا دورانیہ گیارہ سال بنتا ہے ان کو ایک باب میں ذکر کیا ہے جس میں اس دور کے اہم واقعات میں سے چند کو ذکر کیا ہے۔ بینظیر بھٹو کے پہلے دور میں بتایا کہ ان کو ناپ تول کر فیصلہ سازی کا اختیار دیا گیا۔ جس کا بعد میں انہوں نے اعتراف بھی کیا۔ میاں صاحب کے پہلے دور میں عراق کے کویت پر حملے میں صدر اور آرمی چیف ایک طرف جبکہ وزیر اعظم دوسری طرف تھے۔ یہ میاں نواز شریف کا اچھا قدم تھا کہ انہوں نے اپنی پوزیشن کی اہمیت کو منوانے کے لیے اس کا مظاہرہ کیا۔ میاں صاحب کے پہلے دور میں سندھ میں حالات خراب ہوئے جس کی وجہ سے آپریشنز کرنے پڑے۔ محترمہ کے دوسرے دور حکومت پر بہت ہی مختصر بات کی ہے۔ اس دور میں متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف فوجی آپریشن اور پھر میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا ذکر ہے۔ ایسے ہی میاں صاحب کا دوسرے دور پر بھی زیادہ بات نہیں کی گئی۔اس دور میں کی گئی چودھویں اور پندرھویں ترمیم ، ایٹمی دھماکوں اور کارگل کی جھڑپ کا ذکر ہے جس کے بعد میاں صاحب اور فوجی قیادت میں اختلافات بڑھ گئے اور بعد میں آرمی چیف کے طیارے کو پاکستان نہ اترنے دینے پر پرویز مشرف نے میاں صاحب کی حکومت کو چلتا کیا۔
پرویز مشرف کے دور میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کے معاملے پر بات کی ہے اور بتایا کہ لیبیا کے اعتراف کے بعد پاکستان کافی مشکل میں آ گیا تھا۔ اس وقت پاکستان امریکی جنگ میں اتحادی تھا جس کا فائدہ اٹھا کر عالمی دباؤ کے سامنے پاکستان کے بچ نکلنے کا امکان پیدا ہوا۔ پرویز مشرف کے دور میں ہی افغانستان میں امریکہ نے حملہ کیا جس میں پاکستان امریکہ کا اتحادی بنا۔ اس دور میں بلوچستان میں ڈاکٹر شازیہ خالد کا افسوسناک واقعہ ہوا پھر اکبر بگٹی کو مارا گیا۔ عدلیہ کے محاذ پر بھی مسائل پیدا ہوئے جب اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن کو روکا گیا، چیف جسٹس افتخار چودھری کی معزولی اور پھر وکلاء تحریک ، اس دوران لال مسجد کا واقعہ اور پھر محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل یہ سب اس دور کے اہم واقعات ہیں۔
اس حصے میں مجموعی طور پر تو ڈاکٹر کاظمی صاحب نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کو ذکر کیا ہے مگر بیشتر جگہ پر انہوں نے فقط واقعات کو بیان کرنے پر اکتفاء کیا ہے۔ ان واقعات کے پیچھے وجوہات اور ان کا تجزیہ پیش نہیں کیا۔ پھر مشکوک ہاتھوں کا جو ہمیشہ سے کردار رہا ہے اس پر بھی زیادہ بات نہیں کی۔
پاکستان میں آئین سازی کی بھی ایک تاریخ ہے کیونکہ پہلا آئین آزادی کے نو سال بعد بنا جو دو سال چل سکا، دوسرا آئین بھی کم و بیش سات سال چلا اور تیسرا آئین بھی دو تین دفعہ معطل ہو چکا۔ کتاب کے چھٹے حصے میں آئین سازی کی تاریخ کو ذکر کیا گیا ہے کہ آئین سازی کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑا۔ اس میں کیا کیا رکاوٹیں آئیں اور پھر اس کے ساتھ بتدریج کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں۔ اس میں دو ابواب ہیں.
آئین سازی کے حوالے سے شروع میں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اس میں آئین کی نوعیت کے بارے میں کافی بحث ہوئی۔ مرکز اور صوبوں کے اختیارات ، پھر بنگالیوں کا مطالبہ کے بنگالی کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے ، انتخابات کی نوعیت کے وہ جُداگانہ ہوں یا مخلوط ہوں۔ بالخصوص ملک کے مشرقی بازو میں اس حوالے سے کافی بے چینی پائی جاتی تھی۔ یہ بنگالی زبان کے ساتھ ساتھ صوبے کے لیے زیادہ سے زیادہ اختیارات کے حوالے سے بھی مغربی بازو سے الگ سوچ رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ یہاں پر اقلیتی برادری کی تعداد مغربی بازو سے زیادہ تھی لہٰذا یہاں پر مخلوط انتخابات کا مطالبہ تھا جبکہ مغربی بازو جُداگانہ انتخابات کے حق میں تھا۔
ایک اور اہم موضوع آئین میں اسلام کا عمل دخل کتنا ہوگا اس بارے میں بھی حتمی رائے نہیں تھی۔ اس حوالے سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ مسلم لیگ اور جماعت اسلامی کا نظریہ اس حوالے سے مختلف تھا۔ خود قائد اعظم محمد علی جناح نے کسی مذہبی یا پاپائی ریاست کے امکان کو مسترد کر دیا تھا۔ دوسری طرف لیگی رہنماؤں کی جانب سے اسلامی اقدار کی روشنی میں آئین سازی کے بیانات موجود تھے۔ جبکہ ایسی سیاسی جماعتیں بھی موجود تھیں جو ریاستی امور میں مذہب کی مداخلت کی قائل نہ تھیں لہذا اس بارے میں بھی آئین سازی کا مرحلہ طول اختیار کر گیا۔
گورنر جنرل غلام محمد نے آئین ساز اسمبلی کو توڑ کر ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جو عمل پچھلے پانچ چھے سال سے چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ بعد میں اسکندر مرزا نے بھی غلام محمد کی روش اختیار کی اور حکومتوں کو ختم کیا۔ اس ساری کاروائی سے آئین سازی کا عمل اور ملک میں جمہوریت کے سفر کو نقصان پہنچا۔
پاکستان کے تینوں آئین کے بارے میں ڈاکٹر کاظمی صاحب نے لکھا ہے اور ان کی بنیادی خصوصیات پر بات کی ہے۔ ۱۹۷۳ کے آئین میں ہونے والی ترامیم کا بھی ذکر کیا ہے۔ جب یہ کتاب لکھی گئی تو اس وقت تک سترہ ترامیم ہو چکی تھیں ان سب کو ذکر کیا ہے۔
ساتواں حصہ اداروں کی تاریخ کے بارے میں ہے۔ جس میں دو ابواب ہیں ۔ پہلے میں بیوروکریسی اور دوسرے میں مسلح افواج کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ کتاب کے مختصر ترین حصوں میں سے ایک ہے۔ بیوروکریسی اور فوج برٹش انڈیا کی تقسیم کے بعد پاکستان کے حصے میں آئیں۔
برطانیہ نے ان دونوں اداروں کو نئے خطوط پر استوار کیا، بالخصوص فوج کو، انہوں نے نے منظم فوج کی بنیاد پر مغل سلطنت کو شکست دی۔ بعد میں برطانوی ہند کی فوج کا ڈھانچہ تشکیل دیا جہاں اس کی رجمنٹس بنائیں۔ برطانوی حکومت نے پہلے فوج کو منظم کرنے میں جان بوجھ کر مذہبی پسِ منظر کو نظر انداز کیا بعد میں اپنی ضرورت کے تحت فوج میں بھرتیاں نسل اور ذات پات کی بنیاد پر ہوئیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم میں برطانوی ہند کی فوج میں مسلمانوں کے ہونے کا مسلمانانِ ہند کو فائدہ ہوا۔ ان کی وجہ سے برطانوی حکومت کے مسلمانوں کی بابت رویے میں بہتری آئی۔
تقسیم ہند کے وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس نہیں چاہتے تھے کہ فوج کو تقسیم کیا جائے مگر جناح اور لیاقت علی خان نے انگریزوں پر واضح کیا کہ وہ پاکستان کو بغیر فوج کے قبول نہیں کریں گے اس لیے بادل ناخواستہ برطانوی ہند کی فوج کو تقسیم کیا گیا اور پاکستان کے حصے میں فوج آئی۔ ۱۹۷۱ میں آرمی کے سربراہ کو کمانڈر انچیف کہتے تھے بعد میں اس عہدے کو آرمی چیف کے عہدے سے بدل دیا گیا۔
یہاں مختصر طور پر مصنف نے سول ملٹری تعلقات کے بارے میں بھی بات کی ہے اور کہا ہے کہ اس عدم توازن کی وجوہات سویلینز کی اپنی نااہلی ، نالائقی اور حکام بالا کی بدعنوانیاں بھی شامل ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں فوج منظم ہے۔ اگر لوگوں کی تعلیم و تربیت پر کام کیا جائے تو اس خلا کو پر کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم و تربیت کی بات تو ٹھیک ہے مگر سول ملٹری تعلقات کے اس عدم توازن کو ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے کی رائے کمزور ہے۔ سول حکام میں کچھ لوگوں کی بدعنوانیوں سے انکار نہیں مگر وسائل کی جو غیر متوازن تقسیم ہے اور فیصلہ سازی میں جو فوج کا غیر آئینی کردار ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی جگہ خالی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بالفرض سول قیادت نااہل بھی ہو تو فوج کو اس میدان میں دخل دینے کی کوئی آئینی و قانونی گنجائش نہیں ہے۔ جمہوریت میں اس کا طریقہ کار موجود ہے۔ اختیارات کی اس غیر مساوی تقسیم نے اس مسئلہ کو مزید خراب کیا ہوا ہے۔ اس کا حل یہ ہی ہے کہ سویلینز کو ان کا کام بغیر کسی دباؤ میں کرنے دیا جائے اور فوج کی سیاسی امور میں مداخلت کو یکسر مسترد کیا جائے۔
آٹھواں حصہ سفارتی تعلقات کی تاریخ پر ہے۔ اس میں چار ابواب ہیں۔ پہلے باب میں پاکستان کی سفارتی اور خارجہ پالیسی کے مقاصد پر بات کی گئی ہے۔ اس میں خارجہ پالیسی کی تشکیل کے تین ذرائع کا مصنف نے ذکر کیا۔ پہلا ملک کا صدر یا وزیراعظم اس کو طے کرتا ہے۔ زیادہ تر تو سربراہ مملکت مشاورت سے اس کو تشکیل دیتا ہے لیکن کبھی سربراہ مملکت اپنی پارلیمان کو بتائے بغیر بھی اس کو وضع کرتا ہے جیسے کہ ۱۹۵۶ میں برطانوی وزیر اعظم انتھونی ایڈن نے مصر پر قبضے کے لیے کابینہ سے مشاورت نہیں کی۔
دوسرا ذریعہ وزیر خارجہ ہے۔ اگر سربراہ مملکت خارجہ امور میں زیادہ دلچسپی نہ لے تو یہ ذمہ داری وزیر خارجہ لیتا ہے۔ یہاں پر بھی برطانیہ کی مثال دی کہ کلیمنٹ ایٹلی کی وزارت اعظمی میں ارنسٹ بیون نے یہ کام سر انجام دیا۔
تیسرا ذریعہ دفتر خارجہ ہوتا ہے جو خارجہ پالیسی وضع کرتا ہے۔ پاکستان کے تناظر میں یہ تینوں ذرائع ثانوی ہیں یہاں پر ملٹری اسٹبلشمنٹ کا کردار ان سب پر حاوی ہوتا ہے جو خارجہ پالیسی کو وضع کرتی ہے۔ ایسا نہیں کہ باقی ممالک میں ملٹری اسٹبلشمنٹ کا خارجہ پالیسی پر اثر نہیں ہوتا مگر پاکستان میں اور دیگر تیسری دنیا کے ممالک میں اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔
کئی دفعہ عوامی جذبات بھی خارجہ پالیسی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ۔ کبھی حکومت ان کے دباؤ کے تحت اپنی پالیسی کو تبدیل کرتی ہے اور کبھی وہ ان کی پرواہ کیے بغیر اپنی پالیسی پر عمل کرتے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پاکستان نے ابتداء میں ہی غیر جانبداری کی پالیسی اختیار کی اور کہا کہ وہ کسی کیمپ کا حصہ نہیں بنے گا مگر دوسری جانب بھارت کا روس کی طرف جھکاؤ سے پاکستان امریکی کیمپ میں داخل ہوا۔
پاکستان کے عالمی طاقتوں سے سفارتی تعلقات کی تاریخ پر مصنف نے ایک باب لکھا ہے۔ جس میں پاکستان کے امریکہ، روس ، چین اور برطانیہ کے ساتھ تعلقات کی تاریخ ذکر کی ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہے مگر اس میں اتار چڑھاؤ بھی آتا رہا۔۔ فوجی ادوار یعنی کہ ایوب ، ضیاء اور مشرف دور میں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ مجموعی طور پر خوشگوار تعلقات رہے جبکہ جمہوری ادوار میں نسبتاً سرد مہری آتی گئی۔پاکستان امریکی کیمپ کا حصہ بنا، سیٹو سینٹو معاہدوں میں شامل ہوا۔ چین اور امریکہ کے مابین سفارت کاری کے لئے پاکستان نے کوششیں کیں۔ افغان جنگ میں روس کے خلاف امریکہ کا بلواسطہ اتحادی بننے اور پھر دوسری جنگ میں براہ راست اتحادی بننے کے ساتھ ساتھ کئی مواقع پاکستان کو امریکی پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔
لیاقت علی خان کے روس کے دورہ نہ کرنے کی ڈاکٹر صاحب نے وجہ بیان کی ہے کہ روس کی جانب سے دی گئی تاریخ میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کا روس جانا ممکن نہ تھا۔ اس پر ان سے تاریخ کی تبدیلی کی درخواست کی گئی جس کا روس کی جانب سے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر پاکستان بننے پر بھی روس نے کوئی مبارکباد کا پیغام نہیں دیا۔روس کے ساتھ ہمارے تعلقات زیادہ تر کشیدہ رہے۔ اور اکہتر میں روس نے پاکستان کی شکست میں اپنا سفارتی کردار ادا کیا۔
چین کے ساتھ تعلقات ہمارے دوستانہ ہیں لیکن یہ ہمیشہ سے نہیں ہیں۔ جب ۱۹۶۰ میں چین بھارت کی جھڑپیں ہوئیں تو صدر ایوب خان نے جواہر لعل نہرو کو چین کے خلاف مشترکہ اتحاد کی پیشکش کی جسے کو نہرو نے قبول نہیں کیا۔ پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات اس کے بعد استوار ہوئے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے گئے۔ حالانکہ پاکستان چین کو تسلیم کرنے والے پہلے ممالک میں سے تھا۔ لیکن چین پاکستان کی سیٹو اور سینٹو میں شمولیت کے خلاف تھا۔ وہ پاکستان کے امریکہ کی طرف جھکاؤ کو بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ بعد میں ۱۹۶۳ میں دونوں ممالک نے اپنی سرحدوں کا تعین کیا اور ان کے درمیان تجارتی تعلقات قائم ہوئے۔ ۶۵ کی جنگ میں چین نے پاکستان کو مدد کی پیشکش بھی کی مگر پاکستان نے کوئی زیادہ مثبت جواب نہیں دیا۔
برطانیہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں مصنف نے لکھا کہ انگریزوں کی عجلت اور غیر منصفانہ تقسیم کے باعث پاکستان کے بہت سے مسائل کا ذمہ دار برطانیہ تھا۔ ۶۵ کی جنگ میں برطانوی وزیر اعظم نے پاکستان کے حق میں بیان دیا مگر اکہتر میں برطانیہ کا رویہ ایسا نہیں تھا۔ برطانوی رویہ کے خلاف پاکستان نے ۱۹۷۲ میں دولت مشترکہ سے علیحدگی اختیار کی جبکہ ۱۹۸۹ میں محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں پاکستان واپس دولت مشترکہ کا رکن بنا۔
سارک ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے بارے میں بھی ایک باب ہے۔ جس میں زیادہ تر حصہ پاک بھارت تعلقات کے بارے میں ہے۔ پاک بھارت تعلقات ابتداء سے ہی سرد مہری کا شکار رہے۔ پاکستان کو بھارت سے جنگیں لڑنی پڑیں۔ ابتداء سے ہی مسئلہ کشمیر سمیت سرحدی تنازعات کی وجہ سے دونوں ممالک میں کبھی اچھے تعلقات نہیں بن سکے۔ پھر اثاثوں کی تقسیم کے بارے میں بھی بھارت نے پاکستان کا حصہ نہیں دیا۔ بھارت کے علاؤہ پاکستان کے بنگہ دیش اور افغانستان سے تعلقات کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب نے مختصر گفتگو کی ہے۔
مسلم ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر بھی ایک باب ہے۔ ابتداء میں بھارت نے پاکستان کے قیام کو برطانوی سازش کہا۔ جس کی وجہ سے مسلم دنیا میں پاکستان کے بارے میں کوئی دوستانہ فضا قائم نہ ہو سکی۔ سویز نہر کے مسئلہ پر پاکستان نے عربوں کے خلاف برطانیہ کا ساتھ دیا۔ اس سے پاکستان کے بارے میں عرب ریاستوں میں مزید منفی تاثر پھیلا۔ ۱۹۶۷ کی عرب اسرائیل جنگ میں عربوں کو بہت بری شکست ہوئی لیکن پاکستان نے عربوں کی بھرپور سفارتی حمایت کی جس سے اس کے تعلقات عربوں سے خوشگوار ہوئے۔ بعد میں مسجد اقصیٰ میں انتہا پسند یہودیوں کی جانب سے آتش زنی کے واقعے کے بعد مسلمان ممالک ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے اور او آئی سی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس میں بھارت کو بھی مدعو کیا گیا لیکن پاکستان کے احتجاج کے بعد بھارت کو شامل نہ کیا گیا۔ بہرحال اس کے بعد پاکستان کے عرب ریاستوں کے ساتھ بہتر تعلقات استوار ہوئے۔
نواں حصہ پاکستان کی معاشی تاریخ کے بارے میں ہے۔ اس میں کچھ باتوں کا سیاسی دور والے حصے میں بھی ذکر ہو چکا ہے جس میں ان ادوار میں ہونے والی معاشی نشو و نما پر گفتگو ہو چکی ہے۔ پاکستان کو ابتداء میں بھارت کی جانب جو مسائل درپیش ہوئے۔۔نظام دکن نے مدد کی کوشش کی تو ان کا چیک کیش نہیں ہونے دیا گیا۔ پھر بعد میں جو ممالک بھارت کو مال بیچ رہے تھے نے پاکستان سے کاروبار کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ ایوب دور میں کچھ ترقی ہوئی مگر پینسٹھ کی جنگ نے اس رفتار کو ریورس گئیر لگا دیا۔ بھٹو صاحب کی نیشنلائزئشن اور بعد کے ادوار میں معاشی ڈھانچے کی تشکیل نو پر اختصار سے گفتگو کی ہے۔
اس حصے میں ایک اہم بات BCCI کے عروج و زوال پر ڈاکٹر کاظمی صاحب کا مضمون ہے کہ کیسے ایک بڑا ادارہ جس کی ملک بھر میں متعدد شاخیں تھیں زوال پذیر ہوا۔ اس میں کچھ حکام بالا کی پالیسیاں اور پھر منی لانڈرنگ کے الزامات کے سبب یہ ادارہ زوال پذیر ہوا۔
اس کے ساتھ کالاباغ کے ڈیم پر بھی ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی ہے کہ کیسے یہ منصوبہ سیاست کی نظر ہو کر اب تقریباً ناقابل عمل ہو چکا ہے۔ یہ ملک کے لیے ایک بڑا اہم پراجیکٹ ہو سکتا تھا لیکن ہمارے ارباب اختیار نے اس معاملے میں کافی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔
دسواں باب پاکستان کی ثقافتی تاریخ کے بارے میں ہے۔ جس میں کلچر کی تعارف اور اس کے خدوخال پر مصنف نے بات کی ہے اور بتایا کہ کلچر کی کوئی ایک خاص تعریف نہیں ہے۔ پھر کلچر کو تہذیب کے مترادف کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا کہا جا سکتا ہے کلچر مختلف عوامل کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں آپ عادات و اطوار ، طرزِ تعمیر ، بود و باش اور رہن سہن سمیت آپ کی معاشرتی اقدار اور ادارے شامل ہوتے ہیں۔
پاکستان میں آرٹ اور کلچر کے میں قدیمی اور جدید آرٹ اور پھر قدیم و جدید کا امتزاج ان سب کو ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے۔
پاکستان میں بولنے والی مختلف زبانوں جیسے کہ اُردو ، پنجابی ، پشتو، سندھی اور بلوچی میں جو ادبی طور پر ترقی ہوئی اس کا بھی ایک خاکہ مصنف نے پیش کیا اور ان سب زبانوں کے کچھ نمایاں ادیبوں اور شاعروں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اس زبان کے فروغ میں اپنا کردار ادا کیا۔
اس حصے کے آخری باب میں پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی جدوجہد کا بھی ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ سفر اب بھی جاری ہے۔ انسانی حقوق کے بارے میں بدقسمتی سے پاکستان کی صورتحال کوئی زیادہ مثبت نہیں ہے بالخصوص جو کچھ پچھلے چند سالوں میں دیکھا گیا ہے اس کے بعد مصنف کی لکھی گئی باتوں کی اہمیت ہی کم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اٹھارہ سال پرانی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے پچھلے تین چار سالوں میں اس بگڑتی صورتحال کو ہم براہ راست محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن انسانی حقوق اور آزادی کی یہ جدوجہد ختم نہیں ہوئی جو کہ امید کی ایک کرن ہے۔
ڈاکٹر کاظمی صاحب کی یہ کتاب اس لحاظ سے مختصر ہے کہ انہوں نے تقریباً چار سو صفحات میں پاکستان کی قدیم ہندوستان سے لیکر دو ہزار سات کی تاریخ کو بیان کیا۔ تو دوسری طرف یہ کتاب ایک عام قاری کو پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے ایک جامع تصویر پیش کرتی ہے جس کو مزید تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ تیسری طرف ہم اس کتاب کو مفصل اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک جہت پر تاریخ کو ذکر نہیں کیا بلکہ تاریخ سے لیکر ثقافت تک، مسلم دور سے لیکر انگریزوں تک ، پھر قیام پاکستان کے بعد کی بھی ساٹھ سالہ تاریخ سمیت اس دوران ہونے والی سفارتی، معاشی اور آئینی تبدیلوں کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے۔
ایک اور اہم بات اس کتاب کے اندر شخصی تعارف ہے۔ جس میں ڈاکٹر کاظمی صاحب نے متعدد اہم شخصیات کا شخصی تعارف پیش کیا ہے جن میں قائد اعظم محمد علی جناح ، لیاقت علی خان، مہاتما گاندھی، جواہر لعل نہرو ، مولانا ابوالکلام آزاد ، گوپال کرشنا گوکلے ، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی ، مولانا حسرت موہانی ، رانی حضرت محل ، خواجہ امیر خسرو ، ذوالفقار علی بھٹو ، بینظیر بھٹو ،ڈاکٹر محبوب الحق اور حفیظ جالندھری قابلِ ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور شخصیات کا شخصی تعارف اس کتاب میں موجود ہے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب تاریخ کے ساتھ ساتھ بہت سی اہم شخصیات سے بھی ہمیں متعارف کراتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے نتائج فکر سے اختلاف کی گنجائش بھی ہے ، میں نے اس بارے میں چند ایک مقام پر اپنا اظہار کیا ہے لیکن ماہرین مزید اس پر اپنی مختلف رائے دے سکتے ہیں کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے جس میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔




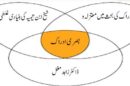
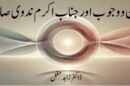












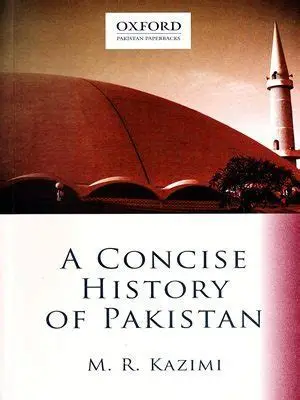
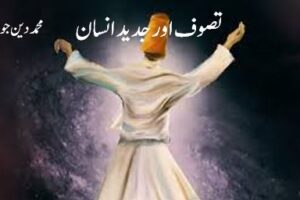
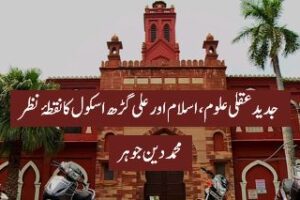

کمنت کیجے