امام ابن تیمیہؓ واضح کرتے ہیں کہ ان کے دور میں مسلمانوں کے ہاں ’’شریعت’’ کا لفظ تین معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے:
۱۔ وہ شریعت جو کتاب وسنت میں نازل ہوئی ہے اور جس کی اتباع ہر مدعی ایمان پر لازم ہے۔ جو یہ سمجھے کہ کچھ لوگوں پر اس کی اتباع واجب نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
۲۔ وہ احکام شرعیہ جو مجتہدین کی تاویل اور فہم واستنباط سے سامنے آئے ہیں اور جن کے متعلق ان کے مابین اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ ایسے امور میں عام مسلمان کسی بھی مجتہد کی پیروی اختیار کر سکتے ہیں جس کے متعلق ان کا گمان ہو کہ اس کی حجت قوی ہے، لیکن کسی خاص مجتہد کی پیروی عام مسلمانوں پر لازم نہیں۔ امام صاحبؒ فقہ کے ان طلبہ کے رویے کی بھی اصلاح کرتے ہیں جو اپنے معتمد اور نیک اساتذہ کی ترجیح کو یہ درجہ دینے لگتے ہیں کہ ان کی رائے ہی صحت وصواب کا معیار ہے اور جو دوسرے اہل علم ان سے اختلاف کرتے ہیں، وہ شریعت کے مخالف ہیں، دراں حالیکہ وہ شریعت کے نہیں بلکہ اس اجتہاد کے مخالف ہوتے ہیں جنھیں یہ متفقہین شریعت کا درجہ دے رہے ہیں۔
۳۔ وہ ’’شریعت’’ جو باطل اور بے بنیاد ہے اور من گھڑت دلائل کی روشنی میں مختلف گروہوں نے اس کی پیروی اختیار کر رکھی ہے۔ امام صاحب اس ضمن میں بعض فقہی گروہوں اور متصوفین کا ذکر کرتے ہیں جو اپنے متعلقین پر خاص فقہی مذہب یا صوفیانہ مسلک کی پیروی کو لازم قرار دیتے اور اس سے خروج کو شریعت محمدیہ سے خروج کا درجہ دیتے ہیں۔
(مجموع الفتاوی ج ۱۱ ص ۴۳۰، ۴۳۱)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
امام صاحب کی یہ نشان دہی صرف ان کے دور کے لیے نہیں، بلکہ تقریباً ہر دور کے لیے درست ہے اور کسی بھی مذہبی روایت میں ان دونوں طرح کے رویوں کا پیدا ہو جانا ایک عام معمول ہے جس پر متنبہ رہنا اور معاشرے کے اہل فہم کو متنبہ رکھنا ضروری ہے۔
ان میں سے پہلا رویہ اصلاً علم وفقہ سے دلچسپی رکھنے والوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اپنے اساتذہ ومشائخ پر اعتماد اور ان کے فقہی رجحان کے ساتھ وابستگی ایک فطری بات ہے جو حدود کے اندر محمود ہے، لیکن عموماً یہ حدود سے متجاوز بھی ہو جاتی ہے۔ متعلقین ومتوسلین میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو تعبیر یا تاویل ان کو درست لگتی ہے، اس کی معاشرے میں بھی یہی حیثیت مانی جائے اور مخالف تعبیرات کو معاشرے میں عصبیت حاصل نہ ہو۔ اسی سے غیر ضروری بحث ومباحثہ اور نزاع وجدال کے سارے راستے کھلتے ہیں۔
دوسرا رویہ بنیادی طور پر اہل علم کے بجائے معاشرے کے عام طبقات میں پیدا ہوتا ہے جو کسی چیز کے ساتھ وابستگی استدلال اور فہم کی بنیاد پر نہیں، بلکہ رواج اور عام قبولیت کی بنیاد پر اختیار کرتے ہیں اور اسی لیے ان کا تعصب بھی حد سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ پھر عوامی سطح پر جو مذہبی پیشوا ان تعصبات کی نمائندگی کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، وہ اپنی پست علمی سطح اور کردار اور عصبیت سے وابستہ مفادات کی بنیاد پر عوام کے تعصب کو اور بڑھاوا دینے لگتے ہیں تاکہ ان کی سیادت اور مفادات کو کوئی ادنیٰ خطرہ بھی درپیش نہ ہو۔ یہی پیشوا پھر فروعی اور جزوی چیزوں بلکہ باطل اور من گھڑت مسائل کو بھی ’’شریعت محمدیہ’’ کا درجہ دے کر اسے عوام کے لیے شناخت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں اور ہر طرح کی جہالت، فتنہ بازی اور تشدد کو انگیخت کر کے اپنی پیشوائی کو تسلسل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
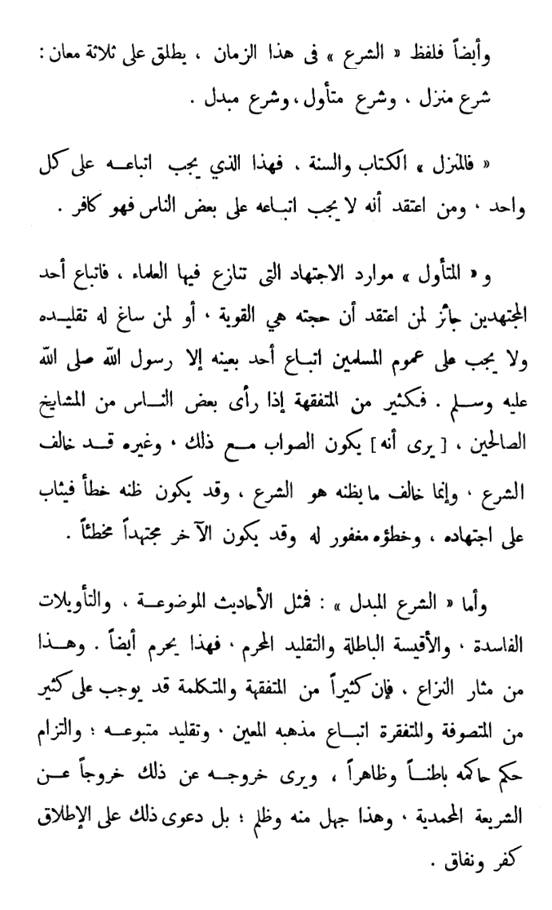


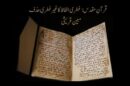















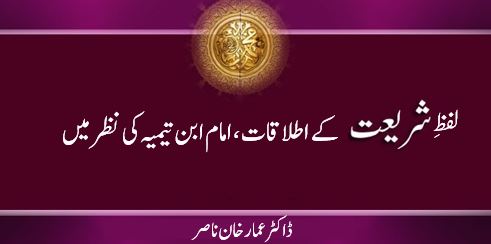



کمنت کیجے