
عاطف حسین
قرآن کریم کے اولین نسخے بغیر نقطوں اور حرکات (زبر، زیر، پیش) کے بغیر تھے۔ اب اگر بغیر نقطوں کے لکھے جائیں تو یعلمون اور تعلمون، کبیر اور کثیر، بشرا اور نشرا ایک جیسے نظر آئیں گے اور اگر نقطوں کا مسئلہ نہ ہو یا حل کر لیا جائے تو بھی حرکات مختلف ہوسکتی ہیں۔ مثلاً ملک، مٰلِکِ یا مَلِکِ ہوسکتا ہے اور نشرا، نُشراً یا نَشراً ہو سکتا ہے۔ اگر یہ بھی حل ہوجائے تو تلفظ میں اختلاف ہو سکتا ہے مثلاً اعلیٰ کو اعلا پڑھا جائے، اعلے یا ان کے درمیان، بل توثرون میں لام واضح پڑھا جائے یا توثرون کے تا میں ملا دیا جائے وغیرہ۔
اب ان ممکنہ قراتوں میں سے کونسی درست مانی جائے گی اس کا انحصار اس فن کے ماہرین نے تین چیزوں پر بتایا:
1۔ اس کی گنجائش مصحف عثمانی کے کسی نسخے میں ہونی چاہیے۔ مثلاً مصحف عثمانی میں جو ملک یوم الدین لکھا ہوا ہے اس کو مَلِکِ یوم الدین یا مٰلِکِ یوم الدین تو پڑھا جاسکتا ہے لیکن عزیزیوم الدین نہیں پڑھا جاسکتا کیونکہ “ملک” کی علامت کا عزیز ہونا کسی طرح ممکن نہیں۔
2۔ جو کچھ پڑھا جارہا ہے وہ نحوی طور پر درست ہو۔ یعنی اس کا کچھ مطلب بنتا ہو اور وہ اس سیاق سباق میں درست بھی معلوم ہوتا ہو۔
3۔ اور پھر سب سے ضروری شرط یہ ہے کہ صحیح سند سے دکھایا جاسکتا ہو کہ کسی صحابی نے اس آیت کو ایسے پڑھا ہے۔ دراصل یہ شرط سب سے ضروری ہے اور باقی دونوں پر مقدم بھی۔ یعنی ایک لفظ کو پڑھنے کی گنجائش رسم عثمانی اور نحو دونوں میں موجود ہو لیکن ایسی کوئی سند نہیں کہ کسی صحابی نے ایسے پڑھا ہے تو وہ درست قرات کسی صورت نہیں مانی جائے گی۔ (دراصل سند ہی سب سے مقدم شرط ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رض کی قرات کے کئی جگہ رسم عثمانی سے مختلف ہونے کے باوجود ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ متواتر نہیں ہے لیکن ہم اصرار نہیں کرسکتے کہ یہ غیر قرآن ہے)۔
اب اگر دوآیتیں ہوں اور ان دونوں میں ایک ایک لفظ کو مختلف پڑھا جاسکتا ہے تو ان دو آیتوں کی چار مختلف قراتیں ہوسکتی ہیں۔ لہذا ان شرائط پر پورا اترتے ہوئے بھی ہزاروں قراتیں ممکن ہیں لیکن اس فن کے “صاحبِ اختیار” ماہرین نے زبان اور سند کے علم کی روشنی میں بعض قراتوں کو “اختیار” کیا۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ پہلی آیت اگر یوں پڑھی جائے تو دوسری یوں اور تیسری یوں۔۔ یعنی پورے مصحف کو یوں پڑھا جائے اور تلفظ یوں کیا جائے۔ یہ لوگ قرات کے آئمہ ہوئے۔
یہ چونکہ آئمہ تھے تو انہوں نے ایک سے زائد درست طریقے بھی بتائے۔ لہذا ایک امام کی کوئی ایک ہی قرات نہیں تھی بلکہ کئی ایک تھیں جن میں سے کسی ایک کو ایک شاگرد نے آگے روایت کیا تو کسی کو دوسرے نے۔ یہ ان آئمہ کے راوی کہلائے۔ اور یہ چونکہ محض راوی نہ تھے بلکہ خود بھی اس فن کے آئمہ تھے تو انہوں نے اپنے اختیار بھی کیے جن کو ان کے شاگردوں نے روایت کیا اور پھر شاگردوں کے روایت میں بھی تھوڑے بہت اختلاف تھے۔ مثال کے طور پر عام طور پر رائج قراتِ حفص کو دیکھیے تو حفص عاصم کے راوی تھے۔ لیکن عاصم سے صرف انہوں نے روایت نہیں کی بلکہ دیگر گئی شاگردوں نے بھی روایت کی۔ جن میں سے ایک شعبہ بھی تھے جن کی قرات میں حفص کی قرات سے کئی اختلافات موجود ہیں۔ اب آگے ان دونوں سے کئی کئی شاگردوں نے آگے روایت کی جن کے آپس میں بھی تھوڑے بہت اختلافات تھے۔ فرض کرلیں کہ ان دونوں سے پانچ پانچ شاگردوں نے تھوڑے بہت اختلافات کے ساتھ روایت کی ہو تو صرف عاصم کی دس قراتیں ہوگئیں۔
اس قدر زیادہ اختلافات چونکہ تعلیم اور تعبیر کے کئی مسائل کو جنم دیتے ہیں لہذا اس میں بھی standardization کی ضرورت ہوئی۔ تو سب سے پہلے تیسری صدی ہجری میں ابن مجاہد (رح) نے سات بڑے آئمہ کا انتخاب کیا جن کی قراتیں ان کے نزدیک شروع میں مذکور تین شرائط پر خوب پوری اترتی تھیں۔ انہوں نے درج ذیل آئمہ کا انتخاب کیا:
1۔ مکہ سے ابن کثیر (رح)
2۔ مدینہ سے نافع (رح)
3۔ شام سے ابن عامر (رح)
4۔ بصرہ سے ابی عمرو (رح)
5،6،7۔ کوفہ سے عاصم (رح)، حمزہ (رح) اور کسائی (رح)
ان کے نزدیک ان سات آئمہ کی مختلف قراتیں بالعموم درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی تھیں۔ انہوں نے سات کا انتخاب سبع احرف والی حدیث کی نسبت سے یا پھر اصل مصحف عثمانی کے ساتھ نسخوں کی نسبت سے کیا۔ تاہم یہاں دو باتیں اہم ہیں۔ اول یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان سات کے علاوہ باقی “غلط” ہیں بلکہ یہ سات ان کے نزدیک سب سے بہتر تھے اور چونکہ انہوں نے صرف سات کا انتخاب کرنا تھا تو یہ بھی روایت ہوا ہے کہ وہ کچھ عرصہ تذبذب میں بھی رہے کہ ساتویں نمبر پر کسائی کا انتخاب کریں یا یعقوب حضرمی کا۔ دوم یہ کہ ابن مجاہد نے صرف آئمہ کا انتخاب کیا۔ ان کے راویوں اور راویوں کے راویوں کا انتخاب نہیں کیا۔ لہذا جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے کہ ان ساتھ آئمہ سے منسوب بھی درجنوں قراتیں موجود تھیں۔
لہذا پھر اگلے مرحلے میں ابو عمرو الدانی (رح) نے چوتھی/پانچویں صدی میں مزید تحدید کرتے ہوئے ان سات آئمہ کے صرف دو دو (ان کی نظر میں) مستند ترین راویوں اور ان راویوں کے آگے صرف ایک “طریق” کا انتخاب کیا۔ گویا اب ایک امام سے منسوب صرف دو قراتیں یعنی سات سے منسوب چودہ قراتیں رہ گئیں جو درج ذیل ہیں:
1۔ ابن کثیر سے بزی اور قبنل
2۔ نافع سے ورش اور قالون (یہ دونوں مغرب یعنی تونس، مراکش، الجزائر، لیبیا وغیرہ میں آج بھی رائج ہیں)
3۔ ابن عامر سے ہشام اور ابن ذکوان
4. ابو عمرو سے سوسی اور دوری (ثانی الذکر سودان اور یمن کے بعض علاقوں میں آج بھی رائج ہے)
5۔ عاصم سے شعبہ اور حفص (حفص عن عاصم ہی وہ قرات ہے جسے ہم آج مسلم دنیا میں سب سے زیادہ سنتے ہیں اور عام طور پر اسی کو اکیلی قرات سمجھتے ہیں)۔
6۔ حمزہ سے خلف اور خلاد
7۔ کسائی سے دوری اور ابی حارث (یہ وہی دوری ہیں جنہوں نے ابو عمرو سے بھی روایت کی ہے)۔
اس کے بعد چھٹی صدی ہجری میں علامہ شاطبی (یہ ابوالقاسم شاطبی ہیں، مشہور علامہ شاطبی سے مختلف شخصیت) نے اپنی قراتِ سبعہ کے اصولوں پر مشتمل مشہور نظم لکھی جو شاطبیہ کے نام سے مشہور ہے اور اس نے سات قراتوں پر گویا ٹیکسٹ بک کی حیثیت کرلی۔ اس کے بعد سے ظاہر ہے ٹیکسٹ بک کے متن میں متحجر ہوجانے کی وجہ سے ان چودہ قراتوں کی تعلیم آسان ہوگئی لیکن یاد رہے کہ باقی قراتیں بھی زبانی طریقے سے پڑھائی جاتی رہیں اور شیوخ ان کی اجازت دیتے رہے۔
قراتوں کی standardization میں اگلا مرحلہ آٹھویں/نویں صدی ہجری میں آیا جب ابن الجزری (رح) سات آئمہ میں مزید تین مشہور آئمہ کو شامل کیا جو درج ذیل ہیں:
1۔ ابو جعفر مدنی۔ ان کے دو راوی ابن جماز اور ابن وردان ہیں
2۔ یعقوب حضرمی۔ ان کے دو راوی رویس اور روح ہیں
3۔ خلف العاشر (یہ وہی خلف ہیں جو حمزہ کے راوی بھی ہیں)۔ ان کے دو راوی اسحاق اور ادریس ہیں۔
[ابن الجزری نے ایک موقعہ پر مزید چار قراتوں یعنی حسن بصری، یزیدی، ابن محیصن اور اعمش کا بھی انتخاب کیا لیکن پھر ان کو متواتر یا مشہور قرار دینے سے گریز کرتے ہوئے انہیں شاذ ہی شمار کیا]۔
اب گویا سات کے بجائے دس سٹینڈرڈ قراتیں ہوگئیں اور دو دو راوی ملا کر کل بیس روایتیں ہوگئیں جن کا متواتر/مشہور مان لیا گیا۔ نویں صدی ہجری کے بعد پھر ابن مجاہد، دانی، شاطبی یا ابن الجزری کے پائے کا کوئی قاری پیدا نہ ہوا جو مزید کوئی تبدیلی کرتا اور شاطبی اور جزری کی ٹیکسٹ بکس کی وجہ سے رفتہ رفتہ یہی دس (یعنی بیس قراتیں) پڑھائی جانے لگیں اور دیگر متروک ہوگئیں۔ اب بیشتر علماء ان کے علاوہ باقی کسی قرات کو نماز میں پڑھنا جائز نہیں سمجھتے۔ بلکہ نماز تو کجا، مصری قاری عنتر مسلم نے جب مجمعوں میں ان قراتوں پر تلاوت شروع کی جن کو اب “شاذ” مان لیا گیا ہے تو ہنگامہ کھڑا ہوگیا اور الازہر نے ان کے خلاف فتویٰ دیا، ان کے کیسٹس مارکیٹوں سے ضبط کرلیے گئے اور انہیں توبہ نامہ شائع کرنے پر مجبور کیا گیا۔
جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، موجودہ بیس standard قراتوں کا انتخاب اور صورت گری لمبے عرصے میں ہوئی ہے جس پر کئی عوامل اثر انداز ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ابن مجاہد سات کی بجائے پانچ یا آٹھ ائمہ کا انتخاب کرتے تو کوئی اور صورت حالات ہوتی۔ پھر دانی نے ہر قاری کے جو دو راوی چنے اس میں اپنی ترجیحات بھی شامل تھیں۔ جن راویوں کے شاگرد کم تھے، یا جو علمی مراکز سے ذرا دور تھے یا جو کسی علاقے یا گروہ کے ساتھ زیادہ conform نہیں کرتے تھے وہ canonical روایتوں میں جگہ پانے سے رہ گئے۔ پھر اس انتخاب میں سیاسی رسوخ بھی استعمال ہوا۔ مثال کے طور پر ابن شنبوذ جو کہ ایک مشہور قاری اور راوی تھے ان کی شاذ قراتوں کی حیثیت کے بارے میں عمومی رائے سے اختلاف کی وجہ سے ابن مجاہد کے فتوے کی بنیاد پر سرکاری سطح پر تادیب بھی ہوئی اور انہیں اپنی رائے سے رجوع پر مجبور کیا گیا۔
حفص کی قرات جو آج دنیا بھر میں سب سے زیادہ رائج ہے، تاریخی طور پر اس کے بھی کئی versions تھے (ابن مجاہد نے 9 طرق ذکر کیے ہیں) جن میں سے ایک بعد میں standard مانا گیا ۔ پھر مسلمانوں کی آخری عالمی سلطنت یعنی عثمانیوں نے اپنی سلطنت میں اس کی حوصلہ افزائی کی۔ پھر اس کو اصل عروج الازہر کی تصدیق سے قرآن کریم کے مصری نسخے کی چھپائی سے بیسویں صدی میں حاصل ہوا۔ چھپے ہوئے نسخے کیلئے حفص عن عاصم کا انتخاب غالباً اس وجہ سے بھی ہوا کہ امالے، تقلیلیں اور ادغامات وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی چھپائی نسبتا آسان تھی۔ ورنہ الازہر میں باقی قراتیں آج بھی نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں جسے کوئی بھی یوٹیوب پر دیکھ سکتا ہے۔
موجودہ زمانے میں جو یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ قرات تو ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ باقی سب غیر قرآن ہے یہ ایک لغو، بے بنیاد، ہٹ دھرمی پر مبنی بات ہے جو جدید ذہن کی سادہ پسندی اور exclusionary instinct سے پیدا ہوئی ہے اس کی تائید نہ تاریخی شواہد کرتے ہیں اور نہ ہی عقل۔
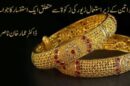
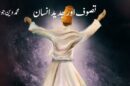
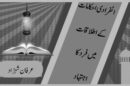
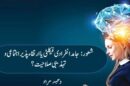















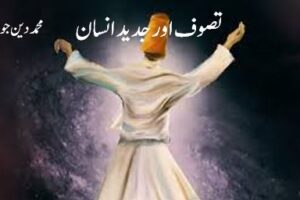
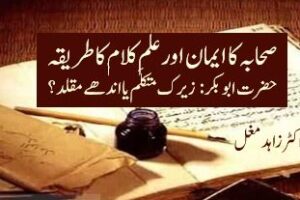

کمنت کیجے