یہاں اختصار کے ساتھ ائمہ اشاعرہ و ماتریدیہ کا میٹافزیکل سسٹم سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس موضوع کو نہ سمجھنے کی بنا پر کئی محققین خلط مبحث کا شکار ہوکر علم کلام کے مباحث پر غیر ضروری نقد کرتے ہوئے جدید علم کلام کی تشکیل کی لاحاصل خطبیانہ باتیں کرتے ہیں۔ یہاں دلائل بیان کرنا مقصود نہیں، موضوع کی پیچیدگی و طوالت کے باعث اشارات پر اکتفا کیا جائے گا۔
1۔ میٹافزکس کا ایک پہلو موجودات کی اقسام کی ایک ھستیاتی یا وجودی توجیہہ پیش کرنا ہے (یعنی کیا کیا موجود ہے اور کیسے وغیرہ)۔ آسان لفظوں میں یہ “حقیقت کیا ہے” کی بحث ہے۔
2۔ جو اشیا حس میں ہیں ان کے چند خصائص ہیں، مثلاً یہ تبدیل ہورہی ہیں، یہ ایک دوسرے سے ممیز اور جداگانہ ہیں۔ ان حسی اشیا کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے متعدد جوابات دئیے گئے۔ بعض (مثلاً افلاطون) کا خیال ہے کہ اشیا کی کلی ماہیات (جیسے انسان، گھوڑا وغیرہ) خارج میں ایک عالم مثال میں پائی جاتی ہیں، بعض (مثلاً ارسطو) نے کہا کہ یہ ماہیات اشیا میں بطور جزو پائی جاتی ہیں، بعض (مثلاً ابن سینا) نے کہا کہ یہ اشیا میں بطور جزو اور ذہن میں تجریداً پائی جاتی ہیں (اسے “وجود ذہنی” کہتے ہیں)، بعض (مثلاً اکبری روایت والوں) نے کہا کہ یہ خارج میں الگ عالم میں بھی پائی جاتی ہیں اور ذہن میں بھی پائی جاتی ہیں، جبکہ بعض (مثلاً کانٹ) نے کہا کہ ان کی حقیقت وجود ذہنی کی صورت ماقبل تجربہ کلی مقولات ہیں۔ ائمہ اشاعرہ و ماتریدیہ کے مطابق یہ حسی اشیا جواہر و اعراض کے مرکبات ہیں جن کی توجیہہ کے لئے ان سے ماورا کسی خارجی عالم مثال، ان میں پیوست کلی ماہیات اور وجود ذہنی کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ یہ ان کی میٹافزکس کا پہلا بلڈنگ بلاک ہوا۔
3۔ اشیا میں واقع ہونے والی تبدیلی اس بات کی متقاضی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو مستقل (constant یا fixed) ہو، اور اس پر کوئی ایسی کیفیت لاحق ہو جو پہلے موجود نہ تھی۔ مثلا اگر کہا جائے کہ دیوار سفید سے کالی ہوگئی، تو یہ تبھی بامعنی ہے جب سفیدی سے کالک میں تبدیلی کے اس عمل میں کچھ ایسا مستقل عنصر بھی ہو جو برقرار رہا اور اس میں تبدیلی ہوئی۔ اس مستقل عنصر کو جسم (body) کہتے ہیں اور جو تبدیلی اس میں واقع ہوئی (یعنی جو نئی کیفیت یا حالت اس پر لاحق ہوتی ہے) اسے عرض (accident) کہتے ہیں۔
4۔ جوہر (atom) سے مراد جزو لایتجزی (indivisible particle) ہے، یعنی ایک ناقابل تقسیم قائم بالذات عنصر (پارٹیکل) جسے کوئی نہ کوئی عرض ضرور لاحق ہوتی ہے جیسے کہ حیز (space)، کیف (مثلا رنگ، بو، ذائقہ، رطوبت، حیات، قدرت، علم، وغیرہ وغیرہ)۔ یوں بھی کہتے ہیں کہ جوہر وہ عنصر ہے جو جگہ گھیرے۔ جزو لایتجزی کا مطلب یہ کہنا ہے کہ حس میں موجود عالم discrete ہے نہ کہ continuous۔ جسم جواہر کے مجموعے یا امتداد (extension) کو کہتے ہیں۔ اعراض از خود قائم نہیں ہوتیں بلکہ جواہر کے ساتھ قائم ہوتی ہیں۔ جواہر چونکہ کبھی اعراض سے خالی نہیں ہوسکتے اس لئے ہر جسم کو اعراض ضرور لاحق ہوتی ہیں (مثلاً ہر جسم یا حالت حرکت میں ہوگا اور یا سکون میں، حرکت کا مطلب کسی جسم کا دو زمانی ساعتوں میں دو مقامات پر ہونا ہے اور سکون کا معنی دو زمانوں میں ایک مقام پر ہونا ہے۔ پس جوہر اگر متحیز عنصر کو کہتے ہیں تو جسم کبھی ان دو میں سے کسی ایک حال سے خالی نہیں ہوسکتا)۔ اعراض جواہر پر زائد حقیقی صفات (real attributes) ہیں، نہ کہ چند پرائمری صفات کے حامل دیموکریٹیرین (Democratarean) اجزاء کے مرکبات و تعاملات سے ابھرنے والی صفات (باالفاظ دیگر اعراض کسی اور شے میں non reducible ہیں)۔ یہ وہ پہلو ہے جو اشاعرہ و ماتریدیہ کی اٹامک تھیوری کو یونان سے چلنے والی اٹامک تھیوری سے یکسر مختلف بناتا ہے۔
5۔ تمام جواہر الگ (non identical) مگر یکساں (similar) ہوتے ہیں، یعنی جو کچھ ایک جوہر کے بارے میں ممکن و لازم یا صدق (true) ہے وہ دوسرے کے لئے بھی صادق ہے۔ اجسام میں فرق کی وجہ ان جواہر کی صفات مختلف ہونا نہیں جن سے مل کر یہ اجسام مرکب ہوتے ہیں، بلکہ یہ فرق جواہر کو لاحق ہونے والی اعراض کے فرق کی بنا پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سانپ اور چھڑی کے درمیان فرق کی بنیاد یہ نہیں کہ ان دونوں میں موجود جواہر ذاتی طور پر مختلف یا الگ صفات کے حامل ہیں، بلکہ فرق اس لیے ہے کہ چھڑی کے ذرات پر مثلاً موت، سختی، اور ایک خاص مکانی ترتیب جیسے اعراض وارد ہیں، جبکہ سانپ کے ذرات پر زندگی، تری، علم، وغیرہ جیسے اعراض وارد ہیں۔ البتہ یہ ذرات اپنی اصل میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اسی لئے اشاعرہ و ماتریدیہ کے ہاں یہ بات معقول ہے کہ ایک لاٹھی کو سانپ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے اگر اس کے ذرات میں زندگی، خاص رنگ وغیرہ جیسی وہ صفات پیدا کر دی جائیں جو کسی جسم کو سانپ بننے کے لیے درکار ہیں۔ اس کے برعکس اصحاب ہیولی (یعنی ارسطو اور اس کے پیروکاروں) کی وجودیات میں یہ شاید ممکن نہیں اس لئے کہ سانپ و چھڑی ان کے ہاں بنیادی و مستقل ماہیات ہیں اور نتیجتاً سانپ چھڑی نہیں بن سکتی کہ یہ صرف اعراض نہیں بلکہ ماہیات میں تبدیلی سے عبارت ہے (اس میں مزید تفصیل ہے جس کا یہ موقع نہیں)۔
6۔ جوہر کا عرض میں (یا بالعکس) تبدیل ہوجانا محال ہے اس لئے کہ تبدیلی کا عمل کسی ثابت و قائم محل (constant substrata) کے بنا مفہوم نہیں ہوسکتا (مطلب یہ کہ جوہر سے عرض میں تبدیلی کے لئے کوئی مستقل گراؤنڈ یا محل نہ ہوگا جس کے بارے میں کہا جاسکے کہ وہ تبدیل ہوگیا، اگر کہا جائے کہ جوہر کے عرض میں تبدیل ہونے کا معنی یہ ہے کہ جوہر معدوم ہوجاتا ہے اور پھر وہ عرض بن جاتا ہے تو یہ غلط فہمی ہے اس لئے کہ جو معدوم ہوگیا عین اسی کے عرض بن کر ہست ہونے کا کوئی مطلب نہیں بلکہ جو بطور عرض خلق ہوگا وہ الگ وجود ہوگا)۔ اسے یوں کہتے ہیں کہ قلب حقائق ( essential inversion) محال ہے، یعنی اشیا کی حقیقت تبدیل ہوجانا (جیسے جوہر کا عرض بن جانا) ناممکن ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ایک عرض بھی دوسری عرض میں تبدیل نہیں ہوتی بلکہ ایک معدوم ہو کر دوسری اس کی جگہ لیتی ہے (یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا سفیدی ہی لالی بن جاتی ہے بلکہ سفیدی معدوم ہوجاتی ہے اور لالی ظاہر ہوجاتی ہے، سفید ہونا اور لال ہونا الگ حقائق ہیں)، الغرض حقائق یا اسنسز (essences) میں تحول نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ بھی درست نہیں کہ لال اور سفید اپنے سے وسیع تر رنگ نامی کسی کلی حقیقت یا ماہیت میں جمع ہوں کہ یہ ایک ہی ماہیت و حقیقت کا بیک وقت دو چیزوں میں پایا جانا ہے۔ یہ بھی جائز نہیں کہ ماہیات خارج اور ذھن جیسے دو الگ mode of existence میں دو الگ کیفیات کی حامل ہوں (کہ مثلاً آگ خارجی وجود میں تپش والی ہو مگر وہی آگ وجود ذہنی میں اس اسنس کے بغیر پائی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ mode of existence بدلنے سے ماہیت بدل جاتی ہے)۔ اس قسم کے خیالات اینٹی رئیل اسٹ (anti-realist) یا نان اسنشلسٹ (non-essentialist) ہیں۔
7۔ اعراض کو دو زمانوں میں بقا حاصل نہیں ہوتی، البتہ جوہر قائم رہتا ہے (اسی سے اجسام میں تبدیلی کا معنی مفہوم ہوتا ہے)۔ لیکن چونکہ جوہر کبھی اعراض سے خالی نہیں ہوتا اس لئے جوہر و جسم بقا کے لئے اعراض کی تخلیق جدید کے محتاج ہوتے ہیں۔ نتیجتاً جوہر و عرض دونوں ہی بقا کے لئے محتاج ہوتے ہیں۔ اسے یوں کہتے ہیں کہ تمام اجسام ہمہ وقت ایک ایسی علت کے محتاج ہوتے ہیں جو اعراض کی تجدید سے انہیں قائم رکھے۔ اعراض (یا حوادث) کا لامتناہی سلسلہ چونکہ محال ہے، لہذا جسے اعراض لاحق ہوں وہ لازماً حادث ہوتا ہے۔ چونکہ حسی عالم اجسام سے عبارت ہے لہذا یہ حادث ہے۔ اشیا میں کوئی ذاتی تاثیرات نہیں، اس لئے تمام اجسام ایک فاعل مختار کے محتاج ہیں۔ اشیا کا اقتران فاعل کی عادت سے عبارت ہے جسے مدارک علم سے سمجھنے کی کوشش کی جاسکتی ہے۔
8۔ کلی ماہیات و مقولات کا نہ خارجی وجود ہے اور نہ ذہنی، یہ صرف اشتراک لفظی ہیں نہ کہ معنوی (یعنی لسانیاتی کلی حقائق جیسے “انسانیت” (human-ness) یا “گھوڑا پن” (horseness) وغیرہ کا کوئی وجود نہیں، خارج میں صرف جزیات متحقق ہیں)۔
یہ ہے حسیات سے متعلق ائمہ اشاعرہ و ماتریدیہ کی آنٹالوجی کا جنرل نقشہ۔ متکلمین کا یہ میٹافزیکل ماڈل نہ صرف یہ کہ افلاطونی عالم مثال، ارسطوی کلیات، نیوافلاطونی عقول عشرہ اور وجودی میٹافزکس سے یکسر خالی ہے بلکہ یہ دیموکریٹس (Democritus) کی اٹامزم سے بھی مختلف ہے۔ اگر کسی کا دعوی ہے کہ سائنس اور سائنسی طریقہ استدلال نے اسے مسترد کردیا ہے تو وہ دلیل لے آئے، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس قسم کے بڑے بڑے دعوے اکثر و بیشتر اس آنٹالوجی کو سمجھے بغیر ہی کئے جاتے ہیں۔
ہمارا ماننا یہ ہے کہ ائمہ اشاعرہ و ماتریدیہ کے ریسرچ پروگرام نے جو میٹافزیکل سسٹم تیار کیا وہ افلاطون و ارسطو وغیرہ سے بہتر و مؤثر ہونے کے ساتھ ساتھ دینی تقاضوں کی بھی رعایت کرنے والا تھا۔ نیوٹن کی فزکس سے متاثر شدہ کانٹ کی ڈٹرمنسٹک علیت کا میٹافزیکل ماڈل جو علم کو وجود ذہنی بنانے پر منتج ہوتا ہے فلسفے کی دنیا میں آج مرجھا چکا، ہیوم کا سوفسطائیت ذدہ ماڈل لیبارٹری میں تجربہ کرنے والے سائنسدان کو راضی نہیں کرسکتا، کائنات کی تفہیم کے لئے نیو افلاطونیت و علامہ ابن سینا کی عقول عشرہ میں آج سائنس کے طلبا کو دلچسپی نہیں ہوسکتی، اس کے برعکس متکلمین اشاعرہ و ماتریدیہ نے علیت کی بحث کو جس طرح پیش کیا وہ آج بھی دینی عقائد اور عقلی اصولوں سے ہم آھنگی برقرار رکھتے ہوئے ایک رئیل اسٹ فریم ورک کے اندر تجرباتی علم اور ان سے متعلق مختلف میٹافزیکل ماڈلز / تھیوریز کی تشکیل کا ایک بہت وسیع گراؤنڈ فراہم کرتی ہے۔
اسی لئے ہم کہتے ہیں: mutakallimun did an excellent job as compared to their counterparts
ان کا تحقیقی پروگرام زیادہ کامیاب رہا۔
اسی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جدید علم کلام کی تشکیل کا مطلب اس میٹافزیکل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے نئے سوالات کے جوابات تلاش کرنا اور اسے نئے پیرائیے میں پیش کرنا ہے نہ کہ علامہ شبلی نعمانی وغیرہ کی ان خطیبانہ باتوں کو دہرانا جو قدیم علم کلام کی اکثر بحثوں کو بے جا طور پر صرف مسترد شدہ قرار دینے سے عبارت ہیں نیز جو کوئی مثبت راہنمائی فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔
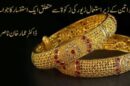
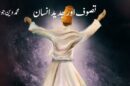
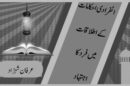
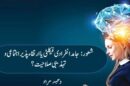














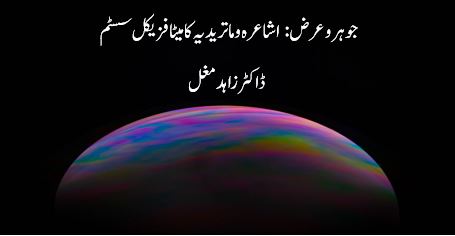
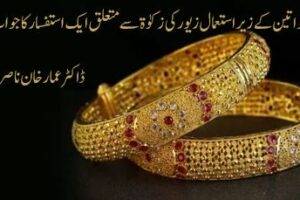
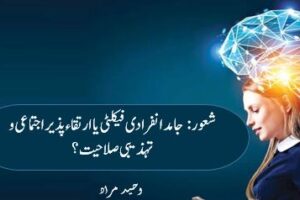
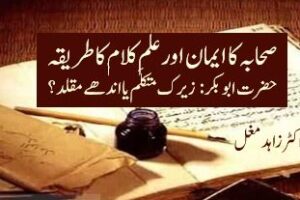
کمنت کیجے