بعض ملحدین کہتے ہیں کہ موجود صرف وہ ہے جو لائق ادراک ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر حقائق کو درست طریقے سے ڈیفائن کرلیا جائے تو آپ کا یہ دعوی غیر متاثر کن ہے اس لئے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہر موجود لائق ادراک ہے۔ ادراک (perception) سے ہماری مراد کسی شے کے بارے میں ایک خاص طرح کا علم، شعور و معرفت ہے (مثلاً جیسے کوئی ہمیں آم کی خبر دے اور پھر ہم آم کو دیکھ لیں، تو اس دیکھنے سے ہمیں جو خاص علم حاصل ہوا اسے بصری ادراک کہتے ہیں)۔ ادراک کی حقیقت میں مدرِک (perceiver) کا پایا جانا، مدرَک (object of perception) کا پایا جانا اور مدرِک میں خاص طرح کا علم پایا جانا شامل ہے، مدرَک کا کسی جہت میں ہونا، مدرِک میں آنکھ و کان وغیرہ ہونا، خارج میں روشنی ہونا وغیرہ یہ سب ادراک کی شرائط نہیں بلکہ امور عادیہ ہیں۔ یہ امور معتزلہ کے نظریہ ادراک کی رو سے ادراک کی شرط ہیں اور اس لئے انہوں نے رؤیت باری کے امکان کا انکار کیا، اشاعرہ و ماتریدیہ کے نزدیک خدا کا لائق ادراک ہونا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ اہل جنت کو یہ ادراک حاصل ہوگا۔ اس امکان ادراک کا مطلب یہ ہے کہ خدا چاہے تو خود سے متعلق بندے میں وہ علم و شعور پیدا کرسکتا ہے جسے ادراک کہتے ہیں۔ الغرض ایسی بات کہنے والا اہل مذہب کے نکتہ نگاہ سے بے معنی بات کررہا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دعوے میں مزید اضافے کرے۔
“موجود وہ ہے جو لائق ادراک ہے” کا وار جب خالی جائے تو ملحدین یہ کہنا شروع کردیتے ہیں کہ موجود وہ ہے جو فی الوقت حسی طور پر مدرَک ہو یا جس کا تصور حسی امپریشن سے منعکس ہو۔ اسے vulgar materialism کہتے ہیں جو خود داخلی تضادات کا شکار ہے۔ اس vulgar materialism کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بذات خود سائنسی نظریات کا بڑا حصہ قابل مشاہدہ نہیں۔ لہذا اس مشکل سے بچنے کے لئے بات بدل کر کہا جاتا ہے کہ موجود وہ ہے جو بذریعہ تجربہ “ویری فائی ایبل” ہو۔ تاہم اس نظرئیے کو بھی اپنے اس پیمانے پر منطق، میتھس اور خود اپنی توجیہہ بیان کرنے میں شدید مشکلات و تضادات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ویری فیکیشن سے کیا مراد ہے؟ اگر مراد یہ ہے کہ کسی معتبر دلیل کی بنیاد پر حس میں آنے والی شے سے کوئی وجود مستنبط ہو، تو ہم اس کے قائل ہیں اور دلیل حدوث اسی کا نام ہے۔ اس پر بعض ملحدین یہ کہتے ہیں کہ جس وجود سے متعلق دعوی بذریعہ تجربہ فالسی فائی ایبل ہو صرف وہ لائق اعتبار ہے۔ علم کی تعریف کا یہ پیمانہ ہی غلط ہے ، اس پر ہمارے چند ملاحظات ہیں :
1) پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ اصول خود اپنے ہی پیمانے پر پورا نہیں اترتا۔ کیا یہ بیان کہ “علمی قضیہ وہ ہے جو تجربے کی رو سے فالسی فائی ایبل ہو” کسی تجربے سے قابل تردید ہے یا نہیں؟ اگر “نہیں”، تو معلوم ہوا کہ یہ اصول خود اپنے پیمانے پر علم نہیں۔ اگر “ہے” تو ہمیں اس تجربے سے آگاہ کیا جائے۔ اگر فالسی فائیبلیٹی کا یہ قضیہ کسی دلیل سے غلط ثابت ہوسکتا ہے تو اس قضئے کا اعتبار جاتا رہا، اس صورت میں علم وہ دلیل ہے جس سے اس کا غلط ہونا ثابت ہوا۔ جس دلیل سے یہ قضیہ غلط ثابت ہوگا یا وہ دلیل بھی قابل تردید ہوگی اور یا نہیں ہوگی۔ اگر نہ ہوئی تو وہ اس پیمانے پر علم نہ ہوگی، اور اگر ہوئی تو ماننا ہوگا کہ آخر میں ایک ایسی دلیل ہونی چاہئے جو ناقابل تردید ہو ورنہ تسلسل لازم آئے گا۔ الغرض اس اصول کو اتنی عمومیت کے ساتھ تمام حقائق و علوم کے لئے پیمانہ بنانا خود ہی متضاد ہے۔
2) دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ نظریہ تمام علم کی کافی توجیہہ کرنے والا نہیں۔ انسانی علم کی بنیاد اولیات عقلیہ کے قضایا ہیں اور وہ ناقابل تردید ہیں، نہ کوئی تجربہ اور نہ ہی شے کے وجود سے متعلق کوئی خیال انہیں رد سکتا ہے بلکہ تمام سائنسی بیانات کی معنویت انہیں مفروضے کے طور پر سچ ماننے پر مبنی ہے۔ “شے یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی” (یعنی شے سے متعلق ہر بیان ثبوت و نفی میں بند ہے)، حادث علت کا محتاج ہوتا ہے، حس میں موجود یہ عالم یا قدیم ہے اور یا حادث، ان میں سے کوئی بھی بیان بذریعہ تجربہ قابل تردید نہیں مگر سب حقیقت ہیں۔ چنانچہ علم کو قابل تردید میں بند سمجھنا غلط پیمانہ ہے۔ اولیات، علم ضروری اور پیچیدہ قسم کی سائنسی تھیوریز تو دور کی بات، خود مشاہدے میں آنے والے متعدد بیانات ایسے ہیں کہ وہ ناقابل تردید ہیں۔ مثلاً “پانی کا ایک یونٹ ایچ ٹو او” ہے، اس بیان کو کسی تجربے سے غلط ثابت نہیں کیا جاسکتا (کیونکہ یہ پانی کی تعریف بن چکی ہے)۔ اسی طرح میتھس کے متعدد قضایا بھی تجربے سے ناقابل تردید ہیں۔
3) تیسرا اعتراض یہ ہے کہ پاپر کا پیش کردہ یہ پیمانہ خود سائنسی نظریات اور سائنس کی تاریخ سے بھی ہم آہنگ نہیں، اس پر متعدد اہل علم نے تفصیلی نقد کررکھا ہے (مثلا دیکھئے Kuhn اور Lakatos وغیرہ کا کام)۔ اس گھسے پٹے خیال کو تمام علم و حقائق کے لئے پیمانہ بناکر اہل مذہب سے خدا کے وجود کی قابل تردید دلیل مانگنا سطحی استدلال ہونے کے ساتھ ساتھ عصری مباحث سے ناواقفیت کی بھی علامت ہے۔ فالسی فیکیشن جیسی باتوں کو ہماری علمی روایت میں فقہیات میں روا رکھا جاتا ہے جہاں مجتہد کا موقف یہ ہوتا ہے کہ میرا قول گمان غالب کی حد تک درست ہے مگر اس احتمال کے ساتھ کہ وہ غلط ہو۔ چنانچہ علم کی تشکیل میں تجربے سے فائدہ اٹھانے کو ہم رد نہیں کرتے، البتہ اسے علم کا واحد پیمانہ بنانا فضول بات ہے۔
4) چوتھا اعتراض یہ ہے کہ فالسی فیکیشن صرف چھانٹی کرنے (sifting) کا پیمانہ ہے (یعنی جو غلط ثابت ہوجائے اسے منظر سے ہٹا دو) نہ کہ کچھ ثابت کرنے کا۔ لہذا فالسی فیکیشن کے اصول سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ وجود اس میں بند ہے، یہ بذات خود ایک فلسفی یا نظری اصول ہے نہ کہ تجربی۔ بلا کسی مثبت دلیل ایسا اصول بنانا محض تحکم ہے۔
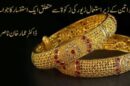
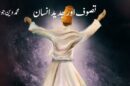
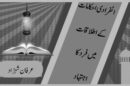
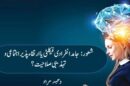














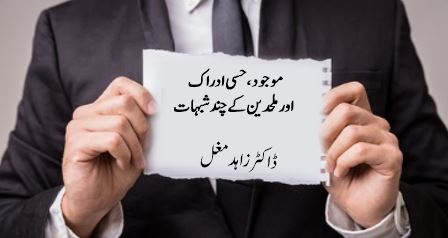
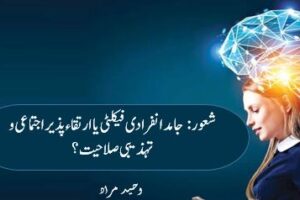
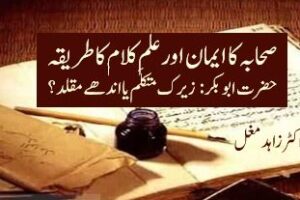
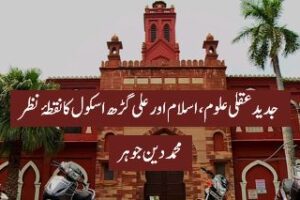
کمنت کیجے