عہدِ روشن خیالی کے دوران معاہدۂ عمرانی یا معاہدۂ سیاسی ظہور پذیر ہوا جس میں ماخذ معاشرہ اور فرد پر حاکمیت کے جواز کے با رے میں سوالات ابھرے۔ معاہدۂ عمرانی(social contract) کے علمبرداروں کانظریہ تھا کہ افراد واضح طور پر یا معنوی طور (tacitly) پر اپنی چند آزادیوں سے رضا مندی سے دستبردار ہو کر حکمران یامجسٹریٹ کے اختیار کے سامنے سرنگوں ہوئے ہیں یا ایک اکثریت کے فیصلے کے سامنے سرنگوں ہوئے ہیں تاکہ ان کے باقی ماندہ حقوق کو تحفظ حاصل رہے۔ اس لیے فطری اور قانونی حقوق کے درمیان تعلق کا سوال، معاہدۂ عمرانی کے نظرئیے کا ایک اہم پہلو ہے۔ اسے مجموعی فلاح کے لیے انفرادی قربانی کا اقرار بھی کہا جاتا ہے۔
نظریۂ معاہدۂ عمرانی کے ماخذ رواقی (Stoic) فلسفے اور رومن اور کلیسا کے قانون میں پائے جاتے ہیں۔ تاہم سترہویں صدی عیسوی کے وسط سے لے کر انیسویں صدی عیسوی کے دوران یہ حکومتوں کے سیاسی جوازوں کے سلسلے میں ایک نمایاں نظرئیے کے طور پر اُبھر آیا تھا۔ نظرئیے کا آغاز انسان کی اس کیفیت کے جائز ے سے ہوتا ہے جس میں کوئی سیاسی نظم نہیں (یعنی وہ حالت فطری پر ہے)۔ اس میں فرد کے کام صرف ان کی ذاتی قوت اور ضمیر کے تابع یا تحت ہوتے ہیں۔ پھر یہ نظریہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک معقول فرد اپنی فطری رضا مندی کا کیوں اظہار کرے گا یا سیاسی نظام کے فوائد کے حصول کے لیے اپنی آزادی سے کیوں دستبردار ہوگا۔
فرانسسکو سواریز اور ہوگوگروشئیش کو غالباً معاہدۂ عمرانی کے ابتدائی قائلین میں سے سمجھا گیا ہے۔ اس نے فطری قانون کے بارے میں اپنا نظریہ مطلق العنان بادشاہ کے آسمانی حقوق کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پیش کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہر کوئی فطری طور پر کسی حکومت کی اطاعت سے مبرا ہے اور یہ کہ عوام Sui juris (اپنی ذاتی عملداری) میں ہیں اور بطور بنی نوع انسان حقوق رکھتے ہیں۔
ٹامس ہابز نے اپنی کتاب Leviathan میں کہا کہ حالت فطرت میں افراد کی زندگیاں الگ تھلگ، ناقص، ناگوار، وحشیانہ اور مختصر ہوتی تھیں۔ ان کی ایسی حالت تھی جس میں ذاتی مفاد اور ناپیدگی حقوق و معاہدات کی وجہ سے باہمی روابط یا معاشرت وجود میں آنا ممکن نہیں تھی۔ زندگی نراجیت (anarchic) سے عبارت تھی (بغیر قائد یا تصورِ حاکمیت کے تھی)۔ اس حالت فطرت میں افراد غیر سیاسی اور غیر معاشرتی تھے۔ اس حالت فطرت کے پیچھے پیچھے معاہدۂ عمرانی آ گیا۔ یہ معاہدہ ایک ایسا وقوعہ تھا جس کے دوران افراد اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنے بعض انفرادی حقوق ترک کر دیئے تا کہ دوسرے بھی اپنے ایسے حقوق ترک کر دیں۔ اس کے نتیجے میں ریاست قائم ہو گئی جو ایک مطلق العنان (sovereign entity) وجود رکھتی تھی جس نے سماجی روابط کو باضابطہ بنانے کے لیے قانون تخلیق کرنا تھے۔ اس طرح انسانی زندگی، سب کی سب کے خلاف جنگ نہ رہی۔
جان لاک نے اپنے دوسرے مقالۂ حکومت (Second Treatise of Government) میں اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ حالت فطرت میں لوگ لازماً پابند اخلاق ہوں گے۔ اپنی زندگیوں یا املاک کی خاطر ایک دوسرے کو ضرر نہیں پہنچا تے ہوں گے۔ لیکن حکومت کی موجودگی کے بغیر ان کے پاس زخمی کیے جانے، غلامی سے بچنے اور اپنے حقوق کے تحفظ کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ انہیں خوف زدگی کی زندگی بسر کرنی پڑتی تھی۔ جان لاک نے دلیل دی کہ افراد کو ایک ایسی ریاست کی تشکیل پر رضا مند ہونا پڑتا تھا جو ان کی زندگیوں، ان کی آزادی اور وہاں آباد لوگوں کی املاک کے تحفظ کے لیے ایک غیر جانبدار جج مہیا کرتی۔ اس نے مزید کہا کہ حکومت کے وجود کاجواز شہریوں کی طر ف سے اس اقدام میں سے نکلتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی دفاع کا حق حکومت کو تفویض کر دیتے ہیں۔ اس کے نظرئیے کے مطابق حکومت اپنے اختیارات عوام کی منشا میں سے اخذ کرتی ہے (عوام نے اپنے جو اختیارات حکومت کو تفویض کر دیئے ہوتے ہیں، وہی حکومت کے وجود کا جواز بن جاتے ہیں)۔
ژان ژاک روسو نے اپنی کتاب معاہدۂ عمرانی میں آزادی کا خاکہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ آزادی صرف اسی وقت ممکن ہے جب عوام کی براہ راست حکومت ہو۔ وہ پوری قانون سازی کر سکتے ہوں۔ جہاں عوامی حاکمیتِ اعلیٰ نا قابلِ تقسیم اور نا قابلِ منتقلی ہو۔ اس کی اشتمالیت (collectivism) اس کے بصیرت افروز تصورِ منشائے عمومی (General Will) میں بھرپور طور پر واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی شہری مغرور و متکبر بنتے ہوئے اپنے حقیقی مفاد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اسے اس قانون کی اطاعت کا رویہ اپنانا ہوگا جوشہریوں نے بحیثیت قوم اجتماعی طور پر بنایا تھا۔ اس طرح قانون انفرادی آزادی کو محدود نہیں کرتا بلکہ یہ آزادی کا مظہر ہوتا ہے۔
چارلس لوئی ڈی مونٹیسکیو نے اپنی کتاب The Spirit of the Laws میں مقننہ (مجلس قانون ساز)، انتظامیہ اور عدلیہ کے مابین تقسیم اختیارات کانظریہ پیش کیا تا کہ تمام اختیارات ایک ہی بادشاہ یا کسی حکمران کے ہاتھ میں بے جا طور پر مرتکز نہ ہوں۔ اس طرح اس نے تحدید و توازن (checks and balances) کے نظام کی پرزور وکالت کی جس کا دنیا کے متعدد دساتیر میں اہتمام کیا گیا ہے۔
انقلاب فرانس (1789ء – 1799ء) نے بادشاہت کا تختہ الٹ دیا اور ان آزادانہ اور انقلابی نظریات سے سرشار ہو کر ایک جمہوریہ قائم کر دی۔ اس انقلاب کو تاریخ انسانی کے اہم ترین واقعات میں سے شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے جدید تاریخ کے دھارے پر بے پناہ اثرات مرتب کیے تھے۔ انقلاب فرانس نے جاگیردارانہ نظام پر کاری ضرب لگائی جس کی وجہ سے فرد کو آزادی ملی۔ غیر منقولہ جائیداد کی بڑے پیمانے پر تقسیم عمل میں آئی۔ بالائی طبقے میں جنم لینے (اشرافیہ) کی بنا پر ملنے والی مراعات منسوخ ہوئیں اور مساوات عمل میں آ گئی۔ بعد میں چلنے والی تقریباً تمام تحریکیں انقلاب فرانس کو اپنے لیے روشنی کا مینار سمجھتی رہیں۔ اس کے مرکزی نعرے Liberte, Egalite and Fraternite(آزادی، مساوات اور اخوت) جدید تاریخ کے بڑے بڑے بحرانوں کے دوران (ازمنہ وسطیٰ میں بجائے جانے والے) طُرّم (clarion call) کی آواز بن گئے۔ ان سے 1917ء کے انقلابِ روس نے بھی جوش اور ولولہ حاصل کیا۔
عالمی سطح پر انقلاب فرانس نے جمہوری مملکتوں کے ظہور کی رفتار تیز تر کر دی۔ یہ تمام جدید سیاسی نظریات کے ارتقاء کے لیے نقطۂ ماسکہ ( focal point) بن گیا۔ جس نے دیگر نظریات کے علاوہ لوگوں کو کشادہ دلی (Liberalism)، انقلابیت (Radicalism)، قومیت (Nationalism)، اشتراکیت (Socialism)، مساواتِ زن و مرد (Feminism) اور مذہب و ریاست کی علیحدگی (Secularism) کی اشاعت و تبلیغ کی راہ پر گامزن کر دیا۔ اس انقلاب سے متعلقہ دستاویزات میں اعلانِ حقوقِ انسان (Declaration of the Rights of Man) کی دستاویز بھی نہایت اہم ثابت ہوئی جس نے حقوق انسانیت کے میدان کو وسیع تر کرکے اس میں عورتوں اور غلاموں کو بھی شامل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں اگلی صدی میں انسدادیت (Abolitionism) اور عالمگیر حق رائے دہی (universal suffrage) کی تحریکوں کو زبردست تقویت ملی۔
اس ذہنی پس منظر نے آزاد خیالی پر مبنی جمہوریت (liberal democracy)، دستوریت (constitutionalism) اورقانون کی حکمرانی کے تصورات کی طرف رہنمائی کی۔ لبرل ڈیموکریسی ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں ایک نمائندہ حکومت لبرل ازم کے ایسے اصولوں کے تحت کام کرتی ہے جن میں مختلف او ر قابل شناخت سیاسی پارٹیوں کے مابین منصفانہ، آزادانہ اور مبنی بر مقابلہ انتخابات (الیکشن) ہوں۔ حکومت کے مختلف شعبوں کے مابین اختیارات کی تقسیم ہو۔ روزمرہ کی زندگی میں ایک کھلے معاشرے کے طور پر قانون کی حکمرانی ہو۔ انسانی حقوق کا مساویانہ تحفظ ہو۔ سب کے لیے شہری حقوق، شہری آزادیاں اور سیاسی آزادیاں ہوں۔ آزادی پسند جمہوریتیں اختیارات حکومت کے تعین کے لیے دستور پر انحصار کرتیں اور معاہدہ عمرانی کے تقدس کو ملحوظ رکھتی ہیں۔ آزاد خیالی پر مبنی جمہوریت بیسویں صدی عیسوی کے دوران مسلسل نشوونما پاتی رہی۔ اس طرح دنیا کا ایک غالب سیاسی نظام بن گئی۔
قانون کی حکمرانی ایک اصول ہے۔ قوم کو اس اصول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ قوم سرکاری حکام کے من پسند فیصلوں کی اطاعت کرنا شروع کر دے۔ یہ اصول ابتداء میں معاشرے کے اندر قانون کو حاکمِ مجاز (authority) ماننے کا ایک حوالہ دیتا ہے۔ یہ خاص طور پر روئیے پر ایک قدغن ہوتا ہے جس میں حکومت کا رویہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اس اصطلاح کو البرٹ وین ڈائسی نے مقبولیت عامہ دلوائی تھی اگرچہ اس کا سراغ ارسطو کے افکار میں تلاش کیا جاسکتا ہے جس نے لکھا تھا کہ قانون کوحکمران ہونا چاہیے۔ قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص بشمول قانون سازی کرنے والوں کے، قانون کا تابع ہے۔
1610ء میں برطانونی پارلیمنٹ کے دارالعوام (House of Commons) نے شاہِ انگلستان جیمز اول کو ایک خط بھیجا جس میں کہا گیا تھا کہ ہزمیجسٹی ( His Majesty) کی رعایا حکمرانی قانون سے رہنمائی پاتی ہے اور وہ اسی کے تابع ہیں جو سربراہ اور ارکان دونوں کو بتاتا ہے کہ کون سا حق ان سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ وہ کسی غیر یقینی یا آمرانہ شکل کی حکومت کے تابع اور اس سے ہدایت و رہنمائی پاتے ہیں۔ 1607ء میں چیف جسٹس سرایڈورڈ کوک نے کہا کہ قانون ایک سنہری اصول اورذریعہ ہے جو رعایا کے مقدمات کے فیصلے صادر کر سکتا ہے اور وہی ہزمیجسٹی کو سلامتی اور امن عطا کرتا ہے۔ اس بات پر بادشاہ بہت ناراض ہوا اور بولا پھر اُسے اس قانون کا تابع ہونا چاہیے جس کی توثیق کرنا غداری ہے۔ ایڈورڈ کوک نے ایک سابقہ قانون دان ہنری بریکٹن کے الفاظ میں کہا:
Quod rex non debed esse sub homine sed sub Deo et lege
(بادشاہ کو کسی انسان کے تابع نہیں ہونا چاہیے بلکہ خدا اور قانون کا تابع ہونا چاہیے)
اس سیاسی سیاق و سباق میں دستوریت (constitutionalism) کے معنی ایک مجموعۂ تصورات (complex of ideas)، رجحانات اور طرز ہائے عمل (patterns of behavior) ہے جو اس اصول کا مظہر ہوتا ہے کہ حکومت کا اختیار ایک مجموعۂ بنیادی قوانین سے ماخوذ اور اسی کے اندر محدود ہے۔ ایک سیاسی تنظیم اس حد تک حسب دستورہے جہاں تک اس کے اندر شہریوں کے مفادات اور ان کی آزادیاں، بشمول اس میں موجود اقلیت کے حقوق کے تحفظ کے لیے اداراتی میکانیاتِ تحفظ اقتدار (Institutional mechanisms of power control) پائی جاتی ہوں۔(Controlling the State by Gordon Scott, p. 4)
اس سیاسی فکر کے ظہور کے نتیجے میں مغرب نے حقوق اللہ، رشتہ داریوں اور مذہبی حکومتوں کے سیاسی ہدایت ناموں کا مکمل طور پر قلع قمع کرکے رکھ دیا اور ان کی جگہ مسلسل انتخابات اور تحدید و توازن کے لیے شعبہ ہائے ریاست کے مابین تقسیم اختیارات، عدلیہ کی آزادی، دستوریت اورقانون کی حکمرانی کے اصولوں پر استوار، نمائندہ جمہوریتیں قائم کر لیں۔ آج کا مغربی سیاسی نظام جمہوریت، عدلیہ کی آزادی، حقوق انسانی کے احترام، فلاحی ریاست اور سیکولرازم کی مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہے جہاں اصل میں لوگوں کی اپنی حکومت ہے جس کا مقصد صرف اور صرف عوام کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ خوشحال بناتا ہے۔
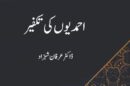



















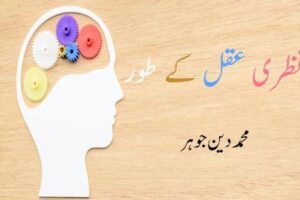
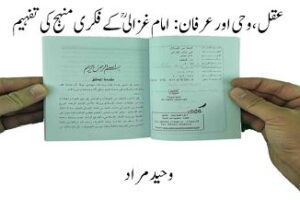
کمنت کیجے