
وحید مراد
تعلیم، صرف ریاست کے مفادات کی خادم ہے یا انسان کے شعور کی معمار بھی؟
بحرانِ تعلیم، نظام کا ہے یا فکر کا؟
چند روز قبل محمد دین جوہر صاحب نے اپنی ایک پوسٹ میں فرمایا کہ ” تعلیم عامہ اصلاً جدید ریاست کا فعل ہے(Education is primarily a political decision)۔تعلیم عامہ اپنی کلیات سے جزیات تک جدید ریاست کی متعین کردہ ہے اور اسی کے طے کردہ legal regime کے اندر کام کرتی ہے اور اس عمل کے لیے سرمایہ بھی وہی فراہم کرتی ہے۔ اگر ریاست براہِ راست سرمایہ کاری سے تعلیم کو کنٹرول نہ کرے تو بھی اپنے قانونی فریم ورک سے اس کا مکمل کنٹرول اپنے پاس رکھتی ہے۔ لہٰذا، تعلیمِ عامہ کوئی تبلیغی یا خانقاہی منصوبہ نہیں ہے بلکہ جدید قانونی، معاشی، ثقافتی اور علمی مؤثرات کو استعمال کرتے ہوئے طاقت اور سرمائے کی ترجیحات پر ایک بالکل نئے انسان کی (mass procuction) ہے۔
اگر مذہب اور مذہبی تعلیم کو بھی تعلیم عامہ کے سانچے میں سمو دیا جائے اور اسی کی شرائط پر ڈھال دیا جائے تو اس میں بھی کوئی اخلاقی اور روحانی محتویٰ باقی نہیں رہتا اور بظاہر مذہبی رہتے ہوئے اصلاً یہ بھی ایک طرح کی سیکولر تعلیم بن جاتی ہے۔ اجتماعی سطح پر طاقت کی ہیئت کو سیاست شرعیہ کے مطابق بنائے بغیر اگر شریعت کو ریاست کا قانون بنا دیا جائے تو مذہب غالب سیاسی قوتوں کا آلۂ کار بن جاتا ہے۔ بعینہٖ، مذہبی تعلیم کو تعلیم عامہ بنانے سے سماجی سطح پر مذہب کی حیثیت بھی آلاتی ہو جاتی ہے۔”
محمد دین جوہر صاحب ( Mohammad Din Jauhar ) نہ صرف ایک صاحبِ علم شخصیت ہیں بلکہ ہمارے لیے استاد اور فکری رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں فکری گہرائی، زبان میں وقار اور اسلوب میں دلکشی پائی جاتی ہے۔ تاہم ان کے طرزِ مکالمہ میں ایک پہلو قابلِ غور ہے کہ وہ اکثر اپنی پوسٹس پر ہونے والے تبصروں یا سوالات پر گفتگو نہیں فرماتے۔ یہ طرزِ عمل علمی مکالمے کے فروغ میں رکاوٹ بنتا ہے کیونکہ جب فکر سوال اور تنقید سے محروم ہو جائے تو وہ مکالمہ نہیں رہتی، بیانیہ بن جاتی ہے۔ اور بیانیہ تو ریاستوں یا اداروں کا ہوتا ہے، اہلِ علم کا نہیں۔ علم ہمیشہ سوال سے جنم لیتا ہے اور سوال ہی مکالمے کو آگے بڑھاتا ہے۔ استاد کے در پر اگر سوال کی گنجائش ختم ہو جائے تو علم کا ارتقاء کیسے ہوگا؟
ایک اور پہلو یہ ہے کہ ان کے نقطۂ نظر کو مزید واضح انداز میں سامنے آنا چاہیے۔ وہ کن مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ ان کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اور ان کے ممکنہ حل کی سمت کیا ہو سکتی ہے؟ ان کی اکثر تحریریں ان سوالات کو ابھارتی ضرور ہیں مگر ان کے جوابات فراہم نہیں کرتیں۔ قاری جب فکری ابہام کے ساتھ متن سے باہر نکلتا ہے تو مکالمہ ادھورا رہ جاتا ہے۔
حالیہ تحریر میں یہ واضح نہیں کہ علم کی سماجی تنظیم کس بنیاد پر قائم ہوگی؟ اگر تعلیم کو انڈسٹری کے بجائے سماجی خدمت بنایا جائے تو اس کا معاشی ماڈل کیا ہوگا؟ کیا تعلیم ریاست کے بغیر بھی مؤثر رہ سکتی ہے؟ حقیقی تعلیم کی اخلاقی اور روحانی تشکیل کس طرح ممکن ہے؟ اور کیا موجودہ نظامِ تعلیم صرف ریاستی کنٹرول کا نتیجہ ہے یا انسانی سماج کے فطری ارتقاء کا حصہ؟
یہ بات درست ہے کہ تعلیم ریاستی اور سیاسی فیصلوں سے متاثر ہوتی ہے مگر اسے صرف “ریاستی آلہ” قرار دینا اس کے وسیع تر سماجی و تہذیبی پہلو کو محدود کر دیتا ہے۔ تعلیم صرف قانون یا سرمایہ نہیں یہ سماجی شعور، ثقافتی اظہار اور انسانی ارتقاء کا عمل بھی ہے۔ ریاست اس کا نظم فراہم کر تی ہے مگر علم کی تخلیق انسان کے باطن سے جنم لیتی ہے اور انسانی سوال کسی سیاسی فیصلے کا تابع نہیں ہو سکتا۔
طاقت کے زاویے سے یہ تجزیہ اپنی جگہ درست ہے مگر اس میں تعلیم کے مثبت پہلو مثلاً مقصد، اخلاق، تخلیق اور حریت فکر کی وضاحت نہیں کی گئی۔ تعلیم عامہ کا اصل ہدف کیا ہے؟ کیا یہ انسان کو آزاد کرتی ہے یا محض نظم و ضبط کے تابع رکھتی ہے؟ کیا تعلیم عامہ ریاست کی خدمت کے لیے ہے یا انسان کی تکمیل کے لیے؟ اسی طرح تحریر میں یہ بھی بیان نہیں کیا گیا کہ جدید تعلیم اپنے موجودہ مقام تک کیسے پہنچی؟ یہ دراصل ایک طویل تاریخی و تہذیبی ارتقاء تھا جس میں صنعتی انقلاب، سائنسی شعور اور معاشی تبدیلیوں نے کردار ادا کیا۔ ریاست نے تعلیم کو ایجاد نہیں کیا بلکہ اسے ایک منظم اور نگران ادارے کی شکل دی۔ جب یہ تاریخی فرق واضح نہ کیا جائے تو تجزیہ فکری طور پر نامکمل رہ جاتا ہے۔
موجودہ نظامِ تعلیم کو “آلاتی، ریاستی یا سیکولر” کہہ کر مسترد تو کیا جا سکتا ہے مگر اس کے بعد پیدا ہونے والے فکری خلا کو پر کرنے کے لیے متبادل کی کوئی واضح صورت پیش کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ریاستی نظامِ تعلیم ناقص ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کی جگہ کون سا ڈھانچہ لایا جائے؟ کیا تعلیم کو ریاست کے دائرۂ اثر سے بالکل آزاد کر دینا ممکن یا مطلوب ہے؟ یا پھر ایسا راستہ اپنانا چاہیے جس میں ریاستی نظم کے ساتھ فکری خودمختاری و روحانی توازن بھی برقرار رہے اور علم اپنی روح میں آزاد مگر نظم میں اجتماعی رہے؟
یہ سوالات صرف تعلیمی نہیں بلکہ تمدنی اور وجودی بھی ہیں۔ انسان کی تربیت محض نصاب یا ڈھانچے سے نہیں بلکہ اس کے اندر کی اخلاقی و فکری قوتوں سے وابستہ ہے۔ اگر تعلیم کو صرف طاقت کے آلے کے طور پر دیکھا جائے تو وہ اپنی روح کھو دیتی ہے جو علم کو بصیرت میں بدلتی ہے۔ تعلیم اگر انسان کی داخلی ساخت کو متاثر نہ کرے تو وہ محض معلومات کی منتقلی رہ جاتی ہے اور یوں آہستہ آہستہ رٹّا سسٹم یا ذہنی غلامی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ مگر دوسری طرف، اگر تعلیم کو ریاست سے مکمل طور پر جدا کر دیا جائے تو اس کی اجتماعی سمت بکھرسکتی ہے اور معاشرہ فکری انتشار کا شکار بھی ہوسکتا ہے۔
فلسفۂ تعلیم کی تاریخ میں ہمیشہ یہ سوال موجود رہا ہے کہ تعلیم کا مقصد “جاننا”ہے یا “ہونا(becoming)‘‘؟جاننا معلومات کے حصول کا عمل ہے جبکہ ہونا انسان کے باطن میں اس علم کے سرایت کر جانے، کردار، شعور اور وجود کی تشکیل کا نام ہے۔جدید دنیا نے صرف جاننے کو کافی سمجھا اور علم سے اپنی ذات کی تعمیر اور اپنے وجود کی گہرائی تک پہنچنے کے عمل کو کم اہم سمجھا۔اسی لیے آج کا تعلیم یافتہ انسان زیادہ باخبر تو ہے مگر کم باشعور؛ اس کے علم میں وسعت تو آئی مگر اس کے ہونے میں وہ گہرائی پیدا نہ ہو سکی جو علم کو تجربے اور تجربے کو بصیرت میں بدلتی ہے۔
مسئلہ شاید نظام کا کم اور نظامِ فکر کا زیادہ ہے۔ چاہے تعلیم کے ادارے ریاست کے ہوں یا غیر ریاستی، جب تک وہ انسان کو محض پیداوار یاسرمایہ سمجھتے رہیں گے، تعلیم ایک میکانکی عمل ہی رہے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم کے اندر ایک ایسا فکری محور تلاش کیا جائے جو انسان کو عقل ہی نہیں بلکہ وجدان کی سطح پر بھی آزاد کرے۔
اہم سوال یہ نہیں کہ تعلیم کس کے ماتحت ہو ، ریاست کے، مذہب کے یا فرد کے بلکہ یہ ہے کہ علم کا مقصد کیا ہو؟ کیا تعلیم محض شہری نظم کی بقا کے لیے ہے یا انسان کی اندرونی تکمیل کے لیے؟ جب تک یہ سوال واضح نہیں ہوگا، ہر نظامِ تعلیم خواہ سیکولر ہو یا مذہبی طاقت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ، آلاتی علم ہی رہے گا، جو انسان کو بہتر نہیں بلکہ زیادہ کارآمد بنانے میں مصروف ہے۔
نئے تعلیمی ڈھانچوں سے زیادہ ضرورت ایک نئی تعلیمی فکر کی ہے ایسی فکر جو یہ احساس پیدا کرے کہ علم کی تحصیل طاقت یا سرمایہ نہیں بلکہ معنی اور مقصد کے لیے ہے۔ تعلیم محض معاشی عمل نہیں بلکہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ جب تک علم سے یہ اخلاقی رشتہ بحال نہیں ہوگا، کوئی بھی تعلیمی اصلاح خواہ مذہبی ہو یا سیکولر اندر سے بانجھ ہی رہے گی۔
یہ تمام گفتگو بالآخر چند اہم فکری سوالات اٹھاتی ہے ۔ یہ سوالات صرف ریاست اور تعلیم کے باہمی تعلق کے نہیں بلکہ انسان، علم، شعور، مذہب ، ریاست اور تہذیب کے باطن میں پوشیدہ رشتوں کی معنویت کے ہیں۔ مثلاً اگر تعلیم ریاستی سانچے سے آزاد ہو جائے تو کیا وہ اپنی اخلاقی و روحانی سمت برقرار رکھ سکے گی؟کیا ریاست کے بغیر تعلیم کا نظم و ضبط بکھر نہیں جائے گا؟یا مسئلہ ریاست کا نہیں، بلکہ تعلیم کے اصل مقاصد اور اس کی تہذیبی بنیادوں کی گمشدگی کا ہے؟کیا جدید ریاست کو محض طاقت و سرمائے کا آلہ سمجھنا درست ہے یا وہ انسانی تجربے کے ایک طویل ارتقائی سفر کی منطقی صورت ہے؟کیا مذہب اگر ریاست یا تعلیم کے اداروں میں شامل ہو جائے تو اپنی روح کھو دیتا ہے یا وہ اخلاقی توازن اور انسانی ضمیر کی صورت میں ان اداروں کو معنویت بخشتا ہے؟کیا اسلام کی روح جدید ریاست کے ڈھانچے میں جذب ہو سکتی ہے یا ہمیں ہر نئے تجربے کو “شرعی” اور “غیر شرعی”خانوں میں بانٹ کر فکری جمود میں رہنا ہے؟اور آخر وہ کون سا فکری و اخلاقی فریم ورک ہے جو تعلیم، ریاست اور مذہب تینوں کو باہم ہم آہنگ کر کے انسان اور سماج دونوں میں توازن پیدا کر سکتا ہے؟یہ وہ سوالات ہیں جن کے بغیر نہ تعلیم کی نئی تعبیر ممکن ہے نہ ریاست کی نئی تفہیم اور یہی وہ سوالات ہیں جن پر گفتگو ضروری ہے۔
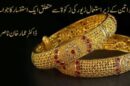
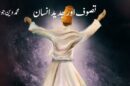
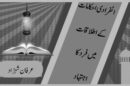
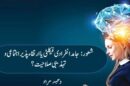


















کمنت کیجے