”تعلیم، ریاست اور انسان: ایک جائزہ“ کے عنوان سے اپنے مضمون کی دوسری قسط میں جناب وحید مراد نے کچھ مغربی فلاسفہ کے حوالے دیے ہیں لیکن وہ شاید ان کے اقوال کی معنویت پر غور نہیں کر سکے۔ انھوں نے فوکو، بوردیو، گرامشی اور ڈیوی کے جو حوالے نقل کیے ہیں وہ میری گزارشات کو ہی مؤید کرتے ہیں، اور ان کے ارشادات کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہنے دیتے۔ لیکن وہ پھر بھی وہ فرماتے ہیں کہ ”تاہم، تعلیم صرف ریاستی میکانزم نہیں بلکہ ایک تہذیبی عمل بھی ہے۔ ہر تہذیب تعلیم کے ذریعے اپنے اخلاقی، فکری اور روحانی تصورات کو نسل در نسل منتقل کرتی ہے۔ جب تعلیم ریاستی ضرورت کے تابع ہو جاتی ہے تو تہذیب کا روحانی مواد زائل ہو جاتا ہے۔ یوں علم “معرفت” سے جدا ہو کر صرف “مہارت” بن جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں رٹّا کلچر جنم لیتا ہے، سیکھنے کا مقصد سمجھنا نہیں بلکہ دہرانا ہوتا ہے اور تعلیم کا ہدف انسان نہیں بلکہ کارکردگی رہ جاتی ہے۔“
چند مغربی فلاسفہ سے استشہاد کے بعد، وہ ”تاہم“ اور ”جب“ پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہیں۔ شاید اس لیے کہ ”اب“ جو کچھ ہے وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہے۔ میں حیران ہوں کہ وہ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ ”جب تعلیم ریاستی ضرورت کے تابع ہو جاتی ہے“ اور یہ دیکھنے سے کیوں منکر ہیں کہ تعلیم عامہ مکمل طور پر جدید ریاست کا ہی فیصلہ ہے اور اس کے تمام پہلو اس فیصلے کے براہِ راست نتائج ہی ہیں۔ وہ جدید ریاست کے جبڑوں میں ”تہذیب کے روحانی مواد“ کے زائل ہو جانے پر فکرمند ہیں، لیکن وہ یہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ کہیں یہ واقعہ ہو تو نہیں چکا یا اس کے ایک واقعہ بن جانے کا اندیشہ کس قدر حقیقی ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنی شسکت خوردہ داخلیت میں اس قدر غرق ہو گئے ہیں کہ شعور و عمل میں کسی معروض اور ایجنسی سے ہمارا کوئی سروکار ہی نہیں رہا۔
اگر جناب وحید مراد بنیادی سوال پر کوئی موقف اختیار کر لیں تو ہی گفتگو بامعنی ہو سکتی ہے۔ تعلیم عامہ کے محیط میں سیکھنے اور سکھانے کے کل پہلو جدید ریاست کے اختیار اور فیصلے سے طے ہوتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں حکومتِ پنجاب نے ایک مراسلہ جاری کیا تھا کہ بچوں کو تجزیاتی تعقل ( analytical reasoning) اور تنقیدی خوض (critical thinking) سکھایا جائے۔ اور ریاست ایسا حکم دینے کی مجاز اس لیے ہے کہ تعلیم عامہ جس legal regime میں کام کرتی ہے اس میں سیکھنے سکھانے، کرنے کرانے، سوچنے سوچوانے کے کل اعمال کا تعین وہی کرتی ہے۔ میں اچھے برے کی تو بات ہی نہیں کر رہا، اور نہ باید کا مسئلہ چھیڑ رہا ہوں کیونکہ ابھی تو ہست ہی کا پتہ نہیں چل رہا کہ ہم زمین پر ہیں یا آسمان میں، ہم خواب میں ہیں کہ جاگے ہوئے ہیں، غلام ہیں کہ آزاد ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں یا نہیں، بول بھی سکتے ہیں یا ہمارا نصیب صرف بڑبڑانا ہی ہے، اور سوچنا ہے تو کیا سوچنا ہے۔ جدید تاریخ نے فرد، معاشرے اور تاریخ کی سطح پر ہمارے لیے جو بھی مسائل کھڑے کیے ہیں ان میں سے کسی کو بھی ہم اپنی سوچ کا موضوع نہیں بنا سکے ہیں۔ فی زمانہ ہم تاریخ کے جس گھیرے میں آ چکے ہیں اس سے نکلنے کا اب شاید امکان بھی باقی نہیں رہا۔ اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ ہمارے اندر ہے اور ہم خود ہی ذمہ دار ہیں۔ ہم نے جیسا سوچا اور کیا تھا اب اس کے نتائج کا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد ملت اسلامیہ کو سوچنے کے لیے نصف صدی سے زیادہ کا وقت ملا تھا۔ اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے اور تاریخ کی موجودہ کروٹ میں ہمارے پاس کہنے اور کرنے کو کچھ نہیں۔ ہمارے علم و عمل کی ایجنسی کا کوئی نشان بھی کہیں باقی نہیں رہا، اور دنیا بھر کے مسلم معاشرے اب اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جو اب نوشتۂ دیوار ہے۔ اس وقت واحد حل اپنی تہذیبی ذمہ داری کا ادراک کرنے اور اسے ادا کرنے کی تیاری ہے۔
گزارش ہے کہ ہر علمی گفتگو، ہر فکری سراغ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اصول کی پیروی میں رواں ہوتا ہے، اور اصول کا پہلا کام ہی یہ ہے کہ وہ حصر قائم کر دیتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ تعلیم عامہ کیا ہوتی ہے؟ اور یہ سوال لٹ پٹ گیا۔ اس لیے اس سے بھی بنیادی سوال کی طرف لوٹنے کی ضرورت پڑی کہ کیا تعلیم عامہ نام کی کوئی شے ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ لیکن مجھے شبہ ہے کہ اس پر بھی گفتگو شاید ممکن نہیں ہو گی۔ تعلیم عامہ کے سرکاری محکمے اور نجی ادارے قائم ہیں، ان کا بجٹ اربوں میں ہے، لاکھوں لوگ تعلیم عامہ کے کام کی تنخواہ لیتے ہیں، کروڑوں لوگ اس اجتماعی عمل میں شریک ہیں۔ اور ہر اجتماعی عمل کی طرح تعلیم عامہ بھی نتیجہ خیز ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ تعلیم عامہ کے قائم کردہ نظام کا ایک ذراتی جز کلاس روم ہے جہاں تیس بچے بیٹھے رٹا لگا رہے ہیں۔ لیکن جس بہتے دریا کا یہ فیض ان تک پہنچ رہا ہے وہ نظر نہیں آتا اور نہ آ سکتا ہے، لیکن معجزہ یہ ہے کہ رٹا نظر آتا ہے۔ ہست کا کوئی ادراک ہو تو آدمی جز اور کل کی بحث چھیڑے، اور جب ہست ہی نہیں ہے تو کیا جز اور کیا کل۔ جس طرح ہم تعلیم عامہ کو سمجھے ہیں اسی طرح ہم داخلی اور عالمی طاقت اور سرمائے کے نظام کو سمجھتے ہیں۔ ہمارا تہذیبی اور علمی شعور ایسی ہی حرکیات میں ڈھلا ہوا ہے اور اسی میں رہ کر کام کرتا ہے۔ علم کی اول ذمہ داری چیزیں جیسی ہیں ان کو ویسے دیکھنا اور سمجھنا ہے، اور یہی ہست کا مقصود ہے۔ ہماری علمی کارگزاری ابھی شرطیہ اور تمنائی کی گھمن گھیری سے آگے نہیں نکل پائی، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا شعور انفس و آفاق سے مکمل طور پر منقطع ہو چکا ہے۔ اس لیے جناب وحید مراد کی رٹے پر گفتگو اور میری تعلیم عامہ پر گزارشات یکساں بے معنی ہیں۔ اب تو لگتا ہے کہ ہمارا کتابیں پڑھنا بھی بے سود ہے کیونکہ ہمارا شعور بین الدفتینی ملفوظات کو ہی معروض سمجھ بیٹھا ہے۔ علم اگر سے مگر تک کا سفر نہیں ہے بلکہ علم کا ہر خواب نگر ہست و باید کی جدلیات کے لہو رنگ راستوں سے گزر کر دکھائی پڑتا ہے۔ مسلم شعور تاریخ سے مکمل ریٹائرمنٹ پر قانع ہو چکا ہے، اور اب تو لگتا ہے کہ پنشن بھی بند ہونے والی ہے۔
جناب وحید مراد ابھی تک اگر سے ہی دامن نہیں چھڑا پا رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ”اگر ریاست تعلیم کو مکمل طور پر کنٹرول کرے تو آزادی اور تخلیق دم توڑ دیتی ہے اور اگر وہ اسے مکمل طور پر آزاد چھوڑ دے تو طاقتور طبقات اس پر قابض ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا مسئلہ ریاستی مداخلت کے ہونے یا نہ ہونے کا نہیں بلکہ ریاست کے فکری کردار کا ہے۔ ریاست کو کنٹرول نہیں بلکہ سرپرستی اور رہنمائی کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ فریم ورک مہیا کرے مگر اس کے اندر تجربہ، تنقید، جستجو اور تنوع کی آزادی باقی رہنی چاہیے۔
”تعلیم ریاست کا فعل اور فیصلہ ہے” درست بات ہے مگر حقیقت میں تعلیم انسان کا فیصلہ ہے۔ ریاست فریم ورک فراہم کر سکتی ہے، مگر روح نہیں۔ یہ روح تب ہی پیدا ہوتی ہے جب علم و اخلاق، نصاب و تربیت، ذہانت و بصیرت ایک دوسرے سے جڑ جائیں۔ جب تک تعلیم نوکری کے ساتھ خود آگاہی کا عمل نہیں بنتی، تب تک ریاستیں بدلیں یا نظام، مگر انسان نہیں بدلے گا۔“
ممدوح محترم کی پوری تحریر میں ambivalence بطور فکر موجود ہے جو تہذیبی سطح کی cognitive dissonance سے پیدا ہوتی ہے۔ جو مختلف سوالات اور مواقف بیان کیے جا رہے ہیں وہ عین اسی موقف کی توسیط کا ذریعہ ہیں۔ ان سوالات پر کوئی فیصلہ کرنا مقصود نہیں ہے، اور نہ ان کا کسی معروض سے تعلق قائم کرنا مطلوب ہے۔ علم شعور کے بڑے تشکیلی اور تخریبی ذرائع میں سے ہے۔ انسانی شعور اگر اپنے علمی تصورات کے نسب نامے اور تاریخی معروض سے منقطع ہو جائے تو علم ایک بہت بڑی تخریبی قوت بن جاتا ہے۔ برصغیر میں ہماری گزشتہ تین صد سالہ تکفیری فکر یہی کام کرتی ہے، اور جدید تعقلی علوم بھی اس کے سانچوں میں ڈھل گئے ہیں۔
میں نے تو اپنی تحریر میں تعلیم کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور صرف تعلیم عامہ کی واقعاتی حقیقت کو تجزیے کا موضوع بنانے کی کوشش کی ہے کیونکہ میری گزارشات کا مدار ہی تعلیم اور تعلیم عامہ کے بنیادی ترین امتیاز پر ہے۔ مجھے فی الوقت تعلیم عامہ کے ارتقا میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کوئی روح یا ڈھانچہ بھی میرا موضوع نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ میں اتنی سادہ بات کا بھی ابلاغ شاید نہیں کر پایا۔ جب وہ فرماتے ہیں کہ ”حقیقت میں تعلیم انسان کا فیصلہ ہے“ تو مجھے جھرجھری آ جاتی ہے۔ وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب جدید ریاست تعلیم عامہ کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ کسی ماورائی مخلوق کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اب میں اس ماورائی مخلوق کو نظام شمسی سے پرے کہاں ڈھونڈھتا پھروں۔ ممدوح محترم کو اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں کہ برطانوی استعمار جو فیصلہ کر چکا اور جو تقریباً دو صدیوں سے نافذ العمل ہے اور اپنے مقاصد کے حصول تامہ میں کامیاب ہو چکا ہے، وہ کیا ہے؟ براہِ استعمار ہمارے ہاں تعلیم عامہ کے قائم ہونے کا کیا معنی ہے؟ یہ عین اسی تعلیم ہی کا نتیجہ ہے کہ ہمارا علمی شعور ابتدائی درجے میں بھی اپنا کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔
جدید تعلیم عامہ ایک ”بدن“ بھی رکھتی ہے کیونکہ وہ تاریخی اور سماجی عمل کے طور پر اپنے حسی مظاہر بھی رکھتی ہے، لیکن بینائی کا کوئی قرینہ اسے دیکھ نہیں پاتا۔ لیکن ہمیں اپنی علمی دراکی کا پورا یقین ہے کیونکہ وہ اچانک سے کوئی روح وغیرہ دیکھ لیتی ہے۔ آدمی اگر خلائی روحوں کے پیچھے چل پڑے تو تاریخ کی بدروحیں نظر نہیں آتیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ بدن اس قدر دریدہ ہے کہ ہم اسے دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے۔ جو چیز مشاہداتی اور تجربی ہے اس کے مسائل کو جاننے اور حل کرنے کی استعداد تو بہم نہ کر پائے، اور روح کو تلاش کرنے اور بچانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر بیٹھ کر کچھ غور کرنے کا ہنر جان لیتے تو شاید بہتر ہوتا۔
محترم مصنف فرماتے ہیں کہ ”تعلیم کو محض ریاستی فیصلہ کہنا انسانی تاریخ کے ارتقائی عمل کو نظر انداز کرنا ہے۔ ریاست نے ضرور تعلیم کو منظم کیا مگر وقت کے ساتھ تعلیم معاشی مواقع، سماجی مقام اور فرد کی بقا سے جڑ گئی۔ یوں تعلیم اب محض ریاستی نظم نہیں بلکہ ایک سماجی و معاشی قوت بن چکی ہے۔ جب تعلیم کا مقصد پیسہ یا مرتبہ بن جائے تو وہ اپنے اخلاقی اور روحانی جوہر سے خالی ہو جاتی ہے۔ مگر حقیقی اصلاح کا راستہ ریاست یا مارکیٹ کو رد کرنے میں نہیں بلکہ تعلیم کے روحانی و فکری پہلو کو نئے فریم ورک میں بحال کرنے میں ہے۔“
یہ پیراگراف بہت دلچسپ ہے، اور گزشتہ دو سو سال میں سامنے آنے والے ہمارے علوم کے مجموعی مزاج کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے علوم میں moralizing کا ازحد غلبہ ہے یعنی ہر وقت باید کی گفتگو چلتی رہتی ہے۔ ہمارے ممدوح محترم ابھی تک مثلاً یہ بحث کر رہے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو یہ ہو گا مگر اخلاقیات یہ کہتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ علمی ذہن کی بنیادی ذمہ داری ہست کا تجزیہ کرنے کے بعد باید کی طرف پیشرفت کرنا ہے۔ صاحبِ مضمون ابھی تک یہ ماننے سے گریزاں ہیں کہ ہماری تعلیم عامہ آج سے دو سو سال پہلے جدید استعماری ریاست کے فیصلے کے طور پر سامنے آئی تھی اور ہمارے معاشرے اور قومی ذہن کی اپنی تہذیبی شرائط پر مکمل تشکیل نو کر چکی ہے۔ ممدوح محترم استعماری تعلیم عامہ کے اس ریاستی فیصلے کو اور گزشتہ دو سو سالہ تاریخ کو ابھی تک ”اگر“ کے زمرے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے بہت ہوا تو ”مگر“ تک سفر کیا جا سکتا ہے۔ یہ میرا ”اگر“ ہے کہ ہمارے شعور اور عقلیت کے احوال یہی ہیں کہ وہ تاریخ سے بھی حالت انکار میں ہیں تو بھئی پھر کیا علمی گفتگو ہو سکتی ہے؟
وہ ”مگر“ جس کا انتظار تھا، ممدوح محترم اس کی رونمائی فرماتے ہیں کہ ”مگر حقیقی اصلاح کا راستہ ریاست یا مارکیٹ کو رد کرنے میں نہیں بلکہ تعلیم کے روحانی و فکری پہلو کو نئے فریم ورک میں بحال کرنے میں ہے۔“ ہمارے ہاں مغرب کی دو تنویری اصطلاحات یعنی ”انقلاب“ اور ”اصلاح“ کا جو حشر ہوا ہے اس کا مطالعہ بھی خاصے کی چیز ہے۔ یہ دونوں مغربی سیاسی فکر کی بنیادی اصطلاحات میں سے ہیں، اور سیاسی طاقت کے دو تصورات کو ظاہر کرتی ہیں جن میں طبائع (نیچر) کے تصورات بھی مضمر ہیں۔ ان دونوں اصطلاحات کا براہ راست تعلق سیاسی طاقت، سرمائے اور سائنسی علم سے ہے، اور یہ دونوں مذہب کی بالکل ضد میں بروئے کار لائی گئی ہیں۔ ہمارے ہاں ان دونوں اصطلاحات کو مذہبی بیلچے سمجھ لیا گیا اور بربادی کے سارے راستے انھی سے ہموار کیے گئے ہیں۔ کچھ ڈھول اٹھائے انقلاب کی طرف نکل گئے اور کچھ نے اصلاح کی ڈفلی بجانا شروع کر دی۔ ابھی تحریک تنویر کے سیاسی تصورِ اصلاح (reform) کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اچانک سے ”حقیقی اصلاح“ بھی نعرے لگاتی نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ اصطلاح بھی ہمارے ہاں ”حقیقی“ یا ”خالص“ دین کی طرح کی کوئی چیز بن جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ واقعاتی تعلیم عامہ کی حقیقت کیا ہے کہ میلے میں ”حقیقی اصلاح“ بھی آن پدھاری، اور اس کے جھولنے کے لیے ”فریم ورک“ وغیرہ کی تنصیب بھی مکمل ہو گئی ہے۔ لیکن اس میلے میں ”روحانی“ اور ”فکری“ پہلوؤں کے شاپر کہیں گم ہو گئے ہیں۔ تلاش کی افراتفری میں کسی کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ ”اخلاقی“ شاپر بھی ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال، تعلیم عامہ کے ”فریم ورک“ میں گملے کی طرح جَڑے ہوئے بچے میں ”روحانی پہلو“ کی پنیری لگانا جدید عہد کی بڑی سائسنی پیشرفت ہو گی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ذہن اب ایک طاقِ نسیاں کی طرح ہے، اور مطالعۂ کتب اس میں متن کا داخل خارج رجسٹر بن گیا ہے۔ اب رجسٹر بھرتا جا رہا ہے اور ہمارے قومی ذہن کی غبار آلودگی کم ہونے میں نہیں آ رہی۔


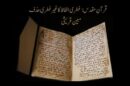















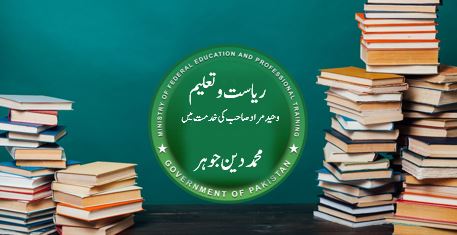



کمنت کیجے