عاصم بخشی
گوئٹے کا المیہ ناٹک فاؤسٹ[1] یوں تو بہت سے دل گرفتہ مناظر کی بُنت سے تخلیق کیا گیا ہے، لیکن گریچن کا قصہ یقیناً اس کا سب سے الم ناک منظر ہے۔ گریچن ایک ایسا معصوم، مخلص اور دلچسپ کردار ہےجو ایک چھوٹی سی محفوظ اور بند مذہبی دنیا سے نمودار ہوتا ہے۔ یہ وہی ننھی سی دنیا ہے جس میں کبھی فاؤسٹ پلا بڑھا تھا لیکن وہ کب کا اسے کھو بیٹھا ہے۔اب وہ اس کا رخ محض ایک ایسے ناظر کی حیثیت سے کرتا ہے جسے اس پر تبصرہ و تنقید مقصود ہے۔ گریچن کی کہانی بنیادی طور پر لاحاصل محبت کے کرب کی کہانی ہے۔اس کا نسوانی حسن دراصل اس روایتی دنیا کا علامتی حسن ہے جس کی بچگانہ معصومیت فاؤسٹ کے لیے بہت جذباتی کشش رکھتی ہے۔وہ میفسٹو سے لیے گئے جواہرات کے تحفے گریچن پر نچھاور کرنا چاہتا ہے ۔اسے اپنی دنیا کی جانب کھینچنا چاہتا ہے۔گریچن کے اندر ایک کشمکش برپا ہے جس کا منبع ان تبدیلیوں کے امکانات ہیں جو اپنی ننھی سی روایتی دنیا کو چھوڑ کر فاؤسٹ کی نئی دنیا میں ہجرت سے عبارت ہیں۔وہ اپنی معصومیت اور سادہ لوحی پر ماتم کناں ہے۔اپنی داخلی بغاوت پراسے ایک جذباتی شرمساری کا سامنا ہے۔ اپنے دردناک انجام سے قبل آخری منظر میں گریچن ایک زنداں میں قید ہے۔ فاؤسٹ اسے اپنے ساتھ فرار پر آمادہ کرتا ہے تو وہ اسے اس کے سرد لہجے کی دہائی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔یہ بات کافی حد تک سچ ہے کیوں کہ تجربہ وعمل کی اقلیم کا مسلسل مسافر ہونے کے ناطے فاؤسٹ کے لیے گریچن کو ساتھ گھسیٹتے رہنا ممکن نہیں۔گریچن وہیں پڑی پڑی بالآخر جان دے دیتی ہے۔
کیا مدرسہ ڈسکورسز کا فاؤسٹ اپنی روح کا سودا کر چکا ہے؟
اس منصوبے سے عملی تعلق نہ رکھنے کے باعث راقم اس منصوبے کے خدوخال اور اغراض ومقاصد کے بارے میں کوئی واضح اور حتمی رائے رکھنے سے قاصر ہے۔لہٰذا اس سوال کا جواب ان دستاویزات کی روشنی میں نظری طور پر ہی دیا جا سکتا ہے جو اس منصوبے سے منسلک دستی کتابچوں، بلاگز، مضامین اور عملی سرگرمیوں کی رپورتاژ کے ذریعے عوام کو دستیاب ہیں۔ ان معلومات کی روشنی میں دیکھا جائے توماہنامہ الشریعہ کے سابقہ شمارے میں قبلہ محمد دین جوہر صاحب کی تنقیدی کاوش اپنے اندر گریچن کی سی معصومانہ لیکن اذیت ناک خودمسماری رکھتی ہے۔ ایک ایسے یک رخی تنقیدی دھارے کا حصہ ہوتے ہوئے جو مسلسل تکرار کے باعث اب خود ایک مستقل صنف بننے کے قریب ہے، اس خودمسمار تنقیدی روایت کی سب سے دلچسپ جہت سماجی تھیوری میں’روایت‘،’تاریخیت‘ اور ’جدیدیت‘ جیسے مقولات کی دستیاب تعریفات میں سے پہلے تو من پسند چناؤ اور پھران چنیدہ تعریفات کو مقبول و معروف کہنے پر اصرار ہے۔ دراصل یہ ایک جانا مانا علتی سلسلہ ہے جس کے ذریعے چنیدہ تعریفات پھیل کر پہلے تو دوسری تمام تعریفات پر حاوی ہوتی ہیں او رپھر انہیں حاشیوں پر بھی جگہ دینے پر راضی نہیں ہوتیں۔یہ کم و بیش اسی قسم کا انتخابی تعصب (ٰselective bias) ہے جس کی معکوس صورت ہمیں کلاسیکی استشراقی منہجِ تنقید میں نظر آتی ہے۔ لہٰذا ہماری رائے میں جینیاتی اعتبار سے جوہر صاحب حریف جدیدیتوں کو جس استشراقی روایتِ فکر کا حصہ بتلا رہے ہیں ، طریقیاتی منہج میں خود اسی سے قریب تر ہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود بھی ایک ایسی تنقیدی روایت کے علم بردار ہیں جو تنقید کے ضمن میں کسی نادیدہ جزیرے پر لنگر انداز ایک ’حریف جدیدیت‘ ہی ہے۔ اس کے برعکس ڈاکٹر فضل الرحمٰن رحمہ اللہ ، ڈاکٹر ابراہیم موسیٰ اور ڈاکٹر عمار ناصر وغیرہم خالص مذہبی روایتِ فکر یعنی ’آرتھوڈوکسی‘ کے جزیرے میں جنم لے کر ایک ایسی حریف جدیدیت کے امکانات برپا کرنے نکلے ہیں جو فکری خودمسماریت پسندی کے برعکس ہماری خالص مذہبی (یعنی آرتھوڈوکس) روایت سے قریب تر ہے۔غالباً ان متقابل علمی جینیات اور ان سے منسلک ذہنی میلانات کی بنیادی وجہ آخر الذکر تحقیقی حلقے کی روایتی مذہبی علمیات سے (کسی نہ کسی درجے میں مدرسی) وابستگی اور اوّل الذکر تنقیدی حلقے کی جدیدیت مخالف مابعدالجدید تنقیدی روایت (مثلاً فرینکفرٹ مکتب ِ فکر) سے ذہنی وابستگی ہے۔
گزارش یہ ہے کہ مطالعہ و تنقید قاری کی نفسیات میں برپا رہنے والا ایک مستقل واقعہ ہے۔ لیکن خودمسماری پر مائل مایوس تنقیدی ذہن میں یہ واقعہ ایک ایسی زمانی سرنگ میں قید ہو جاتا ہے جو لمحۂ موجود اور لمحۂ آئندہ کے امکانات پر نظر نہیں رکھتی۔ اس کے برعکس لمحۂ گزشتہ کی ایک مخصوص مصنوعی تصویر ذہن کو اپنی مکمل گرفت میں رکھتی ہے۔نتیجتاً یہ خودمسمار تنقیدی ذہن خود اذیتی کے علاوہ تنقید سے کوئی ایسی لذت اٹھانے سے قاصر رہتا ہے جو تجربہ و عمل کے دنیا میں انقلاب کے امکانات رکھتی ہو۔ظاہر ہے کہ اگر گریچن کے زاویۂ نگاہ سے اُس کی محبت میں گرفتار فاؤسٹ اپنی روح کا سودا کر چکا ہے تو اس پر تنقید سے سینہ کوبی کے سوا کیا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ زنداں میں پڑی روتی سسکتی گریچن کو کیوں کر اپنی ننھی سی روایتی جنت چھوڑنے پر مائل کیا جا سکتا ہے جس کا وجود اب ذہنی بھی نہیں بلکہ صرف جذباتی خدوخال ہی رکھتا ہے؟ غالباً یہ ایک کارِ لاحاصل ہے۔ راقم گواپنی کم سوادی کے باعث خود کوحریف جدیدیتوں کے منصوبے کے خاطر خواہ دفاع، اور برادربزرگ جوہرصاحب سے مکالمے اور جواب تنقیدکا بھاری پتھر اٹھانے کے قابل نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال اپنے جیسے طلبا اور محققین کو ان سماجی مقولات کی تعریفات میں حائل پیچیدگیوں سے مختصراً آگاہ کرنا ضروری ہے جو اس منصوبے پر ہونے والی مخصوص مقامی تنقیدوں کے زیرِ اثر انہیں مقبول و معروف اور طے شدہ امور سمجھتے ہیں۔
منہجِ فکر یا طریقیاتی تناظرمیں تصورات کی بحث اپنی اساس میں لسانیات ہی کی بحث سے جنم لیتی ہے۔جدیدیت جیسے غیرمقامی سیاسی و سماجی تصورات دوسری زبانوں اور دوسرے معاشروں تک پہنچتے پہنچتے اپنی اصل سماجی اشتقاقیات سے کٹ جاتے ہیں۔ یوں ترجمہ صرف لسانی اعتبار سے ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقلی نہیں بلکہ تہذیبی اور سماجی اعتبار سے بھی اپنی اصل سے ایک فاصلے پر ہٹ جانے کا مظہر ہوتا ہے۔تنقید کے وہ نابینا طریقیاتی منہج جو مقامی تہذیبوں میں ترجمے کے بعد غیرمقامی تصورات کی چنیدہ تعریفات کو ہدف بناتے ہیں دراصل اپنی تنقید کے لیے بھی انہیں غیرمقامی تہذیبوں کے علمیاتی ڈھانچوں آگے کشکول کھنکھناتے ہیں ۔ ظاہر ہے کہ تمام دستیاب تنقیدوں کا مبسوط احاطہ اور ان پر جاری مباحث کا فوری مطالعہ ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا مخاطبین کو عمومی طور پر یہ باور کروایا جاتا ہے کہ یہ تعریفات علمِ سیاسیات یا علم سماجیات میں ’مشہورومعروف‘ اور ’معلوم‘ ہیں۔اس کے برعکس وہ طریقیاتی منہج جو مسلسل مطالعے اور متون کے معانی پر اٹل مہر لگا دینے کے معاملے میں قدرے تشکیک سے کام لیتے ہیں، سماجی تصورات کو لسانی تاریخ یعنی اصل مقامیت میں رکھ کر ان کے معانی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ معانی بعینہٖ اجنبی تہذیبوں میں کسی تاریخی حقیقت پر منطبق نہیں ہوتے لہٰذا ان تصورات کی قدرے بدلی ہوئی اور متبادل شکلیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن عصرِ حاضر میں اصل متون اور ان کے تراجم تک آسان رسائی کے علاوہ ایسی معطیات (data trends) بھی موجود ہیں جن کے بنیاد پر مختلف الفاظ و تصورات کا معاشروں میں استعمال، ان میں واقع ہونے والی زمانی و مکانی تبدیلیوں اور اشتقاقی جنم او راموات کے تاریخی واقعات کا مشاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے[2]۔
مثال کے طور پر انیسویں صدی کے نصفِ آخر میں انگریزی کی لغت میں داخل ہونے والے لفظ enlightenment کو لے لیجیے جو تصورِ جدیدیت یعنی modernity کی تاریخی اساس کے طور پر مقبول و معروف مانا جاتا ہے اور مخصوص روایتی حلقوں میں کافی بدنام ہے۔ ہمارے ہاں اس کا لغوی ترجمہ روشن خیالی اورخردافروزی وغیرہ کے طور پر کیا جاتا ہے۔انگریزی لغت میں اسی لفظ سے جڑا ایک مرکبِ توصیفی Age of Enlightenment بھی مستعمل ہے جسے سترہویں صدی کی سائنس اور عقلیت پسند تحریکوں، مذہب و کلیسا کی علیحدگی، فرد کی سیاسی و سماجی آزادی اور دیگر عمرانی تبدیلیوں کے مترادف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک اور متعلقہ بلکہ کم و بیش مترادف معنوں میں استعمال ہونے والا لفظ renaissance بھی ہے جس کے لیے اردو میں یوروپی نشاۃ الثانیہ، تنویری تحریک اور یوروپی عقلیت پسندی کی تحریک وغیرہ جیسے مرکبات مستعمل ہیں۔ اگر تین چار الفاظ و مرکبات کے اس مختصر سے تناظر میں ’حریف جدیدیتوں‘ کے تصور پر مقامی تنقیدوں کا مطالعہ کیا جائے تو مذکورہ بالا اور اسی قبیل کی دوسری تنقیدوں کی تہہ میں موجود ذہنی رویوں کی عمومی خاکہ بندی کی جا سکتی ہے۔
اولاً تو یہ تنقیدی مزاج اس حد تک غیررسمی اور خطیبانہ ہے کہ اپنے بدیہی مسلمات اور مفروضوں کو عیاں کرنے سے ایک قدم پیچھے رک جاتا ہے۔ہمیں یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ تنقید کا ہدف بنے تصورات سے شدید اختلاف کیا جا رہا ہے لیکن اس اختلاف کی ٹھوس علمی و تحقیقی بنیادوں تک رسائی ممکن نہیں ہوتی کہ مکالمے کو مزیدآگے بڑھایا جائے۔ثانیاً جیسا کہ پہلے ذکر ہوا یہاں تصورات کی کچھ تعریفات کو یوں محکم اور اساسی مانا جاتا ہے کہ اسی تناظر میں پیش کردہ حریف تحقیقی مطالعوں کو جواز تو کیا دینا،ان کا ذکر تک نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر modernity، enlightenment اور renaissance جیسے الفاظ کے ساتھ جڑی تصوراتی پیچیدگیوں کو یا تو عمداً یاپھر باعثِ لاعلمی مکالمے سے حذف کر دیا جاتا ہے۔بحیثیت طالبِ علم ہم گمان ہی کر سکتے ہیں کہ قبلہ جوہر صاحب غالباً کلاسیکی فرینکفرٹ مکتبِ فکر اور اس کے بعد ہیبرماس جیسے مفکرین سے جدیدیت کی تعبیر وتعریف لے کر اس کی مدد سے بلادِ مشرق بالخصوص ایشیائی معاشروں میں برپا ہونے والی عقلیت پسندی، انفرادیت پسندی اور متاثر و متعلق مذہبی اصلاحی تحریکوں کو اپنی تنقید کا تختۂ مشق بنا رہے ہیں۔مانگے کی یہ تنقید چونکہ اپنے ساتھ یوروپ کی سماجی اشتقاقیات نہیں لا سکتی لہٰذا ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جسےصرف خطابت ہی سے پر کیا جا سکتا ہے۔ثالثاً اس قسم کے دعوے دہرانے کے باوجود کہ عقل ،وحی اور تاریخ کا دھارا تقدیر کے تابع ہے ،ان دعووں کی بنیادوں میں موجود زمانی و مکانی تصورات و تشکیلات کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی۔یوں یہ سوال بدستور تشنہ رہتا ہے کہ مسلم فکر کلاسیکی مابعدالطبیعیات میں پیدا ہونے والے پانچ سو سالہ انقلابات پر کیا رائے رکھتی ہے؟ یا کوئی رائے رکھتی بھی ہے یا نہیں! ان معاشروں میں پیدا ہونے والا فرد تجربہ و عمل کی دنیا میں وجود وشعور کو کس طرح ایک اکائی میں تبدیل کر سکتا ہے؟ کیا ہم ان معاشروں کو کسی بھی معنی میں ’جدید‘ معاشرے کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر جواب ہاں میں ہے تو کیا حریف جدیدیت محض اس نئے فرد کی اپنے وجودی حال یعنی existential human condition سے مثبت علمیاتی یا تخلیقی سمجھوتے ہی کی ایک صورت نہیں؟
نتیجتاً اس تنقیدی صورتِ حال میں اس سوال پر مکالمہ ممکن نہیں رہتا کہ کیا ہم خالص مغربی تناظر سے ہٹ کر اپنے مخصوص تناظر میں متبادل، حریف یا غیرمغربی جدیدیت کی بابت کلام کر سکتے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ خود یہ مغربی تناظر بھی ایک اٹل اکائی نہیں بلکہ کم از کم تین صد سال پر پھیلا ہوا ایک مکالماتی منظر نامہ ہے۔ہمارا ماننا ہے اس منظر نامے پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالنے سے بھی الفاظ کے مشار الیہ تصورات کی پیچیدگیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔آئیے ہم مثال کے طور پراسی لفظ enlightenment کی سماجی اشتقاقیت کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں۔
واقعہ یہ ہے کہ جب یہ لفظ سن ۱۸۶۵ء کے لگ بھگ جرمن لفظ Aufklärung کے ترجمے کے طور پر انگریزی لغت میں داخل ہوا تو کم و بیش ایک صدی کے سماجی و سیاسی مباحثے اور ان کا فلسفیانہ تناظر اپنے اندر سموئے ہوئے تھا۔اس کے فوراً بعد انیسویں صدی کے انگریزی پڑھنے والے اور تقریباً ڈیڑھ سو سال بعد یعنی آج ہمارے دور کے اردو، فارسی اور عربی قارئین کے لیے یہ تناظر ایک گونہ مزید سطحیت (flatness) کا شکار یوں ہوا کہ جدیدیت جیسے تصورات پر ہونے والی تنقیدیں اور مختلف تعبیرات نے جن متون کو حوالے کے طور پر استعمال کیا وہ جرمن زبان میں ہونے کے باوجود ایک مخصوص تعبیری تحدید کا شکار ہوئے جو تسلسل سے جاری تھی۔ان متون میں ایک اہم مضمون کانٹ کا ہے جس کے جرمن عنوان میں استعمال ہونے والے لفظ Aufklärung کا ترجمہ Enlightenment کے طور پر کیا جاتا ہے[3]۔ کانٹ کا یہ مضمون جب دسمبر ۱۷۸۴ء میں برلن سے شائع ہونے والے مجلے Berlinische Monatsschrift میں شائع ہوا تو اس سے تین ماہ قبل یعنی ستمبر ۱۷۸۴ء میں کانٹ ہی کے ایک اور ہم عصر مفکر موسیٰ مینڈلسوہن کامضمون بالکل اسی عنوان کے ساتھ اسی مجلے میں شائع ہو چکا تھا[4]۔دونوں مضامین ایک ہی سوال یعنی’’Aufklärung کیا ہے؟‘‘ کا جواب پیش کرنے کی کوشش تھے۔یہ سوال ایک سال قبل یعنی اس سے پچھلے دسمبر جوہان فریڈرک زولنر نامی مذہبی عالم اور مصلح نے اسی مجلے میں شائع شدہ ایک مضمون میں ضمنی طور پر پسِ تحریر ایک حاشیے میں اٹھایا تھا۔ اور پیچھے چلیے توزولنر کی یہ تحریر ایک اور ایسے بے نامی مضمون کےجواب میں تھی جس کا بظاہر گمنام لکھاری بھی اسی مجلے کا مدیر جوہان ایرک بیسٹر تھا ۔ بیسٹر کا مختصرمضمون اس سوال پر بحث کرتا تھا کہ کیا شادی بیاہ کے موقعوں پر پادریوں کے ذریعے کلیسا کی نمائندگی ضروری ہے؟ زیرِ بحث مسئلہ یہ تھا کہ رجعت پسند یا سادہ لوح (un-enlightened) لوگ شادی بیاہ کے معاہدوں کو دوسرے تمام معاہدوں کی نسبت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیوں کہ اول الذکر معاہدے کلیسائی اشیرباد کی وجہ سے مقدس مانے جاتےہیں۔بیسٹر کا استدلال تھا کہ شادی بیاہ کےمعاہدوں سے کلیسائی نمائندگی کی حاضری کی شرط کو ختم کر دینے سے تمام شہری معاہدے ایک جیسی اہمیت اختیار کر لیں گے۔
اس سے پہلے کہ تصورِ جدیدیت کے خلاف مذکورہ بالا مخصوص تنقیدی رجحان کے علم بردار دوست احباب فوراً ایرک بیسٹر کے استدلال میں ’’سیکولرائزیشن‘‘ کی بُو سونگھ لیں، سیاق و سباق کو کلیت میں سمجھنا ضروری ہے۔بیسٹر کے متن پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نظر میں بنیادی مسئلہ شادی بیاہ کے معاہدوں سے مذہبی بے دخلی نہیں بلکہ اس کے برعکس تمام انفرادی و اجتماعی معاہدوں یعنی شہری ذمہ داری کو یکساں ’’مذہبی‘‘ اہمیت کا حامل سمجھنا تھا۔دوسرے لفظوں میں یہ شادی بیاہ کے معاہدوں سے کلیسائی بے دخلی نہیں بلکہ ایک نئی قسم کی’ ’شہری مذہبیت‘‘ کے امکانات کا جواز تھا، جہاں بیسٹر کے الفاظ میں ’’مذہبی عقیدہ اور شہری ذمہ داری ایک بندھن میں بندھ کر مناسب تال میل سے آگے بڑھیں‘‘۔یہ اور اس قسم کے دوسرے سماجی و سیاسی مسائل اس مخصوص ذہنی رجحان کا حصہ تھے جو اٹھارہویں صدی کی المانوی علمی معاشرت کی تشکیل کرتے تھے۔بیسٹر، زولنر ، مینڈلسوہن اور قریباً دو درجن متنوع فکری دھاروں سے تعلق رکھنے والے مفکرین اس ’بدھ وار سوسائٹی‘ کا حصہ تھے جو Berlinische Monatsschrift کے ذریعے اپنے اجلاسوں میں زیرِ بحث آنے والی آراء شائع کرتی تھی۔
قصہ مختصر،زولنر کے مضمون کے حاشیے میں اٹھائے گئے سوال کے جواب پر ’بدھ وار سوسائٹی‘ کے اندر ہی بہت سی آراء سامنے آئیں۔ کچھ مفکرین مثلاً جوہان کارل ولہلم موہسن نے Aufklärung کی تعریف پیش کرنے کی بجائے توہم پرستی اور دوسرے تعصبات کی بنیادوں کا کھوج لگانے کے رویے پر زور دیا جو بالواسطہ عوامی استدلال کے ضوابط کو ازسرِ نو سنوارنے میں مددگار ثابت ہوسکتا تھا ۔اس کا سوال تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ برلن میں تو ایک ثقافتی روشن خیالی (یعنی Aufklärung ) فروغ پا چکی ہے لیکن مضافاتی علاقوں کے عوام اب تک استدلال کے پرانے رویوں پر قائم ہیں۔ موہسن نے دبے دبے الفاظ میں بادشاہی نظام کے تحت المانوی پالیسی اور افسرشاہی کو قانونی ، کلیسائی اور علمی دائروں میں ایک مخصوص روایتی ثقافت اور اس سے منسلک استدلالی ڈھانچوں کو قائم و دائم رکھنے کا ذمہ دار ٹھہرایا کیوں کہ اس کے ذریعے عوام کی سادہ لوحی کو استعمال کرنا آسان تھا۔المانوی علمی ثقافت کے اس مخصوص تناظر میں یہ جاننا اہم ہے کہ لسانی اعتبار سے روشن خیالی کے بنیادی معنی کا تعین توہم پرستی کے مقابل تھا جو روایتی یوروپی معاشرت کا اٹوٹ انگ تھی۔
یہی وہ نکتہ ہے جو کانٹ کے مشہور مضمون کی اولین عبارت میں پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آتا ہے جس کی رو سے Aufklärung کا آدرش دراصل انسان کی اپنے پیروں میں خود اپنے ہاتھ سے باندھی گئی بھولپن کی زنجیروں کو توڑ دینا ہے۔ یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ لسانی معطیات پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں Aufklärung ، Kultur اور Bildung جیسے جرمن الفاظ اٹھارہویں صدی کے بعد ایک نہایت بڑھوتری سے متون میں پھیلتے نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ Aufklärung کا سوال محض سیاسی یا سماجی میدان میں عملی منصوبہ بندی تک محدود نہیں رہتا بلکہ پھیلتے پھیلتے ثقافت (Kultur ) اور تہذیبی اصلاح (Bildung ) کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ دوم، اس تناظر میں کانٹ کی عوامی اور ذاتی استدلال کی تقسیم ایک مخصوص سمجھوتے کی جانب اشارہ ہے جس کی رو سے مذہبی استدلال ایک عملی عقیدے نہ کہ نظری اعتقاد کا ایک مسئلہ ٹھہرتا ہے۔ظاہر ہے کہ کلیسائی نمائندہ اپنے اعتقاد یا من مرضی سے تو شادی بیاہ کی رسوم میں مہرِ کلیسا کے کر نہیں آن ٹپکتا بلکہ کلیسا کا تفویض کردہ ایک فریضہ نبھا رہا ہوتا ہے۔
روشن خیالی، خردافروزی یا تنویری تحریک کی المانوی جہت پر یہ مختصر سی بحث پیش کرنے کا مقصد محض سماجی لسانیات ، تاریخ اور سیاست سے جڑی ان پیچیدگیوں کی جانب اشارہ ہے جو جدیدیت جیسے تصورات سے وابستہ ہیں۔ چونکہ حریف جدیدیت کے منصوبے سے متعلق مقامی مکاتبِ فکر اپنی سماجی (لہٰذا علمی اور سیاسی) خاکہ بندیوں میں ’جدیدیت‘ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ، لہٰذا نہ صرف یہ ’غیرمقامی‘ تاریخی پیچیدگیاں بلکہ جدیدیت کے تصور پر ہونے والی تنقیدوں کے عصری دھارے بھی پیشِ نظر رکھنا ضروری ہے۔یہاں پہلا سوال ایک بار پھر اس تناظر یا پیراڈائم کا ہے جس میں یہ دھارے جنم لیتے اور متعین اور سوچی سمجھی سمت میں اپنے بہاؤ کو جاری رکھتے ہیں۔یہ تناظر یقیناً المانوی تاریخ تک محدود نہیں بلکہ انگریزی ترجمے کے ذریعے انیسویں صدی کے وسط ہی سے ایک طرف تو Aufklärung کو Enlightenment اور Enlightenment کو ’جدیدیت‘ سے جوڑ چکا ہے، دوسری طرف یہ علمی منظرنامے کو دو ایسی شاخوں میں تقسیم کر دیتا ہے جو ایک دوجے کو کبھی کبھار کاٹتی تو ضرور ہیں لیکن اپنی ایک الگ شناخت برقرار رکھتی ہیں۔
ان میں پہلی شاخ سیاسیات کی ہے جہاں ’جدید‘ اور ’جدیدیت ‘ میں ایک واضح فرق ہے۔جدید وہ ہے جو اب قصۂ پارینہ ہے لیکن اس کی بازگشت پس منظر میں سنائی دیتی ہے۔یہ ایک زمانی سلسلہ ہے جو قدیم، وسطی، جدید اور عصری یعنی ان چار پڑاؤ میں مسلسل ڈھلتا رہتا ہے۔جدیدیت اس زمانی سلسلے کے آخری پڑاؤ یعنی عصرِ حاضر سے متعلق ایک ایسی نفسی و سماجی حالت ہے جو اپنے داخلی اور خارجی مظاہر میں پچھلے تین زمانی پڑاؤ کے مقابلے میں انوکھی ہے۔ان مظاہر کا ایک مجموعہ علمی رجحانات، ثقافتی و سماجی مسائل پر تنقیدی غوروفکر اور انفرادیت و اجتماعیت جیسی کشمکش پر ذہنی میلانات سے متعلق ہے، جب کہ دوسرا مجموعہ ان رجحانات سے متعلقہ قوانین، افسرشاہی ، تعلیم اورمعاشیات وغیرہ کے لیے قائم کردہ اداراتی ڈھانچوں سے تعلق رکھتا ہے۔
دوسری شاخ سماجیات و بشریات کی ہے جہاں جدید اور جدیدیت کو ایک دوسرے سے الگ کرنا نسبتاً مشکل ہے۔ اس تناظر میں جدیدیت کی کہانی کا بیانیہ ایک تہذیبی و تاریخی بیانیے کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور یہ کہانی اگر اسی طرح سنائی جائے تو بامعنی تسلیم کی جاتی ہے۔یہاں اٹھنے والے تمام سوال جیسے کہ ہم کون ہیں اور کن آدرشوں سے بندھے ہیں یا ہم کون نہیں ہیں اور کون سے آدرش ہمارے لیے کشش نہیں رکھتے، کسی نہ کسی مقامیت کو پیش قیاس کرتے ہیں یعنی ہمیں اپنی زمین اور اس زمین پر پیش آنے والے مخصوص حالات سے جوڑتے ہیں۔ گو یہ بیانیہ تاریخی خاکوں اور تشکیلات کی مدد سے بنُا جاتا ہے لیکن اس کی بنیادی حیثیت معالجاتی ہوتی ہے ۔ اب جدیدیت ایک ایسی یک طرفہ انسانی حالت بن جاتی ہے جو عصری مسائل کے حل کے لیے اپنی مظہری تعریف و تشکیل پر اصرار کرتی ہے۔ یوں زمانی سلسلے کے عصری پڑاؤ پر ’جدید ثقافت‘ ثقافتی مظاہر کے ایک ممتاز اور ممیز مجموعے کے ساتھ سامنے آتی ہے۔
ان دو شاخوں کو سامنے رکھنے سے تصورِجدیدیت اور اس پر ہونے والی تنقیدوں کی زمرہ بندی آسان ہو جاتی ہے[5]۔ مکرر عرض ہے کہ یہ زمرہ بندی نہ صرف علمی بلکہ نفسیاتی جہت بھی رکھتی ہے کیوں کہ مخصوص نفسیات انسانی ذہن کے سامنے موجود مخصوص استدلالی ڈھانچوں میں ترجیح و انتخاب پر ابھارتی ہیں۔چونکہ موضوع ان تنقیدوں کی زمرہ بندی نہیں لہٰذا طوالت سے بچتے ہوئے ان تنقیدوں کی کامیابی اور ناکامی کے امکانات کا مختصراً احاطہ کافی ہے۔
انیسویں صدی کے نصفِ آخر او ربیسویں صدی کے اوائل کے مفکرین اس نئی ثقافت کو کسی نہ کسی درجے پر ایک ایسی مستقل تبدیلی کا حصہ مانتے آئے جو استدلالی رویوں میں ایک مستقل تبدیلی کا نام ہے۔میکس ویبر کی بقول یہ فسوں ربائی (disenchantment) زمانی سلسلے کے تیسرے پڑاؤ یعنی ’دورِ جدید‘ سے ماقبل ایک ایسا عمل ہے جو ہمیشہ سے جاری ہے لیکن کبھی ختم نہیں ہوتا[6]۔ لیکن سائنسی انقلاب کے بعد بھی ایسے ثقافتی مظاہر ہمیشہ موجود رہے ہیں جو سماجی سائنسی اور ٹھوس ریاضیاتی تشکیلات سے ماورا ہیں۔ویبر کے نزدیک یہ عمل یک طرفہ ہے اور اس کی یہی یک سمتی کسی بھی جدیدیت مخالف منصوبے کی ناکامی کے امکانات پر مہر ثبت کرتی ہے۔ویبر سے ربع صدی قبل کارل مارکس کا تصورِ جدیدیت پیدوار ی اشیاء کی صارفیت کے گرد گھومتی ایک ایسی نئی ثقافت کی تشکیل ہے جو شے کے سماجی تصور اور شے کی پرستش کے سماجی مظہر سے جنم لیتی ہے۔مارکسی تناظر میں ثقافتِ جدید کا تنقیدی مطالعہ اس اہم نکتے پر منتج ہوتا ہے کہ سرمایہ داریت میں طاقت کا مرکز انسان کی جگہ غیرانسانی عوامل بن جاتے ہیں۔ جدید ثقافت کی ان دونوں خاکہ بندیوں کو سامنے رکھا جائے تو اہم ترین اور بنیادی سوال کسی تیسری متبادل خاکہ بندی کا نہیں بلکہ جدیدیت نامی ایک ثقافت کے خلاف ممکنہ ردّ عمل کا ٹھہرتا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خالص مظہری درجے پر زمانۂ جدید میں انسانی حالت (لہٰذا ثقافت) میں قلبِ ماہیت کا واقعہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے خلاف کوئی قابلِ التفات شہادت پیش نہیں کی جا سکتی۔یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں کہ ویبر اور مارکس دونوں ہی اس نئی ثقافت پر طاری پراسرار پردہ چاک کر کے اس کی اصل ماہیت جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ویبر کے ہاں اس پراسرار مظہر کی تہہ میں مسلسل ارتقا سے گزرتا ایک مخصوص استدلالی ڈھانچہ کارفرما ہے جب کہ مارکس کے نزدیک جدیدیت ایک ایسا نظریہ ہے جو طاقت کے موجودہ ڈھانچوں کے لیے استدلالی کمک کا کام کرتا ہے۔اس تناظر میں یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں رہتا کہ ویبر کے نزدیک جدیدیت انفرادیت اور آزادی کا ایسا مظہر ہے جس کے خلاف کسی مخالف منصوبہ بندی کی گنجائش نہیں رہتی جب کہ مارکس کے ہاں مناسب ردّعمل نظریاتی تنقید ہے۔اڈورنو، ہوک ہائمر اور ان کے بعد ہیبرماس وغیرھم کا کام مارکس کی اسی نظریاتی تنقید کا تمام ممکنہ جہات میں پھیلاؤ ہے۔
یہ نہایت مختصر پس منظر حریف جدیدیت کی سمت میں سفر کرتے بہت سے متنوع منصوبوں کو ایک اکائی میں پرونے کے لیے ضروری ہے۔یوروپی جدیدیت پر خود بھی ایک تنقید ہوتے ہوئے حریف جدیدیت یہ مان کر ہی آگے بڑھتی ہے کہ جدیدیت سے فرار ممکن نہیں اور اس کے خاتمے کے متعلق تمام شکوک و شبہات اور پیشین گوئیاں زیادہ سے زیادہ کسی نظریاتی بند گلی میں جا کر ختم ہو جاتی ہیں۔ صرف یہ واقعہ کہ جدیدیت یوروپی تاریخ کا ایک واقعہ ہے اسے خالصتاً یوروپی نہیں بنا دیتا۔ یہ ایسے ثقافتی مظاہر اور استدلالی ڈھانچوں کا مجموعہ ہے جس کا غیرمغربی دنیا میں پھیلاؤ ایک طرف تو یوروپ اور امریکہ کے استعماری منصوبوں اور دوسری طرف مغرب اور دیارِ غیر مغرب کے باہمی اختلاط سے ممکن ہوا۔لیکن چوں کہ یہ پیچیدہ ثقافتی اختلاط خطی یا یک سمتی نہ تھے ،خود جدیدیت کی تہوں میں بھی ایک ثقافتی تکثیریت کی تلاش معقول ہے۔ لیکن اس پیش قیاسی مفروضے کے علاوہ حریف جدیدیت اوپر پیش کیے گئے دو شاخہ علمی تناظر میں جنم لینے والے دو اہم سوالوں کا ممکنہ جواب بھی ہے۔
اول یہ کہ مغربی جدیدیت کی اس دُبدھا کا کیا حل ہو جو عمرانی اور ثقافتی جدیدیت کی دو رخی تقسیم رکھتی ہے ؟[7] ان میں پہلی یعنی عمرانی جدیدیت ان مظاہر کا نام ہے جو ذہنی میلانات اور سماجی رویوں میں قلبِ ماہیت کی وجہ سےپیدا ہوتے ہیں مثلاً سائنسی شعور، ایک مخصوص غیر مذہبی استدلالی رویہ، نظریۂ ترقی، افادیت پسند عقلیت ، سماج کی ایک معاہداتی ساخت، منڈی کی سرمایہ دارنہ صنعتی معیشت، قومی ریاست کی افسر شاہی، قوانین کے منقسم دائرے، انسانی حرکت میں تیزی، شہری دائروں میں وسعت ، میڈیا کی صنعت اور انفرادیت پسندی وغیرہ۔یہ وہ بورژوائی جدیدیت[8] ہے جس نے مغرب کے صنعتی انقلاب کے بعد ایک ایسے آدرش کی صورت اختیار کر لی جو ایک مثبت اور صحت مند سماج کی ضامن قدر کے طور پر باقی دنیا میں طاقت کے زور پر پھیلا۔اس بورژوا جدیدیت کے خلاف ایک ایسی باغی ثقافتی جدیدیت کا ظہور ہوا جس کا آغاز تو اٹھارہویں صدی کی رومانویت پسند تحریکوں سے ہوا لیکن بعد میں میڈیا ، ادب اور فنون ِ لطیفہ کے وجہ سے مکمل سماج میں نفوذ کر گئی۔ہم اسے ایک ایسی جمالیاتی جدیدیت کہہ سکتے ہیں جو بورژوائی جدیدیت سے بغاوت کے باوجود ثقافت میں اپنے نفوذ کے لیے بورژوائی جدیدیت کی تخلیق کردہ دنیا پر منحصر تھی[9]۔
دوم یہ کہ کیا کوئی مظہر خالصتاً جدید کہلایا جا سکتا ہے؟ یعنی کوئی ایسے متعین خدوخال موجود ہیں جن کی بنیاد پر جدید کو غیرجدید سے علیحدہ کیا جا سکے؟ اپنی اصل میں یہ سوال واپس اسی دبدھا کی طرف لوٹتا ہے جس کا ذکر اوپر ہوا۔ یہ وہ تیسرا رخ ہے جو رومانویت پسند زمانی نظریات سے برآمد ہوتا ہے اور جمالیاتی جدیدیت ہی کی ایک ایسی انوکھی جہت بن کر ابھرتا ہے جو روایت اور لمحۂ موجود میں ایک لاینحل جدلیاتی تضاد سے عبارت ہے۔ یہاں اہم مشاہدہ یہ ہے کہ لمحہ ٔ موجود یعنی حال کی کیفیت تعریفی اعتبار سے تو یقیناً نیاپن رکھتی ہے لیکن ہر ’نیا مظہر‘ بہت ہی جلد غائب ہو کر ایک تازہ متبادل کو اپنی جگہ دے دیتا ہے[10]۔ مارکس کے نظریاتی تنقیدی منہج سے کسی نہ کسی درجے میں منسلک مفکرین مثلاً ہیبرماس اس مسئلے کے حل کے لیے ’جدید‘ اور’ نئے پن‘ میں فرق کرتے ہیں۔لیکن یہ سوال اپنی جگہ جوں کا توں رہتا ہے کہ کیا ہم ’نئے پن‘ کے خارج میں کوئی ’جدید‘ مظہر تلاش کر سکتے ہیں؟
یہ جدیدیت کے وہ دو اہم خاکے ہیں جو اپنے مخصوص خدوخال کے ساتھ خالصتاً مغربی ہیں۔عصرِ حاضر کے علمی پیراڈائم میں انہیں عمومی طور پر ویبر کی سماجی ثقافتی جدیدیت یا بادلئیر کی سماجی جمالیاتی جدیدیت کہا جا تا ہے۔اوّل الذکر خاکے میں جدیدیت ثقافت میں معنی کی کلیت کے حصے بخرے کر دیتی ہے۔ اس کے مثبت اثرات میں انسانی معاشرت کی تکنیکی عظمت، انفرادی و اجتماعی معاشی ترقی اور سیاسی حریت شامل ہیں جب کہ منفی اثرات میں اجنبیت کا وجودی حادثہ ، فرد کی یاسیت اور کسی قسم کی سرّی چھتر چھایا سے آزادی کے بعد تاریک لامعنویت کا ظہور ہے۔آخر الذکر خاکہ ان مسائل کے حل کی خاطر ثقافت کو جمالیاتی معنی عطا کرنے کی سعی پر مبنی ہے جہاں فرد تخلیقی تجربے سے مسرت پاتا ہے۔لیکن ظاہری جمالیات کی ایسی دنیا جو جمالیات اور اخلاقیات میں کسی ارفع ربط پر کوئی رائے نہ رکھتی ہو بہرحال فرد کو خودپسندی اور لذتیت کی دلدل میں بھی دھکیل سکتی ہے۔
جدیدیت کے مغربی پیراڈائم میں ہونے والی تمام تر تنقیدیں کسی نہ کسی صورت جدیدیت کی اس دو لخت نظریاتی صورتِ حال پر کوئی نہ کوئی رائے رکھتی ہیں۔مثال کے طور پر فرینکفرٹ مکتب ِ فکر میں ہیبرماس کے مطابق جدیدیت تاحال ایک ایسا نامکمل منصوبہ ہے جسے کوشش سے بچایا جا سکتا ہے[11]۔اڈورنو اور ہوک ہائیمر کی قنوطیت پسند تعبیرات[12] کے برعکس ہیبرماس کے نزدیک ویبر کی استدلالی خاکہ بندی دراصل سرمایہ داریت کے تحت ہے اور ایک ایسا متبادل خاکہ ممکن ہے جو جدید دنیا میں کارفرما عقلیت و استدلال کو اس کا کھویا ہوا توازن واپس عطا کر دے۔دوسری طرف فوکو جیسے مفکرین استدلال کی جینیاتی خاکے بندی سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ استدلال صرف ثقافتی سیاق و سباق ہی میں نہیں بلکہ علمیات اور طاقت کے ایک ایسے پیچیدہ جال میں کارفرما ہوتا ہے جو( فوکو کے بقول) ہر سماج کی اپنی اقلیمِ حق ہے[13]۔فوکو کے نزدیک ویبر کا آلاتی استدلال عقلیتِ محض کی تحدید نہیں، بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ عقل و استدلال، علم اور سچائی کبھی طاقت کے زیرِ اثر بننے والی پیچیدہ باہمی نسبتوں سے آزاد نہیں ہوتے۔
ہم پر یہ مشاہداتی اور تجرباتی سطح پر واضح ہے کہ حریف جدیدیت کا عمومی منصوبہ نہ صرف غیرمغربی بلکہ خود مغرب کے اندر ہی کئی متنوع ثقافتوں کی طرف سے مظاہرِ جدیدیت کا وہ فہم ہے جو ہر مقامیت کے اپنے مخصوص ثقافتی خدوخال اور مقامی سماجی اور علمیاتی ڈھانچوں سے جنم لیتا ہے۔نہ جانے ہمارے محترم نقادوں کو یہ ماننے میں کیا مشاہداتی امر مانع ہے کہ حریف جدیدیت مذکورہ بالا وسیع پس منظر کو پیشِ نظر تو ضرور رکھتی ہے لیکن ایک مخصوص اجنبیت کا شکار نہیں ہوتی کیوں کہ وہ بالتعریف یوروپ مرکز یت کی نظریاتی گرفتار نہیں۔ محترم مقامی نقادوں سے اتفاق کرتے ہوئے حریف جدیدیت کا تصور تو خود یہ تسلیم کرتا ہے کہ جدیدیت بطور ثقافت مغرب سے غیرمغرب میں وارد ہوئی لیکن یہ اس تصور کی حد نہیں۔ بہرحال وہ ایک ایسا ’ڈسکورس‘ بھی ہے جو حال کے ساتھ اور حال ہی میں ہونے والے ایک مکالمے پر مبنی ہے۔ہماری رائے میں یہ وہ نیا فکری پیراڈائم ہے جو چارلس ٹیلر کے بقول کم سے کم ایک بدیہی مفروضے کو پیش قیاس کرتا ہے[14]۔ وہ مفروضہ یہ ہے کہ جدیدیت کی کوئی بھی خاکہ بندی غیرثقافتی نہیں بلکہ ثقافتی ہے۔یہ مفروضہ خودبخود جدیدیت کی ان ’غیرثقافتی‘ تعریفات اور منسلک منصوبوں کو مکالمے سے باہر دھکیل دیتا ہے جو خود کو ثقافتی طور پر ’غیرجانبدار‘ کہتی ہیں،اور اس غیرجانبداری کا اعلان کرتے ہوئے خارج سے وارد ہو کر ’روایتی‘ سماج کی قلبِ ماہیت کی کوشش کرتی ہیں۔یوں مقامی تہذیبوں کا مخصوص ثقافتی ، مذہبی اور لسانی حوالہ لازم ٹھہرتا ہے۔
بطور طالبعلم ہماری رائے ہے کہ حریف جدیدیت کے ’مقامی ‘ منصوبے پر ہونے والی تنقیدیں بھی اگربراہِ راست اس مقامی تناظر کی تشکیل کے امکانات یا متبادل تناظرات کی تشکیل کو اپنا موضوع بنائیں تو وہ اس نظری شکنجے سے نکل سکیں گی جس میں وہ فی الحال گرفتار نظر آتی ہیں۔ بحث کو آگے بڑھانے کے لیے حریف جدیدیت کے منصوبے اور اس پر ہونے والی تنقیدوں کو سماج کو تجربہ گاہ کے طور تصور کرنا لازمی ہے تاکہ نظری خاکوں کی تجرباتی تشکیل کی جا سکے اور مناسب وقت گزرنے کے بعد منصوبے کی کامیابی یا ناکامی اور متعلقہ تنقیدی مطالعوں کی معقولیت یا غیرمعقولیت کا فیصلہ کرنا ممکن ہو۔ اس کے لیے پہلے پڑاؤ پر یہ جاننا لازمی ہے کہ اوپر دیے گئے تنقیدی منظرنامے میں ہمارے ہاں کا مقامی انتقادِ فکر کن مکاتب کے ساتھ کس حد تک کھڑا ہے اور اس اتفاق یا اختلاف کی نظری بنیادیں اور ہماری مقامی ثقافتوں میں ان نظری بنیادوں کو تقویت پہنچاتے ٹھوس عملی شواہد کیا ہیں؟
[1] Von Goethe, Johann Wolfgang. Faust. Oxford University Press, USA, 1998.
[2] See for example, a quick comparative trend of three words, i.e., enlightenment, modernity and historicism from year 1800 to 2000. https://books.google.com/ngrams/graph?content=modernity%2C+enlightenment%2C+historicism&year_start=1800&year_end=2000&corpus=15&smoothing=3&share=&direct_url=t1%3B%2Cmodernity%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Cenlightenment%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Chistoricism%3B%2Cc0
[3] Kant, Immanuel. “What is enlightenment?” On history (1963): 3-10.
[4] Schmidt, James. “The Question of Enlightenment: Kant, Mendelssohn, and the Mittwochsgesellschaft.” Journal of the History of Ideas (1989): 269-291.
[5] Călinescu, Matei, and Matei Calinescu. Five faces of modernity: Modernism, avant-garde, decadence, kitsch, postmodernism. Duke University Press, 1987.
[6] Gerth, Hans Heinrich, and C. Wright Mills. From Max Weber: essays in sociology. Routledge, 2014.
[7] Bell, Daniel. “The cultural contradictions of capitalism.” Journal of Aesthetic Education 6.1/2 (1972): 11-38.
[8] Berman, Marshall. All that is solid melts into air: The experience of modernity. Verso, 1983.
[9] Baudelaire, Charles, and Jonathan Mayne. The Painter of Modern Life and Other Essays (Arts & Letters). London: Phaidon Press, 1995.
[10] Baudelaire, Charles. “The salon of 1846: On the heroism of modern life.” Modern Art and Modernism: A Critical Anthology (1982): 17-18.
[11] Habermas, Jürgen. “Modernity—an incomplete project.” Postmodernism: A reader (1993): 98-109.
[12] Adorno, Theodor W., and Max Horkheimer. Dialectic of enlightenment. Verso, 1997.
[13] Foucault, Michel. Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977. Vintage, 1980.
[14] Taylor, Charles. “Two theories of modernity.” Public Culture 11 (1999): 153-174.









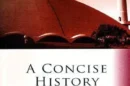












کمنت کیجے