از مولانا محمد علی صدیقی کاندھلویؒ
تحقیق وتخریج: ڈاکٹر انعام الحق غازی/نوید الرحمن داور
مولانا ضیاء الدین کے زمانہ میں علمی حالت:
مولانا سنامی کا زمانہ 646 سے 718 ہجری تک ہے۔ ُاس دور میں ناصر الدین محمود ، غیاث الدین بلبن ، معز الدین کیقباد، جلال الدین فیروز شاہ ، علاء الدین خلجی اور قطب الدین مبارک شاہ ہوئے ہیں۔ یہ 80 سال کے لگ بھگ طویل عرصہ ہے۔ اِن تمام زمانوں میں علماء کی کثرت خوب تھی۔ ناصر الدین محمود کے جن علماء سے تعلقات تھے ان کے نام یہ ہیں: شیخ عماد الدین ، قاضی جلال الدین کاشانی، قاضی شمس الدین بہرائچی، شیخ الاسلام جمال الدین بسطامی اور مولانا سید قطب الدین۔
غیاث الدین بلبن کے زمانے میں مورخین نے جن علماء کا ذکر کیا ہے اُن میں مولانا برہان الدین محمود، مولانا نجم الدین عبد العزیز دمشقی، شیخ سراج الدین ابو بکر، مولانا شرف الدین دلجوائی، مولانا برہان الدین بزاز، قاضی رکن الدین سامانوی، مولانا کمال الدین زاہد ، مولانا شمس الدین خوارزمی اور مولانا فخر الدین ناقلہ۔علاء الدین خلجی کا عہد خلجی تاریخ میں ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔ اُس زمانے میں جس پائے کے علماء دہلی اور اُس کے اطراف میں جمع ہو گئے تھے اُس کی مثال ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ہے۔ شیخ نور الحق زبدۃ التواریخ میں لکھتے ہیں:
اہل ِفضل و کمال جس قدر اُس کے زمانے میں جمع ہو گئے تھے کسی زمانے میں نہیں ہوئے اور نہ آئندہ ہوں گے۔
قاضی ضیاء الدین برنی کا بیان ہے کہ اِن علماء سے ہر ایک علامہ ٔ وقت تھا اور اپنے فن کا ایسا امام سمجھا جاتا تھا کہ اُس وقت کی اسلامی دنیا یعنی بخارا، سمرقند، بغداد، مصر، خوارزم، دمشق، تبریز، رے اور روم میں اس کا ثانی نہیں مل سکتا تھا۔ علم کا کوئی شعبہ ہو ، منقولات و معقولات کا کوئی گوشہ ہو، تفسیر ہو یا فقہ، اصولِ فقہ ہو یا اصول ِدین، نحو ولغت، کلام ہو یا منطق، ہر فن میں کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ بعض علماء تو غزالی اور رازی کی علمی ذہانت کے مالک تھے۔ فقہ کے ایسے ایسے ماہرین موجود تھے کہ ابو یوسف اور محمد شیبانی کا اُن کو مرتبہ حاصل تھا۔ مولانا جمال الدین ، شاطبی مولانا علاء الدین مقری خواجہ زکی ایسے ماہرین قراءت و تجوید تھے کہ خراسان اور عراق میں بھی اُن کے مرتبے کا کوئی قاری نہیں مل سکتا تھا۔ اسلامی دنیا کے دور دراز علاقوں سے علماء دہلی آتے تھے اور اِن بزرگوں کے سامنے زانوئے ادب طے کرتے تھے۔ برنی نے جن اساتذہ کا ذکر کیا ہے اُن میں قاضی مغیث الدین بیانوی، مولاناتاج الدین کلاہی، قاضی محی الدین کاشانی، مولانا تاج دین مقدم، قاضی شرف الدین سرماہی، مولانا ظہیر الدین بھکری، مولانا رکن الدین سنامی، مولانا ظہیر الدین لنگ،مولانا نصیر الدین، قاضی فخر الدین، مولانا کمال الد ین کوٹلی، مولانا وجیہ الدین پاپلی، مولانا منہاج الدین قائنی، مولانا نظام الدین کلاہی، مولانا نصیر الدین کڑہ، مولانا نصیر الدین صابونی، مولانا علاء الدین تاجر، مولانا کریم الدین جوہری، مولانا حجت ملتانی، مولانا حمید الدین مخلص، مولانا برہان الدین بھکری، مولانا افتخار الدین برنی، مولانا حسام الدین سرخ، مولانا وحید الدین ملہو، مولانا علاء الدین کرک، مولانا حسام الدین ابن شادی، مولانا حمید الدین بنیانی، مولانا شہاب الدین ملتانی، مولانا فخر الدین ہانسوی، مولانا فخر الدین سقاقل، مولانا صلاح الدین سترکی، قاضی زین الدین ناقلہ، مولانا وجیہ الدین رازی، مولانا علاء الدین صدر الشریعہ، مولانا میران ماریکلہ، مولانا نجیب الدین ساوی، مولانا شمس الدین تم، مولانا شمس الدین ، مولانا صدر الدین گندھک، مولانا علاءالدین لاہوری، قاضی شمس الدین گاذرونی، مولانا صدر الدین تاری، مولانا معین الدین لونی، مولانا افتخار الدین رازی، مولانا معز الدین، مولانا نجم الدین انتشار۔ یہ تو نمونۂ از خروارے تھے۔ خبر نہیں کتنے اہلِ علم ہوں گے جن میں سے برنی نے اپنی پسند کے مطابق یہ 46 ذکر کئے ہیں۔ [1]
اگر زمانۂ علاء الدین کے کسی مؤرخ کو اِن کے حالات لکھنے کا موقعہ ملتا تو اُس دور کی علمی تاریخ ایسی ہی روشن اور تابناک ہوتی جیسے اُس دور کے مصر و یمن کے علماء کی تاریخ روشن ہے۔
یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ باوجودیکہ، بقول قاضی برنی، اِن علماء کے کمالات کا یہ عالم تھا کہ:
“اگر ایک کے کمالاتِ علمیہ سے متعلق ایک ایک کتاب بھی لکھوں تب بھی حق ادا نہ کر سکوں”[2]۔
مگر اِن کے سارے علمی کمالات صرف درس و تدریس اور وعظ و خطابت ہی تک محدود رہے۔ اُس دور کی تاریخ میں اِن کا کوئی علمی کارنامہ نہیں ہے۔ یہ اَسی سالہ دور تصنیف و تالیف سے بالکل خالی ہے۔ کشف الظنون، الفہرست، معجم المؤلفین اور ثقافۃ الہند کتابیں پڑھیئے ، آپ کو اُس دور کے علماء کا کوئی علمی کارنامہ نظر نہیں آئے گا۔ حالانکہ اُس دور سے پہلے اور اُس دور کے بعد علماء نے بڑے علمی کارنامے انجام دیئے۔ علمِ تفسیر، علمِ حدیث، علم ِفقہ، علمِ سیر و مغازی ، عربی کے لسانی اور ادبی علوم، اِن میں سے کسی بھی علم میں کوئی کام نہیں ہوا ہے جبکہ اِسی ہندوستان میں اِس سے پہلے دور میں کام ہوتا رہا ہے۔
حیرت ہے، اُسی زمانے میں مصر میں بھی ترکی النسل تاتاریوں کی حکومت ہے۔ الملک الظاہر بیبرس اُسی زمانے میں مصر کا حکمران تھا۔ علاء الدین کی طرح بیبرس کی حکومت بھی بڑی وسیع اور منظم تھی۔ اٹھارہ سالہ حکومت 676 ہجری سے لے کر 709 ہجری کل 22 سال کی مدت میں 9 بادشاہ مصر کے تاج و تخت کے مالک رہے جب کہ ہندوستان میں 602 ہجری سے لے کر 715 ہجری تک بارہ بادشاہ تختِ حکومت پر براجمان ہوئے۔ دونوں کا تقابلی مطالعہ کیجئے، یہاں برنی کے بیان کردہ 46 علماء کے نام پڑھئیے ، تاریخ میں اُن کا کوئی علمی کام آپ کو تلاش کے باوجود نہیں ملے گا۔ لیکن آیئے ذرا اُسی زمانے میں مصر کی تاریخ پڑھئیے، وہاں بھی آپ کو علماء ملیں گے مثلا تقی الدین ابو عمر ابن الصلاح 577- 643 ،شیخ الاسلام عز الدین ابن عبد السلام 578-660 ، امام محی الدین نووی 631-702 ، شیخ الاسلام تقی الدین ابن الدقیق العید 625-702، علامہ علاء الدین الباجی 621-704 ، علامہ جمال الدین ابو الحجاج المزی 654 – 742 ، حافظ علم الدین برزالی 665-729 ، علامہ شمس الذہبی 643-748 جیسے محدث اور مؤرخ موجود تھے جو اپنے زمانے میں فنِ حدیث و روایت کے ارکان تھے۔ اِن کے علاوہ کمال الدین ابن الزملکانی 667-727 ،قاضی جلال الدین قزوینی متوفی 739 ہجری ، قاضی تقی الدین السبکی 682-756 ہجری جیسے کامل الفن اساتذہ اور قوی الاستعداد عالم موجود تھے جن کا درس مرجع ٔ خلائق اور جن کا تبحر شہرہ آفاق تھا۔
آیئے اِن کے علمی کارناموں کو ہی پڑھ لیجئے۔ حافظ ابن الصلاح کا علمِ حدیث میں مقدمہ، ابن عبد السلام کی القواعد الکبری، امام نووی کی شرح المہذب اور صحیح مسلم کی شرح، ابن دقیق العید کا التذکرۃ، احکام الاحکام اور شرح عمدۃ الاحکام، الاقتراح ۔ ابو الحجاج کی تہذیب الکمال، حافظ ابن کثیر کی تفسیر اور البدایہ و النہایہ ، ابو الحجاج المزی کی تہذیب الکمال اور علامہ ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ، الاعلام، العبر اور میزان الاعتدال۔ ان علما ء کے کارناموں کا یہاں استیعاب مقصود نہیں، صر ف یہ دکھانا ہے کہ اِن کے مقابلے میں برنی کے 46 علماء کا دامن علمی کارناموں سے خالی ہے۔ برنی کو علاء الدین سے شکایت ہے کہ: “افسوس ہزار افسوس اِن علماء کی بزرگی و فضلیت کی سلطان علاءالدین نے قدر نہیں کی اور اُن کے حقوق کو ایک فیصد بھی ادا نہیں کیا”۔[3]
خبر نہیں برنی کے ذہن میں قدر و منزلت کا پیمانہ کیا ہے ورنہ جیسے مصر میں اہلِ علم سرکاری منصب ِ قضاء و افتاء پر کام کر رہے تھے ،بے شک اُسی طرح علاءالدین، بلبن اور محمود کے زمانے میں بھی علماء سرکاری مناصب پر کام کر رہے تھے۔ بلکہ بڑے بڑے عہدوں پر تھے، مگر اِس کے باوجود مصر کے علماء کی پشت پر پوری تاریخ ہے اور علمی کارناموں کا ایک عظیم انبار ہے جب کہ اُسی زمانے میں اس دور میں ہندوستان کے علماء کے نہ علمی کارنامے ہیں اور نہ ہی اُن کی کوئی تاریخ ہے۔ برنی کے 46 علماء میں سے جن کا چہرہ مولانا عبد الحئی نے نزہۃ الخواطر میں لکھا ہے اُن میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی علمی کارنامہ ہو۔ علم ِحدیث کا ذکر تو کیا ، اُس کے نام سے بھی قاضی ضیاء الدین برنی آشنا نہیں۔ وہ علوم جن سے برنی آشنا ہے، ( یعنی) فقہ، اصولِ فقہ، تفسیر، اصولِ تفسیر، کلام، بلاغت، صرف ونحو اور تصوف ، اُن میں سے 46 بزرگوں کا کون سا قابلِ ذکر علمی کارنامہ ہے؟ صرف مولانا فخر الدین ہانسوی کے بارے میں لکھا ہے کہ اُنہوں نے تصوف کے موضوع پر دستور الحقائق کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ یا پھر مولانا فخر الدین زرادی نے سماع کے موضوع پر اُصول السماع کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے ۔ بلا شبہ اُس دور کے بزرگوں کے ملفوظات اُن کے مریدوں نے ترتیب دیئے ہیں جیسے راحت القلوب ملفوظاتِ فرید شکر گنج، فوائد الفواد ملفوظاتِ شیخ المشائخ ، خیر المجالس ملفوظاتِ شیخ نصیر الحق چراغ۔ اُس دور میں صرف امیر خسرو کی ذاتِ گرامی ایسی ہے جن کی تصانیف کا ذکر ہے مگر اُن کا شمار اُس دور کے علماء میں نہیں بلکہ دانشوروں میں ہے۔ قاضی ضیاء الدین برنی کے ذکر کردہ علماء میں سے اگر کوئی عالم ہے تو وہ صرف مولانا ضیاء الدین سنامی ہیں جنہوں نے اپنے پیچھے علمی کارنامہ چھوڑا ہے ، تفسیر میں تفسیر سورہ ٔ یوسف ہے، قانون میں الفتاوی الضیائیہ ہے، سیاست اور اجتماع میں نصاب الاحتساب ہے۔ تفصیل تو اپنے موقعہ پر آئے گی، یہاں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا سنامی اپنے دور میں ایک منفرد شخصیت ہیں جو ایک وقت میں قاضی، واعظ، مذکر، مفسر، فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ مصنف و مؤلف بھی ہیں۔
بتانا یہ ہے کہ مولانا سنامی کا ماحول علمی کارناموں کا ماحول نہیں، درس و تدریس و وعظ و تذکیر کا ماحول ہے۔ اُس دور کے علماء میں وسعت بھی نہیں اور عمق بھی نہیں۔ غور و فکر کی کمی ہے، گفتار کا ذوق غالب ہے،مذاہبِ فقہیہ کے سانچے پر زور نہ تھا۔ یوں کہنے کو دعوی سب کا تھا کہ حق مذاہبِ اربعہ میں دائر ہے لیکن عملاً حق اپنے مذہب و مسلک کے اندر محدود مانتے تھے۔ ہر مذہب کے پیرو اپنے فقہی مسلک کو تمام مذاہبِ فقہ سے افضل و اعلی سمجھتے تھے، اُن کی تمام ذہانت ، قوت ِبیانی اُس کی ترجیح اور اُسی کی فضلیت ثابت کرنے میں صرف ہوتی تھی۔ اِس کا اندازہ اِس سے ہو سکتا ہے کہ اُس دور کا سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا محدث جس موضوع پر علمی کام کر رہا ہے وہ مسئلۂ سماع ہے۔ اس موضوع پر اُنہوں نے دو رسالے علمی سرمایہ کے طور پر چھوڑٹے ہیں ایک اُصول سماع اور دوسرا کشف القناع عن وجوہ السماع۔ سماع ہی کے موضوع پر ایک مجلسِ مناظر ہ میں مولانا فخر الدین زرادی نے اپنے تبحر علمی اور وسعت نظر کا اس طرح مظاہر ہ کیا کہ:
“علمائے شہر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ دو پہلوؤں میں سے ایک پہلو اختیار کر لیں، اگر حرمت کا پہلواختیار کریں گے تو میں حلت ثابت کروں گا اور اگر حلت کا پہلو اپنائیں گے تو میں حرمت کروں گا”۔[4]
یہ علامت ہے اِس بات کی کہ مولانا سنامی کے زمانے میں تصوف عروج پر تھا، علماء اور بادشاہ تک خانقاہوں سے عقیدت رکھتے تھے ، اُس میں بہت سے غیر اسلامی افکار و عناصر شامل ہو گئے تھے اور بہت سےپیشہ ور جاہل، غیر محقق اور مبتدع اُس گروہ میں شامل ہو کر عوام و خواص کو گمراہی اور شرک و بدعت کی گرم بازاری کا سبب بن رہے تھے۔
بہرحال یہ تھا وہ سیاسی ، اخلاقی، اجتماعی اور علمی ماحول جس میں مولانا ضیاء الدین سنامی نے اپنی عمر کی 78 بہاریں گذاری ہیں، اور جس میں اُنہوں نے اصلاحِ اخلاق ، اصلاحِ معاشرہ اور اصلاحِ نظامِ سیاست کا جھنڈا بلند کیا ہے۔
[1] ۔ تاریخ فیروز شاہی محولہ بالا، ص: 353-354
[2] ۔ تاریخ فیروز شاہی محولہ بالا، ص: 354
[3] ۔ تاریخ فیروز شاہی محولہ بالا، ص: 354
[4] ۔ سیر الاولیاء، محولہ بالا، ص: 424


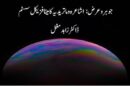
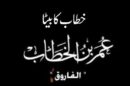



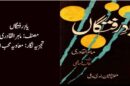


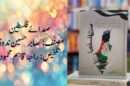








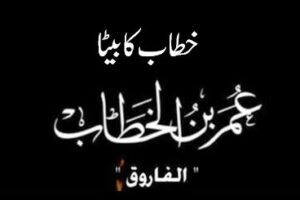


کمنت کیجے