حضرت شاہ ولی اللہ رح کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور مختلف موضوعات پر ولی اللہ فکر سے رجوع و استفادے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ۔لیکن بکثرت ذہن شاہ صاحب کی فکری گتھیوں کو سلجھانے میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ کوئی آٹھ دس سال قبل اپنے مخلص و کرم فرما سید عبید الرحمان(مصنف و ناشر گلوبل میڈیا پبلی کیشنز نئی دہلی) کی خواہش پر میں نے شاہ صاحب کی کتاب “التفہیمات الالہیہ”کا ترجمہ کرنا شروع کیا تو اس میں صاحب تصنیف کے فکری تفردات کا رنگ کچھ زیادہ ہی گہرا نظر آیا اور ذہن اس حوالے سے الجھتا چلا گیا۔ ایک موقع پر اس کا ذکر میں نے پروفیسر یسین مظہر صدیقی مرحوم سے کیا تو سنتے ہی فرمانے لگے کہ شاہ صاحب جب اسلامی تصوف کو یونانی فلسفے کے قالب میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔
یہ مختصر سا تبصرہ بہت با معنی ہے لیکن یہ صرف شاہ صاحب کا مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تصوف کے امام اکبر ابن عربی رح اور شیخ الاشراق شہاب الدین سہروردی مقتول جیسے صوفی فلاسفہ کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ اس سے قطع نظر کہ خود شاہ صاحب ابن عربی سے متاثر ہیں،انہوں نے یونانی فلسفے اور اسلامی تصوف کے امتزاج سے اسلامی فکر کی جس طرح تشکیل و ترجمانی کی کوشش کی اس نے ایک طرف بہت سی فکری پیچیدگیوں کے حل کی راہ ہموار کی تو دوسری طرف اس نے بہت سی نئی فکری پیچیدگیوں اور مشکلات کا دروازہ کھول دیا ۔شاہ صاحب نے “قدم عالم”(eternity of the world) کے حوالے سے یہ نظریہ پیش کیا کہ مادہ علم “قدیم بالزمان حادث بالذات”ہے۔ گویا ارسطاطالیسی تصور کے تحت شاہ صاحب زمان کو لامتناہی تصور کرتے ہیں اور اس حوالے سے مسلم فلاسفہ ابن سینا ابن رشد کے پیروکار ہیں۔ علامہ زاہد الکوثری اور علامہ انور شاہ کشمیری دونوں شاہ صاحب کے اس تصور کے شدید ناقد رہے ہیں۔
اصل سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب اٹھارویں صدی میں یونانی فلسفے کے ملبے کو استعمال کرکے دینی فکر کی تشکیل کے کیوں خواہاں تھے؟ارسطو کا فلسفہ ڈیکارٹ( م،1650) کے بعد اہل علم کےحلقوں میں بہت حد تک اپنی معنویت کھو چکا تھا لیکن دوسروں کی طرح شاہ صاحب بھی اس کے سحر میں گرفتار رہےاور خود کو اس دائرہ فکر سے باہر نہیں نکال سکے۔ابن عربی رح یا شیخ الاشراق یا ان سے ماقبل کے مسلم فلاسفہ کو البتہ اس بنا پر نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ ان کے زمانے کی دنیا فی الواقع ارسطو کے فلسفے سے ہی عبارت تھی۔ کسی نئے عقلی پیراڈائم میں بات کرنا ان کے لئے مشکل تھا۔ ورنہ ناطقہ سر بہ گریباں ہے کہ یونانی فلسفہ کی اس ایک شق کی بناپر کہ ایک ذات سے صرف ایک ہی چیز کا صدور ہوسکتا ہے( الواحد لایصدر عنہ الا واحد)،نظریاتی بھول بھلیوں پر مبنی مسیحی “نظریہ فیض” (emanation theory )کے اسلامی فکر میں در آنے کی راہ ہموار کی۔ چناں چہ”عقول عشرہ “کا تصور وضع کیا گیا کہ خدا نے صرف عقل اول کو پیدا کیا( کیوں کہ ایک سے ایک کا ہی صدور ہوسکتا تھا) اس سے پھر عقل ثانی وہکذا دوسری عقول و افلاک وجود میں آئیں اور موجودات عالم کی تشکیل ہوئی- اس نے ابن عربی رح کو اس بات پر مائل کہ وہ “اعیان وتنزلات” کا پورا فلسفہ وجود میں لائیں جس کے قالب میں وحدت الوجود کا فلسفہ تیار ہوسکے۔


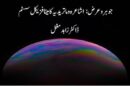
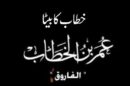



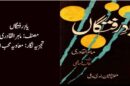


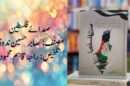








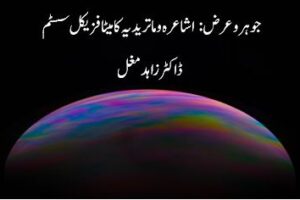
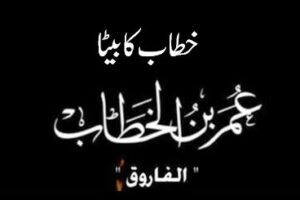

کمنت کیجے