علمِ کلام کے ارتقاء، طرزِ استدلال، اور اثرات کے مطالعہ سے یہ حقیقت نمایاں ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد صرف اسلامی متون کے داخلی مسائل پر نہیں تھی بلکہ اس پر یونانی فلسفے کے گہرے اثرات بھی مرتب ہوئے۔
علامہ اقبال، شبلی نعمانی اور جناب جاوید احمد غامدی کے مطابق، یونانی فلسفے کے اثرات نے علمِ کلام کو قرآن کی سادہ اور وجدانی تعلیمات سے دور کرکے ایک پیچیدہ علمی قالب میں ڈھال دیا۔ اس تبدیلی نے علمِ کلام کے اندازِ فکر کو ایک ایسی استدلالی جہت دی، جو دینی متون کے فطری منہاج سے نمایاں طور پر مختلف تھی۔
شبلی اپنی تحقیقات میں واضح کرتے ہیں کہ اسلامی متکلمین نے جب یونانی فلسفے کے اصولوں کو اپنانا شروع کیا تو ان کی بحثیں قرآن کی سادہ اور وجدانی تعلیمات سے دور ہوتی گئیں، اور ان میں مجرد عقلی اور منطقی اصطلاحات کا غلبہ ہو گیا۔ ان کے مطابق، متکلمین نے اپنے عقائد کے دفاع کے لیے یونانی استدلالی اصولوں کا سہارا لیا، جس سے دینی مباحث فطری استدلال سے ہٹ کر فلسفیانہ موشگافیوں میں تبدیل ہو گئے۔
علامہ اقبال بھی اسی نقطہ نظر کے حامی تھے اور ان کا کہنا تھا کہ علمِ کلام نے اسلامی فکر کو جمود کا شکار کر دیا اور اسے ایک ایسے استدلالی ڈھانچے میں قید کر دیا جس میں منطق اور فلسفہ ہی بنیادی حوالہ بن گئے۔ ان کے نزدیک، اسلامی عقائد کو منطق و فلسفے کے دائروں میں قید کرنے سے دین کی اصل روح نظر انداز ہو گئی، اور علمِ کلام کی پیچیدگیوں نے سادہ دینی حقائق کو غیر ضروری مناظرات میں الجھا دیا یوں وہ فطری وجدانی، اور روحانی سطح پر دین کو زندہ رکھنے میں ناکام رہا، کیونکہ وہ عقل و منطق کے ایسے سانچے میں قید ہو گیا جو انسانی شعور کی داخلی حرکت سے ہم آہنگ نہ تھا۔
استاد جناب جاوید احمد غامدی بھی اس موقف کی تائید کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے یونانی فلسفے، عیسائی الہیات، اور زرتشتی فکر کے نظریاتی چیلنجز کا سامنا کیا، تو انہوں نے انہی کے استدلالی اصول اپنانے شروع کر دیے۔اس کے نتیجے میں اسلامی عقائد میں ایسی منطقی اور تجریدی بحثیں شامل ہو گئیں جنہوں نے دین کے اصل پیغام کے ثبوت و استدلال کو اس کی فکری ساخت سے ہٹا دیا۔
اس کے برعکس، اس موقف کے ناقدین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علمِ کلام کی جڑیں خالصتاً اسلامی ہیں اور اس کا ارتقاء داخلی طور پر مسلم معاشرے میں پیدا ہونے والے فکری اور عقائدی چیلنجز کے نتیجے میں ہوا، نہ کہ کسی بیرونی فلسفے کے زیرِ اثر۔
ان ناقدین کا کہنا ہے کہ متکلمین کے مباحث، جیسے اللہ کی صفات، تقدیر و اختیار، اور ایمان و عمل کا تعلق، وہ سوالات تھے جو خود اسلامی نصوص میں پہلے سے موجود تھے۔ وہ یہ مؤقف بھی تسلیم نہیں کرتے کہ اسلامی متکلمین نے یونانی فلسفے کو اختیار کیا، ان کے مطابق اگر یہ درست ہوتا، تو پھر امام اشعری اور امام ماتریدی جیسے متکلمین کے نظریات یونانی فلسفے کے باضابطہ تعارف سے پہلے کیونکر ظاہر ہوتے؟
مزید برآں، ناقدین یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ ابو حاشم الجبائی جیسے متکلمین کی فکری کاوشیں یونانی فلسفے سے متاثر نہیں تھیں، بلکہ خالصتاً اسلامی نصوص پر مبنی داخلی بحثوں کا نتیجہ تھیں۔ ان کے نزدیک، علمِ کلام درحقیقت ایمانیات کے دفاع میں پیدا ہوا اور اس کا بنیادی محرک یونانی فلسفہ نہیں بلکہ قرآنی تعلیمات اور ابتدائی مسلم فرقوں کے نظریاتی اختلافات تھے۔
تاہم، تاریخی شواہد اس دعوے کی تائید کرتے نظر نہیں آتے۔عباسی خلیفہ ہارون الرشید (170ھ–193ھ) کے عہد میں “بیت الحکمہ” کا قیام اور یونانی فلسفے و سائنس کے متون کا عربی میں ترجمہ ایک اہم سنگِ میل تھا، جس نے اسلامی فکر کو نئے فکری اثرات سے روشناس کرایا۔ ان تراجم نے نہ صرف اسلامی علم کلام کے اندازِ استدلال کو بدلا بلکہ اس کی نظریاتی سمتوں کو بھی متاثر کیا۔ اس عمل کے نتیجے میں متکلمین نے اپنی بحثوں میں یونانی فلسفیانہ اصولوں کو اپنانا شروع کیا اور اسلامی علمی روایت میں تجریدی اور منطقی مباحث کا غلبہ بڑھتا گیا۔
الکندی (185-256ھ) اسلامی فلسفے کے اولین مفکرین میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے ارسطو اور نو افلاطونی فلسفے کے اصولوں کو اسلامی عقائد کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی۔ ان کی تصانیف، مثلاً “الفلسفۃ الاولیٰ”، میں خدا کے وجود کے حق میں دیے گئے دلائل نیوپلاٹونزم کے “واحد مطلق” (Absolute One) کے تصور سے متاثر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ رجحان بعد میں فارابی (339ھ) اور ابن سینا (429ھ) جیسے فلاسفہ کے ہاں مزید واضح ہوا، جنہوں نے اسلامی عقائد کو فلسفیانہ اصولوں کے تحت پیش کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔
عباسی خلافت کے دوران، خاص طور پر مأمون (198–218ھ) کے عہد میں، یونانی فلسفے اور سائنس کے تراجم کا ایک وسیع سلسلہ “بیت الحکمہ” میں شروع کیا گیا۔ اس تحریک ترجمہ کے تحت ارسطو، افلاطون، جالینوس، بطلیموس اور دیگر یونانی مفکرین کے علمی ذخائر کو عربی میں منتقل کیا گیا۔ حنین بن اسحاق (260ھ)، یحییٰ بن عدی (363ھ)، اور ابو بشر متی بن یونس (329ھ) جیسے مترجمین نے یونانی فلسفے کو اسلامی علمی روایت میں شامل کیا، جس نے بعد میں علمِ کلام کے مباحث کو ایک نئے فکری سانچے میں ڈھال دیا۔
نسطوری عیسائی مفکرین، جو یونانی فلسفے میں مہارت رکھتے تھے، اسلامی خلافت میں شامل ہوئے اور انہوں نے یونانی فلسفے کو عربی زبان میں منتقل کیا۔ یعقوبیوں نے بھی نو افلاطونی نظریات کو فروغ دیا، جبکہ زرتشتی علماء نے “نور و ظلمت” (Light and Darkness) کے اصول کو اسلامی نظریہِ تقدیر کے مقابلے میں پیش کیا۔
ان نظریاتی چیلنجز کے جواب میں، متکلمین نے یونانی فلسفے کے اصولوں کو اپنانے کی ضرورت محسوس کی، کیونکہ عیسائی اور زرتشتی فلاسفہ کے ساتھ مناظرات میں صرف نقلی دلائل پیش کرنا ناکافی ثابت ہو رہا تھا۔ یونانی فلسفے کی منطقی اور استدلالی روش نے متکلمین کو ایک مضبوط علمی بنیاد فراہم کی، جس کے ذریعے وہ اپنے عقائد کا دفاع بہتر طور پر کر سکتے تھے۔ چنانچہ، علمِ کلام کے بڑے مکاتبِ فکر، جیسے معتزلہ، اشاعرہ، اور ماتریدیہ، کے نظریات میں یونانی فلسفے کے اثرات نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔
مثال کے طور پر، معتزلہ نے انسانی اختیار اور اعمال کے لیے ذمہ داری پر زور دیا، جو کہ ارسطو کے علت و معلول (Causal Chain) کے اصول سے قریب تر ہے۔ ان کا موقف تھا کہ انسان اپنے اعمال کا خالق ہے اور وہ اپنے اعمال کے نتائج کا ذمہ دار ہے۔ اس نظریے نے نہ صرف عیسائی اور زرتشتی چیلنجز کا جواب دیا بلکہ اسلامی فلسفیانہ روایت کو بھی ایک عقلی اور منطقی تائید فراہم کرنے کی کوشش تھی۔نتیجتاً، یونانی فلسفے کے اصول متکلمین کے استدلال کا ایک لازمی حصہ بن گئے، جو ان کے لیے ایک علمی اساس اور فکری دفاع کا ذریعہ ثابت ہوئے۔
اسی طرح، ان کے خدا کے واحد ہونے کے تصور میں نیوپلاٹونزم کے “واحد مطلق” کا اثر نمایاں نظر آتا ہے۔ اشاعرہ کے نزدیک خدا کی صفات اس کی ذات سے جدا نہیں، بلکہ وہ “بلا کیف” موجود ہیں، جو کہ ارسطو کے “جوہر و عرض” (Substance and Accidents) کے فلسفے سے ملتا جلتا ہے۔ ماتریدیہ نے جبر و اختیار کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی، جو نو افلاطونی “فیضان” (Emanation) کے اصول کے مشابہ ہے۔
ناقدین کی یہ دلیل کہ امام اشعری، امام ماتریدی اور ابو ہاشم الجبائی یونانی فلسفے کے تعارف سے پہلے علمِ کلام کے مباحث میں مشغول ہو چکے تھے، تاریخی لحاظ سے درست نہیں۔ یہ متکلمین دراصل اسی دور میں علمی میدان میں سرگرم ہوئے جب یونانی فلسفے کے تراجم مکمل ہو چکے تھے اور وہ اسلامی علمی روایت میں پوری طرح داخل ہو چکا تھا۔ ان کے ہاں استدلالی اسلوب، منطقی قالب اور تجریدی تعبیرات اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ان کی فکر براہِ راست یا بالواسطہ طور پر یونانی منطق و فلسفے سے متاثر تھی۔ اس لیے زیادہ قرینِ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ اول اول یہ مسائل اسلامی نصوص اور داخلی فرقہ وارانہ مباحث سے پیدا ہوئے، تاہم ان کی تعبیر و تفسیر میں بیرونی فلسفیانہ اثرات کی جھلک نمایاں رہی۔
ابو ہاشم الجبائی (321ھ)، جو معتزلی مکتبِ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا دور عباسی خلافت کے اس مرحلے سے مربوط ہے جب بیت الحکمہ کی تحریکِ ترجمہ اپنے عروج پر تھی .یعنی دوسری صدی ہجری کے اختتام سے تیسری صدی کے وسط تک.جب یونانی فلسفہ، منطق، طب اور سائنس کے اہم متون عربی میں منتقل ہو چکے تھے اور ان کا اثر علمی مجالس میں شدت سے محسوس کیا جا رہا تھا۔ ابو ہاشم کے والد، ابو علی الجبائی (303ھ) بھی اسی علمی ماحول میں پروان چڑھے، جہاں یونانی فلسفے کو اسلامی کلامی فکر سے ہم آہنگ کرنے کی کوششیں جاری تھیں۔
اسی طرح، امام ابوالحسن اشعری (260–324ھ)، جو ابتدا میں معتزلی فکر سے وابستہ تھے،انھوں نے بعد میں اہلِ سنت کے عقائد کے دفاع میں ایک منفرد کلامی جہت متعارف کروائی۔ تاہم ان کا فکری پس منظر، علمی تربیت، اور استدلالی طرزِ استنباط اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ بھی یونانی اثرات سے خالی نہ تھے۔ اگرچہ انہوں نے معتزلہ کے بعض نتائج سے انحراف کیا، لیکن ان کا عقلی و منطقی اصولوں پر اعتماد کا استدلالی منہج وہی رہا، جو یونانی فلسفے کی بنیاد پر اسلامی فکر میں داخل ہوا تھا۔
امام ماتریدی (333ھ) بھی اشعری کے ہم عصر تھے، اور اگرچہ وہ خود فلسفی نہیں تھے، لیکن ان کی کلامی کاوشوں میں عقلی و منطقی استدلال کا غلبہ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ان کے نظامِ استدلال میں جو تجریدی مفاہیم، پیچیدہ مباحث، اور دقیق منطقی بحثیں ملتی ہیں، وہ اس امر کا پتہ دیتی ہیں کہ ان کا علمی ماحول یونانی منطق و فلسفے کے اثر سے خالی نہ تھا۔
یہ بات بجا ہے کہ اللہ کی صفات، جبر و قدر، اور ایمان و عمل جیسے مسائل اسلامی نصوص کی تفہیم کے دوران داخلی طور پر جنم لیتے رہے، اور ان پر ابتدائی صحابہ و تابعین کے دور میں بھی سوالات اٹھے۔ تاہم ان سوالات کو جس انداز سے بعد کے متکلمین نے منطقی، تجریدی، اور قیاسی منہج کے تحت موضوعِ بحث بنایا، وہ اس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک یونانی منطق اور فلسفہ علمی فضا میں داخل نہ ہو چکا ہو۔ خاص طور پر ارسطو کی منطق، جس میں قیاس (syllogism) کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، علمِ کلام کی فکری ساخت پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے، اور اس نے دینی فکر کو اس کے وجدانی، فطری اور نقلی منہاج سے ہٹا کر ایک مجرد اور فلسفیانہ قالب میں ڈھال دیا۔
چنانچہ محض زمانی ترتیب کی بنیاد پر کسی متکلم کو یونانی اثرات سے ماورا سمجھنا تاریخ کی سطحی قرأت ہے۔ فکری اثرات تقویمی ترتیب میں نہیں، بلکہ ذہنوں کی تہوں اور طرزِ استدلال میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور جن ایام میں یہ متکلمین فکری معرکوں میں سرگرم تھے، انہی دنوں یونانی فلسفہ اسلامی کلامی روایت کے مزاج، زبان اور منہج میں گہرائی سے سرایت کر چکا تھا۔
اگرچہ متکلمین نے بسا اوقات یونانی فلسفے پر تنقید بھی کی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کے استدلال کے طریقے، ان کے فلسفیانہ مباحث، اور ان کے دلائل کی بنیادیں اکثر یونانی فلسفیانہ اصولوں پر استوار تھیں۔ امام غزالی (505ھ) نے “تہافۃ الفلاسفہ” میں فلسفے پر سخت تنقید کی، لیکن خود ان کے استدلالی طریقے میں یونانی منطق کا اثر نمایاں تھا۔ امام رازی (606ھ) نے بھی فلسفیانہ اصولوں کے تحت اسلامی عقائد کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے
یہ تمام حقائق شبلی، اقبال اور غامدی صاحب کے اس مؤقف کی تائید کرتے ہیں کہ علمِ کلام صرف ایک داخلی اسلامی علمی تحریک نہیں تھا، بلکہ اس کی تشکیل اور ارتقاء میں یونانی فلسفے کے اصولوں اور اثرات نے اہم کردار ادا کیا۔ متکلمین نے فلسفیانہ مباحث اور اصطلاحات کو اختیار کرتے ہوئے دینی فکر کو ایک ایسا علمی منہاج دیا جو سادہ، فطری اور وجدانی فہم کے بجائے زیادہ تر تجریدی اور منطقی بحثوں پر مشتمل تھا اور جس نے دین کی اصل دعوت دھندلا دی۔
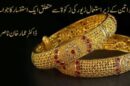
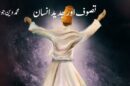
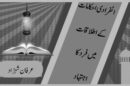
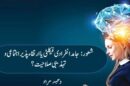















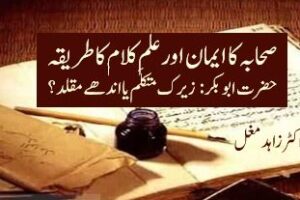
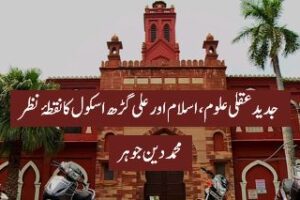
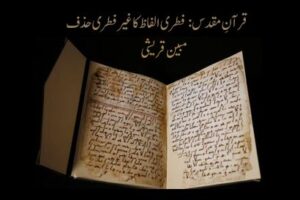
ماشاءاللہ آپ نے بہترین تحقیق پیش کی ہے۔۔برائے مہربانی آپ رہنمائی کرسکتے ہیں کہ ان معلومات کو حاصل کرنے کے لیے کس کتاب کی طرف رخ کروں۔۔شکریہ