سورہ یوسف میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں ایک واقعہ یہ بیان ہوا ہے کہ جب سوتیلے بھائی سیدنا یوسف علیہ السلام کی فرمائش پر ان کے سگے بھائی بن یامین کو اپنے ساتھ مصر لے کر آئے تو ان کی خواہش ہوئی کہ وہ بن یامین کو اپنے پاس روک لیں۔ اس کی تدبیر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو یوں سجھائی کہ وہ بن یامین کے سامان میں اپنا ایک برتن رکھ دیں۔ پھر جب قافلہ غلہ لے کر رخصت ہونے والا تھا تو شاہی کارندوں نے بادشاہ کے پیمانے کو گم پایا اور قافلے والوں پر چوری کا الزام لگا دیا۔ قافلے والوں نے یہ کہہ کر صفائی دی کہ ہم چور نہیں ہیں اور تلاشی کے بعد اگر کسی کے سامان میں سے برتن نکل آئے تو ہمارے ہاں کے رواج یا قانون کے مطابق اس شخص کو ہی سزا کے طور پر محبوس کر لیا جائے۔ یوں برادران یوسف کی اپنی رضامندی کے مطابق جب بن یامین کے سامان سے برتن نکل آیا تو یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کا راستہ نکل آیا۔
اس خفیہ تدبیر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ’’ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ“ (آیت ۷۶)۔ اس کا ترجمہ جمہور مفسرین نے یہ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے مصر کے قانون کے مطابق یہ ممکن یا جائز نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر سے ان کے لیے یہ ممکن ہو گیا۔ مولانا مودودی کو اس ترجمے سے اختلاف ہے۔ ان کی رائے میں درست ترجمہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون پر عمل کرتے، کیونکہ ایک غیر اسلامی حکومت کے قانون پر عمل کرنا نبی کے شایان شان نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر رو بہ عمل کی اور جب برادران یوسف نے خود شریعت ابراہیمی کے قانون پر عمل کی تجویز دے دی تو حضرت یوسف کے لیے شریعت ابراہیمی کی رو سے، نہ کہ مصر کے قانون کی رو سے بھائی کو روکنے کا جواز پیدا ہو گیا۔
مولانا لکھتے ہیں:
’’عام طور پر اس آیت کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ’’یوسف بادشاہ کے قانون کی رو سے اپنے بھائی کو نہ پکڑ سکتا تھا“۔یعنی ما کان لیاخذ کو مترجمین ومفسرین عدم قدرت کے معنی میں لیتے ہیں نہ کہ عدم صحت اور عدم مناسبت کے معنی میں۔ لیکن اول تو یہ ترجمہ وتفسیر عربی محاورے اور قرآنی استعمالات دونوں کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ عربی میں عموماً ما کان لہ بمعنی ما ینبغی لہ، ما صح لہ، ما استقام لہ وغیرہ آتا ہے اور قرآن میں بھی یہ زیادہ تر اسی معنی میں آیا ہے۔ مثلاً ما کان اللہ ان یتخذ من ولد، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، فما کان اللہ لیظلمھم، ما کان اللہ لیذر المومنین علی ما انتم علیہ، ما کان لمومن ان یقتل مومنا۔ دوسرے اگر اس کے وہ معنی لیے جائیں جو مترجمین ومفسرین بالعموم بیان کرتے ہیں تو بات بالکل مہمل ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کے قانون میں چور کر نہ پکڑ سکنے کی آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا دنیا میں کبھی کوئی سلطنت ایسی بھی رہی ہے جس کا قانون چور کو گرفتار کرنے کی اجازت نہ دیتا ہو؟“ (تفہیم القرآن، سورہ یوسف)
مولانا کے نزدیک اس جملے کی درست تفسیر یہ ہے :
’’یہ بات حضرت یوسف کی شان پیغمبری کے شایاں نہ تھی کہ وہ اپنے ایک ذاتی معاملہ میں شاہ مصر کے قانون پر عمل کرتے۔ اپنے بھائی کو روک رکھنے کے لیے انھوں نے خود جو تدبیر کی تھی، اس میں یہ خلل رہ گیا تھا کہ بھائی کو روکا تو ضرور جا سکتا تھا مگر شاہ مصر کے قانون تعزیرات سے کام لینا پڑتا، اور یہ اس پیغمبر کی شان کے مطابق نہ تھا جس نے اختیارات حکومت غیر اسلامی قوانین کی جگہ اسلامی شریعت نافذ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں لیے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو اس بدنما غلطی میں مبتلا ہو جانے دیتا، مگر اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ دھبہ اس کے دامن پر رہ جائے، اس لیے اس نے براہ راست اپنی تدبیر سے یہ راہ نکال دی کہ اتفاقاً برادران یوسف سے چور کی سزا پوچھ لی گئی اور انھوں نے اس کے لیے شریعت ابراہیمی کا قانون بیان کر دیا۔“
حاصل یہ کہ قانون تو مصر کا بھی یہی تھا اور اس کی رو سے حضرت یوسف چوری پر اپنے بھائی کو روک سکتے تھے، لیکن نبی ہونے کی وجہ سے ایک غیر اسلامی حکومت کے قانون پر عمل کرنے کے بجائے انھوں نے شریعت ابراہیمی کا حوالہ اختیار کرنا ضروری سمجھا تاکہ نبی کا دامن ایک غیر اسلامی حکومت کے قانون پر عمل سے داغدار نہ ہونے پائے۔
اس دلچسپ تفسیر کے بعض پہلووں پر ہم تبصرہ کرنا چاہیں گے۔
مولانا کی تفسیر پر سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی بیان کردہ صورت واقعہ میں اختیار کردہ تدبیر اور مطلوب نتیجے کے مابین مناسبت کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے۔ جمہور کی تفسیر کے مطابق تدبیر اور نتیجے کی مناسبت بالکل واضح ہے۔ مصر کے قانون کی رو سے بھائی کو محبوس کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تدبیر سے خود برادران یوسف نے چوری کی ایک ایسی سزا تجویز کر دی جو سیدنا یوسف کی منشا کے مطابق تھی۔ یہ ایک واضح اور قابل فہم بات ہے۔ مولانا کی تفسیر کے مطابق تدبیر اختیار کرنے سے مطلوب نتیجے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا، کیونکہ مصر کا قانون بھی یہی تھا اور سیدنا یوسف اس کے مطابق بھی بھائی کو روک سکتے تھے۔ ساری تدبیر کا حاصل صرف یہ نکلا کہ بھائی کو روکنے کی بنیاد مصر کا قانون نہیں، بلکہ بقول مولانا ’’شریعت ابراہیمی“ قرار پائی۔ کیا یہ اتنا ہی حساس معاملہ تھا کہ نتیجہ ایک ہوتے ہوئے بھی صرف فیصلے کی بنیاد کو شرعی بنانے اور غیر شرعی بنیاد سے گریز کے لیے یہ سارا اہتمام کیا گیا؟
مولانا نے آگے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس طرز عمل کی جو مماثلت بیان کی ہے، وہ قطعاً ناکافی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے قبل جن چیزوں سے اجتناب فرمایا، وہ منکرات تھے جن سے اجتناب پیغمبر کی سلیم فطرت کی آواز ہوتی ہے۔ چور کی سزا کیا ہو سکتی ہے اور کیا نہیں، اس کا تعلق معروف ومنکر سے نہیں ہے۔ اگر تو یہ ظلم وعدوان کا معاملہ ہوتا اور شریعت ابراہیمی اور مصر کا قانون باہم متضاد ہوتا تو یہ بات قابل فہم تھی کہ پیغمبر کے لیے کسی مبنی بر ظلم قانون پر عمل سے گریز کی صورت نکالی جائے۔ لیکن جب مصر کا قانون اور مبینہ طور پر شریعت ابراہیمی کا قانون ایک ہی تھا تو یہ سارا اہتمام صریح تکلف بن جاتا ہے۔
پھر یہ مفروضہ اپنی جگہ قابل تحقیق ہے کہ برادران یوسف نے جو سزا بیان کی، وہ ’’شریعت ابراہیمی“ کی بیان کردہ سزا تھی۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ ان کے اپنے علاقے کا رواج یا قانون کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کا کوئی تاریخی ثبوت ہے کہ تورات کے نزول سے پہلے بھی تمام امور سے متعلق شریعت کے تفصیلی قوانین سیدنا ابراہیم اور ان کی اولاد کو دیے گئے تھے؟ اگر نہیں تو ایک علاقے کے رواج کے مقابلے میں دوسرے علاقے کے رواج کے انتخاب کی یہ توجیہ کیونکر کی جا سکتی ہے کہ پیغمبر نے ’’غیر اسلامی حکومت“ کے قانون کے بجائے ’’اسلامی قانون“ پر عمل کا اہتمام کیا؟
مولانا کی تعبیر کے مطابق یہ ساری تدبیر اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمائی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ایک ’’ذاتی معاملے“ میں غیر اسلامی حکومت کے قانون کے تحت فیصلہ نہ کرنا پڑے۔ یہاں مولانا کی پیش کردہ تصویر میں ایک شدید داخلی تضاد پایا جاتا ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ جب نبی نے مصر میں اقتدار کا منصب سنبھالا تو اس کی بنیادی شرائط کیا تھیں؟ کیا ان کا اختیار ریاستی وسائل کے انتظامی بندوبست کی حد تک تھا یا انھیں ریاستی قانون کی تشکیل نو کا اختیار بھی حاصل تھا؟ مولانا کا کہنا ہے کہ انھیں مصر کے سیاہ سپید کا مالک بنا دیا گیا تھا اور انھوں نے اقتدار قبول ہی اس شرط پر کیا تھا کہ مصر میں دین الملک کے بجائے خدا کے قانون کو نافذ کریں گے:
’’یہ اختیارات جو حضرت یوسف نے مانگے اور ان کو سونپے گئے، ان کی نوعیت کیا تھی؟ ناواقف لوگ یہاں ’’خزائن الأرض“ کے الفاظ اور آگے چل کر غلہ کی تقسیم کا ذکر دیکھ کر قیاس کرتے ہیں کہ شاید یہ افسر خزانہ، یا افسر مال، یا قحط کمشنر، یا وزیر مالیات، یا وزیر غذائیات کی قسم کا کوئی عہدہ ہوگا۔ لیکن قرآن، بائیبل، اور تلمود کی متفقہ شہادت ہے کہ درحقیقت حضرت یوسف سلطنت مصر کے مختار کل (رومی اصطلاح میں ڈکٹیٹر) بنائے گئے تھے اور ملک کا سیاہ سپید سب کچھ ان کے اختیار میں دے دیا گیا تھا۔“
اگر واقعتاً یہی صورت تھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصری قانون پر عمل کرنا تو ان پر اس شرط کی رو سے ہی لازم نہیں تھا، پھر شریعت ابراہیمی پر عمل کے لیے اتنی لمبی چوڑی تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی؟ مولانا کے سامنے یہ سوال ہے اور وہ اس کی توجیہ تدریج کے اصول کے تحت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں:
’’ظاہر ہے کہ اللہ کا پیغمبر زمین میں ’’دین اللہ“ جاری کرنے کے لیے مبعوث ہوا تھا نہ کہ ’’دین الملک“ جاری کرنے کے لیے۔ اگر حالات کی مجبوری سے اس کی حکومت میں اس وقت تک پوری طرح دین الملک کی جگہ دین اللہ جاری نہ ہو سکا تھا تب بھی کم از کم پیغمبر کا اپنا کام تو یہ نہ تھا کہ اپنے ایک شخصی معاملہ میں دین الملک پر عمل کرے۔ لہٰذا حضرت یوسف کا دین الملک کے مطابق اپنے بھائی کو نہ پکڑنا اس بنا پر نہیں تھا کہ دین الملک میں ایسا کرنے کی گنجائش نہ تھی، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ پیغمبر ہونے کی حیثیت سے اپنی ذاتی حد تک دین اللہ پر عمل کرنا ان کا فرض تھا اور دین الملک کی پیروی ان کے لیے قطعاً نامناسب تھی۔“
لیکن یہ قطعی طور پر بے معنی توجیہ ہے، کیونکہ اس خاص معاملے میں سوال کسی قانون کو عمومی سطح پر تبدیل کرنے کا نہیں تھا۔ پورے قانونی نظام کی یک بارگی تبدیلی خلاف مصلحت ہو سکتی ہے، لیکن ایک جزوی سے ذاتی معاملے میں اس قانون کی پابندی نہ کرنے میں ایسی کیا رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے یہ ساری تدبیر اختیار کی گئی؟ منصب اقتدار کی بنیادی شرط کے تحت سیدنا یوسف صاف کہہ سکتے تھے کہ میں اس خاص معاملے میں ملکی قانون کے تحت نہیں بلکہ شریعت ابراہیمی کے تحت فیصلہ کروں گا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر وہ یہ سیدھی بات کہنے اور اپنا تسلیم شدہ اختیار بروئے کار لانے کے بجائے ایک پر پیچ راستہ اختیار کرتے ہیں جس کی کوئی حکمت یا منطق واضح نہیں ہوتی اور نہ مولانا اپنی تعبیر میں موجود اس بنیادی تضاد کو محسوس کر پاتے ہیں۔
اب اگر سیدنا یوسف کے اقتدار کی بنیادی شرط مصر میں دین اللہ یعنی خدا کا قانون جاری کرنا نہیں تھا اور وہ مصر کے ملکی قانون کے پابند تھے تو مولانا کی بیان کردہ تفسیر کی بنیاد ہی ڈھے جاتی ہے، کیونکہ وہ کھڑی ہی اس نکتے پر ہے کہ غیر اسلامی حکومت کے بنائے ہوئے قانون کے تحت فیصلہ کرنا ایک پیغمبر کے شایان شان نہیں تھا۔
مولانا نے جمہور کی بیان کردہ تفسیر کے درست نہ ہونے پر دو استدلالات پیش کیے ہیں۔ ایک یہ کہ ’ما کان’ کا اسلوب عربی میں عدم قدرت کے معنی میں نہیں، بلکہ عموماً عدم صحت یا عدم مناسبت کے معنی میں آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ چور کو گرفتار کرنے کی تو دنیا کے ہر قانون میں اجازت ہوتی ہے، اس لیے ’مَا كَانَ لِیَأخُذَ أَخَاهُ فِی دِینِ ٱلمَلِكِ إِلَّا أَن یَشَاءَ ٱللَّهُ’ کا یہ مفہوم عقلاً بھی درست نہیں کہ سیدنا یوسف مصر کے قانون کی رو سے اپنے بھائی کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے۔
دونوں استدلال بہت کمزور اور ناقص ہیں۔ پہلا استدلال اس لیے کہ کسی اسلوب کا ’’عموماً’’ ایک مفہوم میں وارد ہونا اس کی دلیل نہیں بن سکتا کہ اس کا کوئی دوسرا مفہوم نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ہی اس اسلوب کا استعمال مختلف سیاق وسباق میں مختلف مفاہیم میں ہوا ہے۔ چنانچہ ایک عام مفہوم تو یہی ہے کہ ’’مناسب یا روا نہیں تھا’’، جیسا کہ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِیُضِیعَ إِیمَـٰنَكُم (اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ تمھارے ایمان کو ضائع کر دے۔ البقرۃ، ۱۴۳) اور فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِیَظلِمَهُم وَلَـٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُم یَظلِمُونَ (اللہ کے شایان یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر ظلم کرے، بلکہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ التوبہ، ۷۰)۔
یہی اسلوب کسی کے ارادے اور اس کے طریقے یا قانون کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِیَذَرَ ٱلمُؤمِنِینَ عَلَىٰ مَا أَنتُم عَلَیهِ حَتَّىٰ یَمِیزَ ٱلخَبِیثَ مِنَ ٱلطَّیِّبِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِیُطلِعَكُم عَلَى ٱلغَیبِ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ یَجتَبِی مِن رُّسُلِهِ مَن یَشَاءُ (اللہ کا یہ ارادہ یا فیصلہ نہیں ہے کہ مومنوں کو اسی حالت میں چھوڑ دے جس پر تم ہو، جب تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ اسی طرح اللہ کا یہ بھی طریقہ یا ارادہ نہیں ہے کہ تم سب کو غیب پر مطلع کر دے، بلکہ اللہ اس مقصد کے لیے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، چن لیتا ہے۔ آل عمران، ۱۷۹)۔
اسی طرح یہ اسلوب کسی کام کے عملاً ممکن نہ ہونے یا باعث دقت ہونے کو بھی بیان کرتا ہے۔ جیسے وَمَا كَانَ ٱلمُؤمِنُونَ لِیَنفِرُوا كَافَّة فَلَولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَة مِّنهُم طَاىِٕفَة (مسلمانوں کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، لیکن ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکلی؟۔ التوبہ، ۱۲۲)
سورہ یوسف کی زیربحث آیت میں بھی ’مَا كَانَ لِیَأخُذَ أَخَاهُ فِی دِینِ ٱلمَلِكِ إِلَّا أَن یَشَاءَ ٱللَّهُ’ کا جملہ اسی مفہوم میں آیا ہے۔ یہاں اس کے سوا کوئی دوسرا مفہوم ممکن ہی نہیں۔ مولانا نے غور نہیں کیا کہ اگر مراد یہ کہنا ہوتا کہ ’’یوسف کے لیے بادشاہ کے قانون پر فیصلہ کرنا مناسب نہیں تھا’’ تو اس کے لیے ’’ما کان لیحکم بدین الملک“ یا اس جیسی کوئی تعبیر ہونی چاہیے تھی اور اس کے بعد إِلَّا أَن یَشَاءَ ٱللَّهُ کا استثنا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مَا كَانَ لِیَأخُذَ کی تعبیر اور اس کے بعد إِلَّا أَن یَشَاءَ ٱللَّهُ کا استثنا کسی بھی طرح اس تعبیر کو قبول نہیں کرتا جو مولانا نے بیان کی ہے۔
جہاں تک اس نکتے کا تعلق ہے کہ چور کو گرفتار کرنے کی تو دنیا کے ہر قانون میں اجازت ہوتی ہے تو یہ واضح طور پر ایک لفظی twist ہے۔ یہاں چور کو گرفتار کرنا یا نہ کرنا زیربحث ہی نہیں، زیر بحث اس کو چوری کی سزا کے طور پر محبوس کر لینا یا غلام بنا لینا ہے۔ دنیا کا ہر قانون چور کو گرفتار کرنے کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن سزا کے طور پر اس کو مملوک بنا لیا جائے، یہ کوئی آفاقی ضابطہ نہیں ہے۔ مصر کے قانون میں بھی یہ سزا موجود نہیں تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی تدبیر فرمائی کہ برادران یوسف نے خود اپنے علاقے میں رائج سزا تجویز کر دی جس کی بنیاد پر بن یامین کو اپنے پاس روک لینا سیدنا یوسف کے لیے ممکن ہو گیا۔
مولانا کی بیان کردہ تفسیر کا محرک، جیسا کہ ذکر ہوا، دراصل سیاست واقتدار اور قانون ونظام کے حوالے سے ان کا خاص نظریہ ہے جس کی توضیح ان کی کتابوں میں جگہ جگہ کی گئی ہے۔ اس نظریے کی رو سے خدا کی توحید کے تصور میں خدا کی حاکمیت کا نکتہ بنیادی ہے اور اہل ایمان پر اس حوالے سے جو بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ دنیا میں قانون ونظام کی سطح پر خدا کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے۔ مولانا اسی نکتے کی روشنی میں انبیاء کی دعوت اور ان کی ذمہ داری بھی متعین کرتے ہیں اور ان کے نزدیک انبیاء نے جب اپنی قوموں کو لا الہ الا اللہ کا پیغام سنایا اور انھیں صرف خدا کی عبادت اختیار کرنے کی دعوت دی تو یہ دراصل اس بات کا مطالبہ تھا کہ وہ حکومت اور اقتدار کی زمام بھی ان کے ہاتھ میں دے دیں تاکہ وہ خدا کی زمین پر خدا کے قانون کو جاری کر سکیں۔
ظاہر ہے، اس نظریے کے مطابق یہ بات ناقابل تصور ہے کہ اللہ کے ایک نبی کو کسی معاشرے میں ایسا غیر معمولی سیاسی اثر ورسوخ حاصل ہو جیسا کہ سیدنا یوسف کو حاصل ہوا اور وہ اپنی دعوتی ذمہ داری کو انفرادی طور پر لوگوں کو توحید کا پیغام دینے تک محدود رکھتے ہوئے سیاست واجتماع کے دائرے میں، قائم شدہ نظام کی پابندی قبول کرتے ہوئے اپنی صلاحیت اور توانائیوں کو محض لوگوں کی مادی بہبود کے لیے وقف کر دے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے مصر کے اقتدار میں شرکت قبول کرنے کی وہ تصویر جو قرآن سے بظاہر سامنے آتی ہے، مولانا کے اس نظریے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا کو اس پورے واقعے کی ایسی توجیہ وضع کرنی پڑی جو ان کی تعبیر دین سے ہم آہنگ ہو۔
یہ مولانا کے بیان کردہ تصور الہ اور تصور دین کا لازمی تقاضا تھا جس کی وضاحت مولانا نے اپنی کتاب ’’قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں“ میں کی ہے اور تفہیم القرآن میں بھی جگہ جگہ اس کی وضاحت موجود ہے۔ بن یامین کے واقعے کی تفسیر کا یہ فکری پس منظر مولانا نے خود بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے اور اپنے نقطہ نظر سے جمہور کی تفسیر میں موجود فکری ونظریاتی کجی پر بھی سخت الفاظ میں تنقید کی ہے، کیونکہ مولانا کے وضع کردہ خاص کلامی نظریے کا کوئی ذکر اذکار دینی روایت میں نہیں ملتا۔ مولانا نے بن یامین کے واقعے کی، جمہور کی بیان کردہ تفسیر کو ’’دور انحطاط“ کے مسلمانوں کی طرف منسوب کیا ہے، جبکہ تمام اکابر تابعین سے اس کی یہی تفسیر منقول ہے، جیسا کہ طبری کے نقل کردہ آثار میں دیکھا جا سکتا ہے۔
عن قتادة قوله: ﴿ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله﴾ ، يقول: ما كان ذلك في قضاء الملك أن يستعبد رجلا بسرقة.
عن أبي مودود المديني قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: ﴿قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه﴾ = ﴿كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك﴾ ، قال: دين الملك لا يؤخذ به من سرق أصلا ولكن الله كاد لأخيه، حتى تكلموا ما تكلموا به، فأخذهم بقولهم، وليس في قضاء الملك.
عن معمر قال: بلغه في قوله: ﴿ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك﴾ ، قال: كان حكم الملك أن من سَرَق ضوعف عليه الغُرْم.
عن ابن إسحاق: ﴿ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك﴾ :، أي: بظلم، ولكن الله كاد ليوسف ليضمّ إليه أخاه.
قال ابن زيد في قوله: ﴿ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك﴾ ، قال: ليس في دين الملك أن يؤخذ السارق بسرقته. قال: وكان الحكم عند الأنبياء، يعقوب وبنيه، أن يؤخذ السارق بسرقته عبدًا يسترقّ. (تفسیر الطبری، رقم ۱۹۵۷۲ تا ۱۹۵۷۸)
ہذا ما عندی واللہ تعالیٰ اعلم
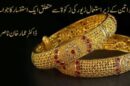
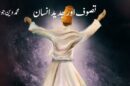
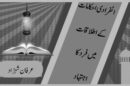
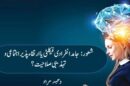















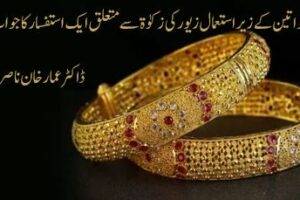
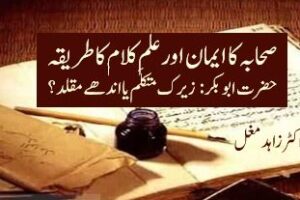

کمنت کیجے