تجدید اور تجدد کا موضوع اپنے مختلف فکری سیاق میں اسلامی فکر و روایت میں ہمیشہ زیر بحث رہا ہے اور اس کی نظریہ سازی و معیار بندی کی جاتی رہی ہے کہ اسلامی فکر کی تعبیر کے کس پہلو پر تجدید اور کس دیگر پہلو پر تجدد کا اطلاق ہوتا ہے؟ تجدید حدیث رسول سے ماخوذ ایک خالص دینی اصطلاح ہے جس کے معنی ہیں :دین کی اصل اور روح کا احیا اور داخلی وخارجی آمیزشوں سے اس کی تطہیر۔جبکہ تجدد کا استعمال دین کی انحرافی تعبیر پر ہوتا ہے۔ البتہ تجدد کی اصطلاح نئی ہے۔ عربی میں یہ لفظ یااصطلاح اس معنی میں مستعمل نہیں۔ عربی میں تجدید کا اطلاق دونوں پہلوؤں: تجدید و تجدد پر ہوتا ہے اور ان کے مابین تفریق کے لیے انہیں دو متقابل رجحانات کی شکل میں دیکھا جاتا ہے۔ یعنی دینی فکر کی تعبیر کے پہلے رجحان کو اسلامی جبکہ دوسرے رجحان کو علمانی(سیکولر) ،غیر اسلامی اور عصرانی وغیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔عربی میں ایک دوسری اصطلاح ’’الحداثۃ‘‘ کی ہے جو جدیدیت (modernism)کے لیے رائج الاستعمال ہے۔ اس لحاظ سے عربی میں تجدید و تجدد کے تصور میں خلط مبحث کی کیفیت بظاہر پائی نہیں جاتی جبکہ اردو میں اس حوالے سے خلط مبحث کی کیفیت پختہ اقلام میں بھی نظر آتی ہے۔
اس تمہید کے بعد بحث کا اصل پہلو تجدد کے اطلاقات سے تعلق رکھتا ہے ۔ایک عمومی علمی ظاہرہ یہ نظر آتا ہے کہ ایسی تمام آرا و مواقف کو تجدد پسندی سے تعبیر کیا جاتا ہے جو جمہور علماء و ائمہ کی آرا سے مختلف اور متصادم ہیں۔مثلا پاکستان کے ایک سنجیدہ مزاج عالم ڈاکٹر حافظ محمد زبیر عرب مصنفین اور دانشوروں میں طہ حسین اور توفیق الحکیم کے ساتھ رشید رضا، یوسف قرضاوی اور وھبہ الزحیلی کو ہندوستانی مصنفین میں سرسید اور غلام احمد پرویز کے ساتھ مولانا طاہر القادری کو بھی متجددین کی صف میں شمار کرتے ہیں ۔(دیکھیے ،’تحریک تجددد اور متجدد دین‘، باب دوم وچہارم)مولانا مفتی تقی عثمانی نے اپنی کتاب ’’اسلام اور جدت پسندی‘‘ میں جہاں ڈاکٹر فضل الرحمن کے افکار کا اس سیاق میں تجزیہ کیا ہے، وہیں مولانا سید سلیمان ندوی اور مولانا حنیف ندوی کے افکار بھی اس کتاب میں تجدد پسندی کے زمرے میں زیر بحث آئے ہیں۔ اسی طرز پر ہندو پاک میں بالعموم ایسے تمام افکار و مواقف پر تجدد پسندی کا اطلاق کیا جاتا ہے جو جمہور کے طریق فکر سے ہٹے ہوئے ہیں ۔ چناں چہ ہندو پاک میں اسی حوالے سے مولانا ابوالکلام آزاد،مولانا وحید الدین خان ، مولانا عمر احمد عثمانی اورجاوید احمد غامدی وغیرہ کے افکار و فرمودات زیر بحث آتے ہیں۔بہت سی تحریروں میں جن پر عموما مسلکیت کی چھاپ گہری ہوتی ہے ،شبلی نعمانی ،مولانا حمید الدین فراہی، مولانا امین احسن اصلاحی اور مولانا ابو الاعلی مودودی جیسی شخصیات کو بھی اس فہرست میں شامل کر لیا جاتا ہے کیونکہ قرآن و حدیث کی مختلف آیات و احکام کے حوالے سے ان کی آرا جمہور علمائے اسلام کی فکر سے مختلف ہیں۔
خالص علمیاتی اور منہجی لحاظ سے یہ ایک بڑا فکری سقم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کے عہد سے دور جدید تک علمائے امت کی کوئی نسل ایسی نہیں گزری، جس کے بہت سے کبار اور نمائندہ علماء کا جمہور علماء امت سے مختلف موضوعات و مسائل پر اختلاف نہ رہا ہو۔ ان کے اقوال و مواقف کو ہمیشہ شذوذ و انفرادات سے تعبیر کیا گیا جس کے لیے اردو میں ’تفرد‘ کی اصطلاح مستعمل ہے۔ کبھی ان شاذ مواقف کی بنا پر ان پر تجدد یا اس کی متبادل اصطلاح کا اطلاق نہیں کیا گیا ۔غزالی، ابن حزم، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن عربی اور شاہ ولی اللہ جیسی صرف چند نمایاں شخصیات پر اگر اس حوالے سے قلم اٹھایا جائے تو ضخیم مجلدات تیار ہو سکتی ہیں۔
اس لیے میرے خیال میں تجدد اور تجدید میں تفریق کے لیے چند اصولی نکات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے:
٭ پہلی بات یہ ہے کہ تفرد ایک الگ چیز ہے اور تجدد دوسری چیز۔ مختلف علمی مسائل میں چاہے وہ فقہی و کلامی ہو یا کسی اور نوعیت کے، جمہور سے اختلاف کی روایت ہماری فکری روایت کا حصہ رہی ہے۔ اس کو کبھی انحراف وضلالت تصور نہیں کیا گیا اور ان پر ہمیشہ علمی و فکری دائرے میں بحث و مکالمہ جاری رہا ہے۔ اسلامی فکری روایت کی تشکیل میں اس نے اہم رول ادا کیا ہے ۔اس معنی میں تجدد کی یہ شکل روایت کی توسیع کی ہی ایک شکل ہے۔ کیوں کہ روایت کوئی متحجر شے نہیں ہے۔ بلکہ وہ متحرک فکری تسلسل کا نام ہے۔ روایت کی بقا اور معنویت اسی فکری تحرک و تسلسل سے عبارت ہے۔
٭جمہور یا اسلام کی متوارث فکر سے اختلاف کی ایک دوسری شکل وہ ہے جس کا تعلق دین کے فہم و استنباط اور تفہیم و تعبیر کے اصول و کلیات سے ہے۔ کیا اس میں کوئی اختلاف و تغیر ممکن ہے یا یہ تصور کرنا ایک ایمانی تقاضا ہے کہ اس کے جو اصول و کلیات اور معیارات اسلاف نے طے کر دیے ہیں ان سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا؟ یہ ایک گہرا سوال ہے ۔سیکولر اور جدیدیت پسند مستغربین پر مشتمل اہل علم و قلم کا طبقہ نئی عمارت کے لیے نئی بنیاد سازی کی وکالت کرتا ہے، جس کے نمائندگان شرق و غرب کی دانش گاہوں اور علمی حلقوں میں پھیلے ہوئے ہیں جبکہ دوسرا طبقہ وہ ہے جو قدیم بنیاد پر ہی نئی عمارت اٹھانے کی اصولی فکر رکھتا ہے ۔تاہم وہ یہ تصور رکھتا ہے کہ دین کی اصول و کلیات کا وہ حصہ جو وحی سے ماخوذ ہے اور اس میں کوئی بڑا اور قابل ذکر اختلاف نہیں پایا جاتا، اسے تو جوں کا تو قبول کرنا چاہیے، لیکن وہ حصہ جو قرآن و سنت کے ہی اصولی فریم ورک میں انسانی فہم و استنباط پر مبنی ہے، اس میں تجدد اور تغیر دین کا لازمی عصری تقاضا ہے اور یہ خود دین کے مزاج اور اس کی اصولی تعلیمات میں شامل ہیں۔ اس کی ایک مثال مقاصد شریعت کا موضوع ہے جس کے نظریاتی فریم ورک میں سامنے آنے والے کام معرض بحث و تنقید میں رہے ہیں۔
٭ان دو بنیادی نکتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ :اصلا تجدد وہ ہے جس میں دین کی مجموعی تعبیر اور اس کے فہم کا پیمانہ تبدیل ہو جاتا ہو اور دین کے تاریخی فکری تسلسل میں انقطاع کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہو جس کے نتیجے میں دین کا مجموعی فکر و فہم متاثر ہوتا ہو۔ اس سیاق میں بر صغیر سے تعلق رکھنے والے اصحاب علم میں سر سید احمد خاں، غلام احمد پرویز، آصف فیضی اور عنایت اللہ مشرقی جیسی شخصیات کے نام آتے ہیں۔ اس طبقے میں شبلی، ابوالکلام آزاد ،مولانا وحید الدین خان اور جاوید احمد غامدی جیسی شخصیات اور عالم عرب کے حوالے سے جمال الدین افغانی، رشید رضا اور یوسف قرضاوی اور محمد الغزالی وغیرہ کو شمار کرنا درست نہیں ہے۔ہر چند کے ان میں سے سبھوں کے یہاں شاذ و متفرد اقوال و آراء پائی جاتی ہیں، لیکن جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، یہ اقوال و مواقف فہم و تعبیر دین کے مجموعی اور کلی فریم ورک کے داخلی دروبست سے ہی تعلق رکھتے ہیں نہ کہ ان کی حیثیت خارجی اضافات کی ہے۔
خلاصہ یہ کہ تجدید کا تعلق دینی فکرکی توسیع، اس کے جدید انطباق اور تشکیل سے ہے، جب کہ تجدد دینی فکر کی تخلیق و ایجاد سے تعلق رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کے ساتھ مکمل وفاداری اور اخلاص کے ساتھ ،تعبیر دین کے مجموعی فریم ورک میں رہتے ہوئے انجام دیے جانے والے ان اعمال کو بھی جن پر ڈھیلے ڈھالے انداز میں تجدد کا اطلاق کردیا جاتا ہے، اصلا تجدید کے زمرے میں ہی شمار ہوتے ہیں۔


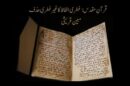
















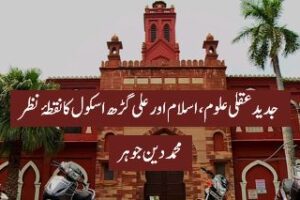
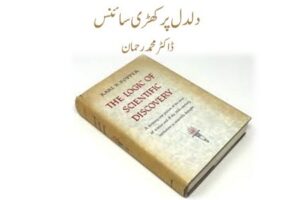
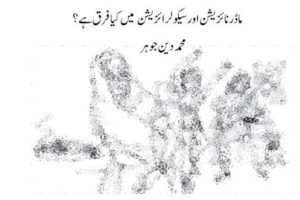
کمنت کیجے