ڈاکٹر زاہد مغل
امام اشعری (م 324 ھ) کی چند عبارات کو لے کر بعض دوست جس طرح خلط مبحث کرتے ہوئے امام صاحب کے موقف کو علامہ ابن تیمیہ (م 728 ھ) کے موقف کے ساتھ ملاتے ہیں ، پچھلی تحریر میں اس کی غلطی واضح کی گئی۔ دراصل یہ دوست متکلمین کی اصطلاحات سے سہو نظر کرتے ہوئے عبارات میں الفاظ کے اضافے کرکے اپنے موقف کے مطابق مفاہیم پیدا کرتے ہوئے یہ تاثر قائم کراتے ہیں کہ اسلاف کا موقف ان کے موقف کے مطابق تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ متکلمین جب “ید بلا کیف” کہتے ہیں تو اس کا مطلب “کیف کی نفی” ہوتا ہے نہ کہ “کیف کے علم کی نفی” (اس فرق کی تفصیل کے لئے امام اشعری کے موقف پر ہماری تحریر ملاحظہ کیجئے)۔ مزید یہ کہ یہ دوست واضح ہی نہیں کرتے کی آخر “کیف” کسے کہتے ہیں جبکہ متکلمین واضح طور پر اس سے چند چیزیں مراد لیتے ہیں جن میں سے ہر ایک فنی اصطلاح ہے نہ کہ عامیانہ الفاظ۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ دوست “الاستوی معلوم” کی ترکیب میں لفظ معلوم کے ساتھ اپنی جانب سے “حقیقی معنی معلوم” کا سابقہ لگا کر اسے اپنے موقف کی ترجمانی فرض کرلیتے ہیں جبکہ امام مالک کے قول میں دور دور تک “حقیقی معنی معلوم” کا کوئی ذکر نہیں۔ ائمہ ان امور کی اصل نص میں مذکور ہونے کی بنیاد پر انہیں بطور صفات الہیہ ثابت مانتے ہیں اور یہی ان کی عبارت میں “معلوم ہونے” کا مطلب ہے۔ بعینہہ اسی قسم کا استدلال یہ دوست امام ابوحنیفہ (م 150 ھ) کی جانب منسوب کتاب “الفقہ الاکبر” کی بعض عبارات سے بھی کرتے ہیں۔ ایک مشہور عبارت یہ ہے:
وَله يَد وَوجه وَنَفس كَمَا ذكره الله تَعَالَى فِي الْقُرْآن فَمَا ذكره الله تَعَالَى فِي الْقُرْآن من ذكر الْوَجْه وَالْيَد وَالنَّفس فَهُوَ لَهُ صِفَات بِلَا كَيفَ وَلَا يُقَال إِن يَده قدرته اَوْ نعْمَته لِأَن فِيهِ إبِْطَال الصّفة وَهُوَ قَول أهل الْقدر والاعتزال وَلَكِن يَده صفته بِلَا كَيفَ وغضبه وَرضَاهُ صفتان من صِفَات الله تَعَالَى بِلَا كَيفَ
مفہوم: اس کا ید، وجہ اور نفس ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، پس اللہ نے قرآن میں وجہ، ید اور نفس کا جو ذکر کیا وہ اس کی “صفات بلا کیف “ہیں، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا ید اس کی قدرت یا (عطائے) نعمت ہے کیونکہ اس سے اس کی صفت کا انکار لازم آتا ہے اور یہ اہل قدر و اعتزال کا قول ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس کا ید اس کی “صفت بلا کیف” ہے، اسی طرح اس کا غضب و رضا اس کی “صفات بلا کیف” ہیں
امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان امور کا صفات الہیہ ہونا ہم مانتے ہیں اس لئے کہ یہ قرآن سے ثابت ہیں نیز ان کی تاویل نہیں کی جائے گی، لیکن ہم سمجھ نہیں پائے کہ آخر اس عبارت میں وہ کونسا لفظ ہے جو “حقیقی معنی معلوم” کا ان کا مفہوم پیدا کررہا ہے؟ عبارت میں صاف طور پر “کیف کی نفی” کی گئی ہے اور کیف کی نفی کس چیز کو کہتے ہیں یہ ہم پچھلی تحریر میں واضح کرچکے ہیں۔ ان دوستوں کی غلطی یہ ہے کہ یہ “ید بلا کیف” کا مطلب “ید بلا علم کیف” فرض کرلیتے ہیں۔ الغرض اس نوع کے جتنے اقوال ہیں وہ علامہ ابن تیمیہ کے موقف کے مطابق نہیں بلکہ صراحتاً ان کی نفی کرتے ہیں اور ایسا اس لئے ہے کیونکہ اسلاف تفویض مطلق کے قائل تھے۔
مثال سے وضاحت
چونکہ علم کلام کی بحثیں سمجھنا اکثر لوگوں کے لئے مشکل ہے لہذا آسانی پیدا کرنے کے لئے ایک مثال سے بات سمجھتے ہیں کہ متکلمین “کیف” کسے کہتے ہیں نیز علامہ ابن تیمیہ کا موقف کیونکر غیر معقول باتوں پر مبنی ہے۔
• گائے، کار اور درخت کا تصور کیجئے۔ ان میں بہت سے امور مختلف ہیں، مثلا یہ کہ گائے کے سینگ ہیں، چار ٹانگیں ہیں، گوشت ہے، رنگ ہے، خاص وزن ہے وغیرہ ؛ اس کے برعکس درخت میں چھال ہے، پتے ہیں، اونچائی ہے وغیرہ لیکن نہ اس میں گوشت ہے اور نہ سینگ اور نہ کھال وغیرہ؛ اس کے برعکس کار کے پہیے ہیں نہ کہ ٹانگیں، اس میں سٹیل ہے نہ کہ گوشت وغیرہ۔ کیا ان میں کچھ مشترک بھی ہے؟ جی ہاں، مثلا رنگ، کمیت، مقدار، طول و عرض، خاص قسم کی وضع (یعنی اعضا کی ایک دوسرے کے ساتھ نسبت سے جنم لینے والی ھیئات)، مکانی مقام میں اور زمانی ساعت میں پایا جانا۔ یہ “امور عامہ” ہیں، اگر آپ ان تین کے سوا دیگر چیزوں کا تصور کریں مثلاً ہاتھ، کرسی، میز وغیرہ تو یہ امور انہیں بھی گھیرے ہوئے ہیں (ضروری نہیں کہ مشاہدے میں آسکنے والی ہر شے میں یہ سب امور موجود ہوں لیکن کچھ ضرور ہوں گے)۔ ان امور کو آپ زمان و مکان سے متعلق مشاہدے میں آنے والی موجودات کی upper tips سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے سب امور کو گھیر رکھا ہے۔ انہی امور کو متکلمین کسی شے کے ہونے کی کیفیات یا کیف کہتے ہیں۔
• ہاتھ، گائے، کار اور درخت سب اجسام ہیں، کچھ مزید باریکی میں اتر کر سوچیں تو معلوم ہوگا کہ ہر جسم مختلف اجزا سے مل کر بنا ہے اور ہر مجموعے کے چھوٹے سے چھوٹے قابل تصور جزو جو مکان گھیرے اسے جوھر کہتے ہیں۔ یعنی گائے، کار، درخت، ہاتھ سب کی آخری یا اوپری tip مکان و زمان ہیں۔ چنانچہ متکلمین کی اصطلاح میں جسم کا مطلب گوشت پوست یا خاص صورت و وضع (مثلا پانچ انگلیوں)کا وجود نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب کسی موجود پر زمان و مکان اور اس سے متعلق کیفیات کا اطلاق کرنا ہے جیسے کہ جہت، زمان، مقدار، رنگ وغیرہ۔ اسے اصطلاحاً تجسیم کہتے ہیں۔
• جو شے یا موجود اس اوپری tip سے ماورا ہے اس کے ہونے کی کیفیت کا علم حس و عقل سے ناممکن اور اس لئے ناقابل ہے۔ انسان با معنی طور پر یا کسی موجود پر ان کیفیات کا اطلاق کرسکتا ہے اور یا ان کیفیات سے ماورا کسی موجود کے ہونے کا اثبات کرسکتا ہے، لیکن وہ ماورا موجود کیسا ہے نیز کیا اس پر ان کیفیات سے پرے کسی کیفیت کا اطلاق ہے یہ حس و عقل سے جاننا ناممکن ہے۔
• یہ امور عامہ گائے، درخت، کار و ید (ہاتھ) کی حقیقت میں شامل ہیں۔ انسان ان امور سے ماورا کسی “ید” سے واقف ہے اور نہ ہی مثلا عربی یا اردو زبان میں لفظ “ید” یا “ہاتھ ” کا کوئی ایسا استعمال ہے جو ان کیفیات سے ماورا کسی “ید” سے متعلق اس کا حقیقی معنی ہو۔ انسانوں کے وضع کردہ لفظ “ید” کے حقیقی معنی وہی ہیں جو ید کی حقیقت میں شامل ان امور عامہ سے متعلق ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ عربی زبان میں لفظ ید کا کوئی ایسا “حقیقی معنی” بھی ہے جو ان امور عامہ سے ماورا ید پر لاگو ہے، اسے اپنے دعوے کی دلیل کے لئے کلام عرب سے اس پر استشہاد پیش کرنا ہوگا۔ چنانچہ ایک بامعنی کلام میں یا آپ “ید” کے حقیقی معنی کہہ کر لازما یہ امور عامہ مراد لیں گے اور یا اس کے مجازی معنی مراد لیں گے، ان دو کے علاوہ عربی لغت میں لفظ ید کا کوئی “حقیقی معنی” نہیں، ایسے معنی فرض کرنا خوش فہمی کے سوا کچھ نہیں کیونکہ ایسی گفتگو میں لفظ بول کر آپ قابل فہم بات نہیں کرتے۔ مثلا جب کوئی کہتا ہے کہ خدا کے لئے جہت ثابت ہے مگر وہ جہت ہماری ان جہات سے بالکل مختلف ہے تو اس نے ایسا کوئی قابل فہم جملہ نہیں بولا جس میں لفظ جہت کو اس کے “حقیقی معنی” میں تو استعمال کیا گیا ہو بس کیفیت مجہول ہو۔ اس شخص کا یہ جملہ اسی قدر مبہم ہے جتنا کسی شخص کا یہ کہنا کہ “اس جہت کا معنی ہمیں معلوم نہیں” اس لئے کہ حس و عقل سے متعلق جہت سے ماورا اگر کوئی جہت ہے تو اس کا کوئی تصور و ادراک ہمیں حاصل نہیں۔ اب اس مثال میں آپ اس “ید” کو رکھ لیجئے جو زمان و مکان سے ماورا ہے تو ناقدین متکلمین کی غلطی عین واضح ہوجائے گی۔
• زمان و مکان سے متعلق جو کچھ ہے وہ قطعی طور پر حادث و مخلوق ہے، لہذا یہ ماننا قطعی طور پر لازم ہے کہ ذات باری ان سے ماورا ہے
• ان مقدمات سے یہ واضح ہے کہ لفظ “ید” کے حقیقی معنی کا اقرار ذات باری پر ناممکن ہے، تاہم وحی کی بنیاد پر اس صفت کا ہم اقرار کریں گے۔ اسے ہی “ید بلا کیف” کہتے ہیں۔ ہمارے دوست علم کلام کی اصطلاحات و ابحاث سے سہو نظر کرتے ہوئے عبارات کو من مانے معنی بھی پہناتے ہیں اور ساتھ یہ بھی نہیں بتاتے کہ آخر یہ لوگ “کیف” کسے کہتے ہیں اور اس کی نفی کے بعد “معلوم حقیقی معنی” کیا ہے۔ جب لفظ سے سمجھ آسکنے والی قابل فہم سب سے اوپری سطح (upper tip) کی نفی کردی تو اس کے بعد لفظ کا حقیقی معنی کہاں سے آگیا کیونکہ آپ تو اس کی سب سے اوپری ترین حقیقت کی نفی کرچکے؟ آخر وہ کونسے اہل زبان ہیں جنہوں نے ان اوپری ترین سطح سے ماورا حقائق کو بیان کرنے کے لئے بھی الفاظ ایجاد کئے تھے؟ پس “ید اللہ” میں لفظ ید کے “حقیقی معنی معلوم” فرض کرنے کے لئے اس ید کو زمان و مکان اور اس کی کیفیات کے تحت لانا ہوگا جس کا مطلب خدا کو مخلوق کی صفات سے متصف ماننا ہے، ان کیفیات سے ماورا اس لفظ کا کوئی حقیقی مطلب عربی لغت میں منقول نہیں۔ پھر ان کیفیات کے تحت لاچکنے کے بعد “حقیقی معنی معلوم مگر کیفیت مجہول” ایک متضاد جملے کے سوا کچھ نہیں کیونکہ جو کیفیت معلوم ہے بعینہہ وہ نامعلوم کیسے ہے؟ الغرض اس ید کی کیفیت یا معلوم ہے اور یا مجہول ہے، اگر معلوم (یعنی حقیقی معنی معلوم) ہے تو یہی تجسیم ہے اور اگر نا معلوم ہے تو یہی تفویض مطلق ہے۔ یعنی نفس معاملہ یوں ہے:
• ید بالکیف، ید کے حقیقی معنی
• ید بلا کیف، ید کے حقیقی معنی نا معلوم یا مجہول
ان کے درمیان جو یہ “حقیقی معنی معلوم اور کیفیت مجہول” کا موقف بنایا گیا ہے اس کی کوئی علمی بنیاد نہیں، یہ موقف دراصل ایک ہی بات کی نفی و اثبات کا مجموعہ ہے: “حقیقی معنی معلوم ہے اور حقیقی معنی نا معلوم ہے”، “کیفیت معلوم ہے اور کیفیت نامعلوم ہے”۔
خلاصہ بحث
“ید بلا کیف” کا مطلب ید کے کیف یعنی اس کے حقیقی معنی کے علم کی نفی ہے، ائمہ کے کلام میں اپنی طرف سے الفاظ و معانی داخل کرکے انہیں اپنے موقف کا ہمنوا ثابت کرنے کا جو طریقہ ہمارے دوست اختیار کرتے ہیں وہ درست نہیں۔ جو کوئی “اللہ کے ید” کے حقیقی معنی معلوم ہونے کا مدعی ہے، متکلمین کے نکتہ نگاہ سے یا:
• وہ تجسیم (اور نتیجتاً خدا کے لئے مخلوق کی صفات ماننے) کا قائل ہے
• یا وہ ناقابل فہم و بے معنی بات کررہا ہے مگر اسے اس کا علم نہیں
• یا اس کا موقف وہی ہے جو متکلمین کہتے ہیں
چونکہ یہ دوست تیسری بات کے انکار پر مصر ہیں اور پہلی بات بھی کھل کر نہیں کہتے، لہذا دوسری بات راجح ہے۔


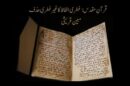















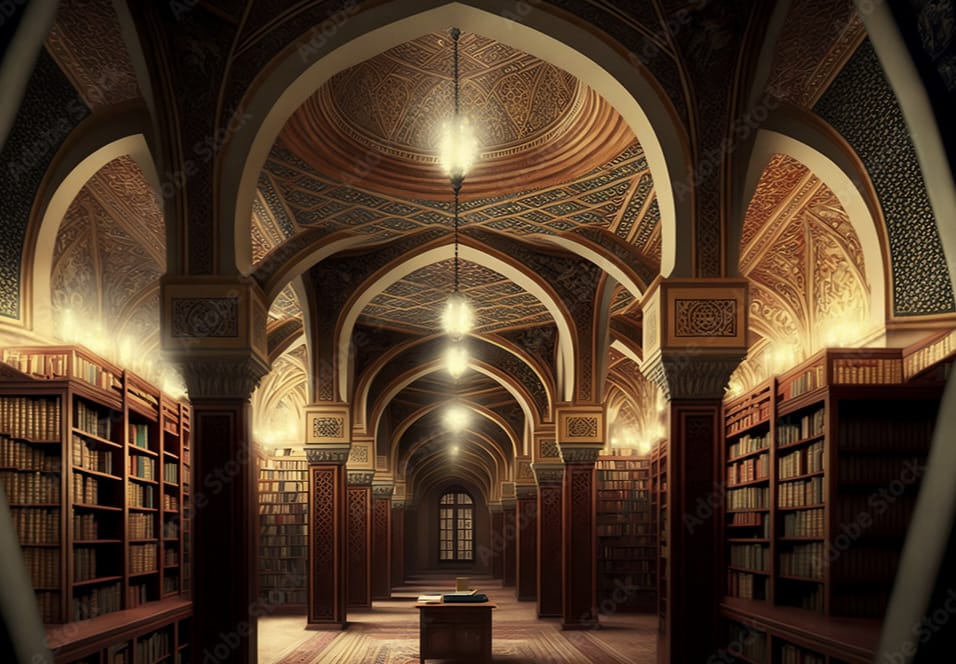
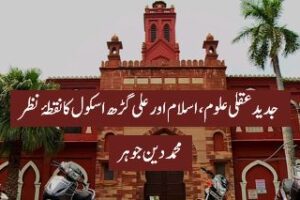
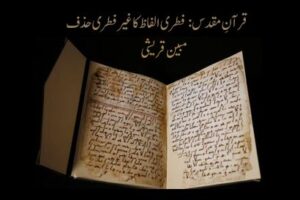

کمنت کیجے