ڈاکٹر راشد شاز کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں ڈاکٹریٹ حاصل کی۔ فکر اسلامی کا احیاء اور اس کی تشکیل نو آپ کے بنیادی موضوعات ہیں۔ جس پر ان کی متعدد کتابیں اور مضامین ہیں۔ ‘کودرا’ بھی اس ہی سلسلے کی ایک اہم کتاب ہے جس میں ڈاکٹر شاز کے خیالات اور فکر سے بخوبی آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ کتاب ہندوستان سے شائع ہوئی ، پاکستان میں اس کو عکس پبلیکیشنز لاہور نے شائع کیا ہے۔
کودرا ایک فرضی سفرنامہ ہے۔ اس کو آپ مصنف کی خودکلامی بھی کہہ سکتے ہیں جہاں وہ مختلف کرداروں کے نام سے خود کلامی کرتے ہیں۔ اس سفرنامے میں ایک جگہ جہاں مختلف مذاہب و اقوام کے لوگ جمع ہیں۔ وہاں پر مصنف علی کودرا نام کے ایک شخص سے ملتے ہیں۔ علی کودرا ایک دلچسپ شخصیت ہیں۔ وہ پہلے مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے جہاں سے وہ سلفی نظریات کے مبلغ بنے۔پھر وہ حوضہ علمیہ قم سے فارغ التحصیل ہیں جہاں سے تشیع کو جاننے کا موقع ملا۔ اب وہ اسلام کی فرقہ وارانہ تعبیر سے کچھ بیزار بھی ہیں مگر کسی وقت اچانک ان کے اندر فرقہ واریت کی رگ پھڑک اٹھتی ہیں۔ پہلے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ غیر شعوری طور پر ہے لیکن یہ باتیں مسئلہ کے تصفیے کے طور پر سامنے آتی ہیں۔
یہ سفرنامہ دراصل مصنف کے اس درد کی ایک روداد ہے کہ مسلمان دنیاوی قیادت سے محروم ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور پھر ان کے حل کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں۔ مصنف اپنے اس دکھ کا اظہار علی کودرا سے کرتے ہیں اور وہاں سے ان دونوں کے درمیان گفتگو شروع ہوتی ہے جس میں مزید کردار جیسے کہ شیخ الحذیفی ، شیخ حسن فولادی اور دیگر اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔
مصنف کے نزدیک مسلم اُمہ کا بحران معاشی نہیں ہے بلکہ فرقہ وارانہ کشیدگی کی وجہ سے ہے۔ مسلمانوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں، اگر وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کرنا چاہیے تو بآسانی کر سکتے ہیں مگر انہوں نے اس میدان کو خالی چھوڑا۔ اس ٹیکنالوجی کے فرق کی وجہ سے ہی مغلیہ سلطنت اور سلطنت عثمانیہ اپنے مخالفین جو کہ تعداد میں بہت کم تھے سے مار کھا گئے.
مصنف نے ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو لوگ دنیاوی قیادت کی ڈرائیونگ سیٹ پر نہ ہو تو ان کے بڑے لوگوں کو دنیا نظر انداز کر دیتی ہے اور ان کو شخصیت اور کام کو اس طرح سے نہیں دیکھتی جیسے وہ اپنے لوگوں کو دیکھتی ہے۔ اس کی کچھ مثالیں بھی ڈاکٹر شاز نے دی ہیں۔ آرٹ اور فن کی دنیا میں ہسپانوی آرٹسٹ پیکاسو کو دنیا جانتی ہے جبکہ البانیہ کے ابراہیم کودرا سے اس طرح واقف نہیں حالانکہ ابراہیم کودرا پیکاسو سے کسی طرح کم نہیں۔ ایسے ہی مارکو پولو ، کولمبس اور وسکو ڈی گاما کی سیاحت کے تو چرچے دنیا بھر میں ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں ابن بطوطہ ، ابن ماجد اور ابن جبیر کی سیاحی مہمات بہت بڑھ کر ہیں۔ دنیا نیلسن منڈیلا کی جدوجہد کو جانتی ہے مگر کوسوو کے آدم دماچی سے ناواقف ہیں جنہوں نے اٹھائیس سال جیل کاٹی۔ اس زوال کا یہ المیہ ہے کہ ہم اپنی عظیم شخصیات کو اہل مغرب کی عینک اور شخصیات کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ یہ کافی حد تک درست بات ہے جب یہ پڑھا تو ذہن میں کرکٹ کی مثال آ گئی۔ کرکٹ میں زمبابوے کی ٹیم میں ہیتھ سٹرہیک اور اینڈی فلاور بہترین کھلاڑی تھے۔ وہ کسی بڑی ٹیم میں ہوتے تو ان کا ٹیلنٹ زیادہ نکھر کر سامنے آتا اور کرکٹ کی تاریخ میں ان کا نام زیادہ اوپر ہوتا مگر چونکہ وہ ایک کمزور ٹیم کے کھلاڑی تھے اس لیے ان کو وہ پذیرائی نہیں مل سکی جیسے ان جتنی یا کم صلاحیت کے ان کھلاڑیوں کو ملیں جو مضبوط ٹیم کا حصہ تھے۔
کتاب میں بوسنیا کی آزادی اور آزادی سے پہلے کے حالات پر گفتگو کی گئی ہے۔ بوسنیائی راہنما عزت بیگووچ کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ عزت بیگووچ سے پہلے میں واقف نہیں تھا مگر یہاں ان کا ذکر دیکھنے کے بعد ان کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی۔ وہ مدبرانہ صلاحیت رکھنے والے مسلم راہنما تھے۔ اس کے ساتھ ایرانی لیڈر امام خمینی کا بھی ذکر ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ان دونوں راہنماؤں نے مسلم قیادت میں نئی روح پھونکنے کی کوشش کی مگر افسوس امام خمینی کے پیروکار اپنے فرقے سے باہر نہیں نکلے۔ جبکہ مصنف کا خیال ہے کہ امام خمینی اس فرقہ وارانہ تقسیم سے اوپر ہو کر سوچ رہے تھے جس کی گواہی ان کے خطبات دیتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں فرقہ وارانہ تعبیر موجود ہے مگر خطبات میں انہوں نے وسعت کا مظاہرہ کیا۔ امام خمینی کے ولایت فقیہ کے نظریے کی بھی مصنف نے تائید کی اور بتایا کہ اس نظریے نے شیعہ مسلک میں جمود کو توڑا اور ان میں ایک تحریک پیدا کی۔ اس کے ساتھ شیعی فکر میں امام خمینی سے پہلے غیبت امام کے بعد شیخ الطائفہ ، محقق الکراکی ، شہید الثانی وغیرہ نے جو اس میں اثر ڈالا اور ان کے اندر تحرک پیدا کیا ان کا ذکر کیا ہے۔مصنف کہتے ہیں امام خمینی نے خلفاء ثلاثہ رضی اللہ عنہم کی خلافت کی تائید کی۔ مگر جس نہج پر خمینی صاحب کی سوچ تھی ان کے بعد متبعین اس کو نہیں اپنا سکے۔ دوسری طرف عزت بیگووچ نے وسیع المشربی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعودیوں کی سلفیت ، ترکوں کے صوفیت اور ایرانیوں کی شیعیت کو تبلیغ کی اجازت دی جس کی وجہ سے بوسنیا میں فرقہ واریت نے جنم لیا۔ جس کی وجہ سے اتحاد امت کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ عزت بیگووچ نے تو فرقہ واریت سے اٹھ کر سوچا مگر اس کا نتیجہ بوسینا کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ بوسینا کے بارے میں مصنف نے بتایا کہ وہ پر ہمیشہ سے حنفی ماتریدی اکثریت میں تھے مگر آزادی کے بعد یہاں پر سربوں کے خلاف جب سعودیہ اور ایران نے مدد کی تو سعودی عرب کے سلفی مبلغین اور ایران کے شیعہ مبلغین بھی یہاں آئے اور یوں مسلمانوں کے درمیان کشیدگی نے جنم لیا۔ معلوم نہیں کہ مصنف کی باتوں میں کتنی سچائی ہے مگر ایرانیوں اور سعودیوں کی پراکسی جنگوں کا تو بہت سے مسلم ملک نشانہ بنے۔ پاکستان بھی اس سے محفوظ نہیں رہا۔ ممکن ہے کہ بوسینا میں بھی یہی صورتحال ہو مگر جس طریقے سے اس فرقہ وارانہ کشیدگی کی تصویر کشی اور اس کے تباہ کن نتائج کو بوسینا کے تناظر میں مصنف نے ذکر کیا ہے اس میں مبالغہ محسوس ہوتا ہے۔ دراصل مصنف اس کی شدت کو بیان کرتے ہوئے خود مبالغہ آرائی کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ مسائل نہیں ہیں مگر جس انداز سے مصنف نے ذکر کیا تو ان کے تجزیے میں کمی ممکن ہے.
مصنف نے کتاب میں سرمایہ دارانہ نظام پر بھی تنقید کی ہے اور جس طرح سماج پر اس کی وجہ سے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نظام میں آپ کو ویسے تو مکمل آزادی ہے کہ آپ کوئی بھی تحریک چلائیں اور آزادی اظہار کی بھی اجازت ہے مگر جیسے ہی آپ کی تنقید یا عمل سے اس نظام کو خطرہ ہو تو یہاں آپ کو خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ سرمایہ داروں کی جانب سے عوام بالخصوص مزدور اور محنت کشوں کے استحصال پر بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کی محنت کا صلہ سرمایہ دار دینے کو تیار نہیں۔ پھر اس نظام میں فلاحی اداروں کا بھی مقصد عوام کی فلاح نہیں بلکہ سرمایہ داروں کا تحفظ ہے کہ وہ عوامی غضب کا نشانہ نہ بنیں۔وہ اپنی دولت میں سے تھوڑا سا حصہ ان فلاحی اداروں کو دیکر مزید دولت کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ جہاں جمہوریت ہے وہاں یہ طبقہ انتخابات پر بھی اثرانداز ہوتا ہے جب یہ مختلف جماعتوں کو فنڈ فراہم کرتے ہیں۔ تاکہ آنے والی حکومت کے ذریعے ایسی پالیسیوں کو ممکن بنایا جا سکے جس سے ان کے سرمائے میں اضافہ ہو سکے۔ حکومتوں کے علاوہ میڈیا پر بھی سرمایہ داروں کا مکمل قبضہ ہے جو اپنے خلاف ایسا بیانیہ کامیاب نہیں بنانے دیتے جس سے ان کو خطرہ ہو۔ وہاں کبھی کبھار اس نظام پر تنقید سننے کو بھی ملتی ہے مگر اس کا مقصد میڈیا کو معتبر بنانے کے لیے ہوتا ہے کہ کسی کو جانبداری کا شک نہ ہو۔
سرمایہ دارانہ نظام پر مصنف نے بہت عمدہ نقد کیا ہے۔ اس نظام نے جو عوام کا استحصال کیا ہے اس کی داستان تو طویل ہے مگر مصنف نے یہاں اختصار کے ساتھ اس کا اصل چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے جو کہ قابل تحسین ہے۔
کتاب کا زیادہ تر حصہ شیعہ سنی کی باہمی کشیدگی اور منافرت پر ہے۔ اس منافرت کی وجوہات پر بورل کاسل میں موجود کردار بہت کھل کر بات کرتے نظر آتے ہیں۔ مصنف کے نزدیک شیعہ اور سنی دونوں اسلام کی اصل سے انحراف پر وجود میں آئے ہیں۔ ان کی اصل دین میں نہیں تاریخ میں ہے۔ شیعہ سنی اختلافات کو سمجھنے کے لیے یہ ایک الگ اور کافی حد تک دلچسپ بحث ہے کہ یہ اختلافات درحقیقت تاریخی ہیں۔ جہاں دونوں فرقے اپنی تعبیر و تشریح کو حتمی سمجھتے ہیں۔
ان دونوں کے مابین کئی نزاعی معاملات جیسے کہ غدیر خم ، واقعہ قرطاس ، بعد از وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت کا قضیہ ، فدک، سیدہ نساء العالمین رضی اللہ عنہا کے گھر جلانے کا شیعہ بیانیہ ، شہادت عثمان رضی اللہ عنہ ، خلافتِ علی رضی اللہ عنہ اور پھر اس کے بعد جمل اور صفین کی جنگیں، مصنف نے جمل کا ذکر نہیں کیا صفین کے بعد نہروان کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد واقعہ کربلاء۔ یہ وہ تمام واقعات ہیں جن کی تعبیر کے بارے میں دونوں فرقوں کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ لہذا مصنف کی یہ بات وزن رکھتی ہے کہ ان اختلافات کی بنیاد تاریخ کی مختلف تعبیرات ہیں.
مصنف نے دونوں مسالک کے کچھ نظریات کو غلط قرار دیا ہے۔ اہلسنت کے ہاں تراویح کو انہوں نے بدعت قرار دیا ہے تو اہل تشیع کے ہاں عزاداری کو بھی دین میں اضافہ اور بدعت قرار دیا ہے۔ کربلاء کی روایات کے بارے میں بھی انہوں نے نقد کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس میں بہت سی باتیں بعد میں شامل کی گئیں۔ کربلاء کے سانحے کے سو سال بعد تک کوئی کتاب موجود نہیں۔
مصنف نے ظہور مہدی اور آمد مسیح کے نظریے کو بھی غلط قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ اہل تشیع کے تصور مہدی اور اہلسنت کے ہاں مجدد والی روایات کو بھی وضعی اور بےبنیاد قرار دیا ہے۔
مصنف نے تبرک و آثار کے بارے میں بھی کلام کیا ہے اور اس بارے میں رائج تصورات اور اس کی تائید کرتی روایات پر بھی سوالیہ نشان اٹھائے ہیں۔ انہوں نے تاریخی جائزہ لیتے ہوئے بتایا ہے کہ تبرکات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور اس کے حق میں روایات گھڑی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی برکت کا مصنف نے ایک نیا نظریہ پیش کیا ہے کہ پانی کی برکت یہ ہے کہ اس سے ہائیڈرو پاور انجن ، ڈیمز ، آب پاشی وغیرہ کے لیے استعمال کرکے پیداوار میں اضافہ کیا جائے۔ مصنف نے جس طرح بہت سی باتوں کو وضعی قرار دیا ہے تو ان کا یہ نظریہ بھی اپنے اندر برکت کا مادہ پرستانہ تصور لیے ہوئے ہے۔اس بات سے انکار نہیں کہ ہمارے ہاں تبرکات کے نام پر کھیل کھیلا جاتا ہے اور لوگوں کا استحصال کیا جاتے اور ان میں ضعیف الاعتقادی کو بھی فروغ کی بھی وجہ ہے مگر برکت کے مکمل تصور کو مسترد کرنا زیادتی ہے۔ ڈاکٹر شاز تصوف کے بھی خلاف ہیں۔ خرقہ پوشی کے اوپر بھی انہوں نے بھرپور تنقید کی ہے۔
شیعہ اور سنی کتب میں کچھ روایات پر بھی ڈاکٹر شاز نے گفتگو کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ اسلام کی روح کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان دونوں فرقوں کی کتب میں احادیث کے نام پر ایسی روایات موجود ہیں جو قرآن مجید کی ثقاہت کو مجروح کرتی ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کے خلاف جہاں شیعہ کتب میں آئمہ کی زبانی روایات موجود ہیں تو سنی کتب میں بھی ایسی روایات پائی جاتی ہیں جس سے قرآن کے محفوظ ہونے پر سوال اٹھتا ہے۔ اس کے ساتھ سبع احراف ، قرآت عشر، رجم کے بارے میں جو احادیث ہے مصنف نے سب کو وضعی قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ سب قرآن مجید کی تقدیس کو مجروح کرتی ہیں۔ مصنف کا یہ اعتراض نیا نہیں ہے۔ اس پر پہلے بھی ہمارے مذہبی لٹریچر میں مباحث موجود ہیں۔ البتہ ایک بات جو محسوس ہوئی کہ ناسخ و منسوخ کی احادیث کو بھی مصنف نے اس ہی سلسلے میں شامل کیا ہے جو کہ ان کے مقدمے کو کمزور کرتی ہے۔
ڈاکٹر شاز نے ایک دلچسپ بات کہی کہ اگر تاریخ کی کتب سے ابو مخنف لوط بن یحیی اور ابوہشام جیسے جھوٹے راویوں کو نکال دیا جائے تو واقعہ کربلاء سمیت بہت سے تاریخی واقعات کی بنیاد پر کھڑی مبالغہ آمیز عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ احادیث میں بھی تشیع کے ہاں سے سلیم بن قیس ہلالی اور سنی کتب سے امام زہری کی روایات کو نکال دیا جائے تو شیعہ سنی نزاع کے اسی فیصد مسائل کھڑے ہی نہ ہوں۔ ڈاکٹر شاز کہتے ہیں کہ زہری کے ضعیف اور ناقابلِ اعتبار ہونے پر خود سنی محدثین اور سلیم کے مجہول ہونے پر شیعہ علماء کی گواہیاں موجود ہیں۔ یہ بات بھی غور طلب ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب میں درج باتوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیت کا جو خاکہ پیش کیا ہے وہ قرآن مجید کی بیان کردہ صفت ‘رحماء بینھم’ کے سراسر متصادم ہے۔ جن شیعہ علماء نے اس کتاب سے برات کا اعلان کیا، ان کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں تصور بالکل مختلف طور پر سامنے آیا۔ جس کی وجہ سے اپنے مکاتب فکر کے حوالے سے ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاں تک زہری کی بات ہے تو ان پر بھی علماء نے تحفظات کا اظہار کیا ہے لیکن ساتھ ہی ایک بڑی جماعت ان کی توثیق بھی کرتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو وہ علماء جن کا زیادہ زور رد تشیع پر رہا ان میں سے اکثر نے زہری پر عدم اعتماد کیا ہے۔ اس کی وجہ کتاب میں بھی موجود ہے کہ دونوں کتابوں میں بہت سی روایات ہیں جو مخالفین کے نظریات کی تائید کرتی ہیں تو سنی کتب میں ایسی روایات میں زیادہ تر کے راوی امام زہری ہیں۔
مصنف مکمل ڈی کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں ، جہاں قرآن کے علاوہ سب کتابوں سے دستبرداری کی بات کرتے ہیں۔ احادیث ،تفسیر، قرآت،اسماء الرجال، فقہ اور تاریخ کی سب کتب کو تلف کرنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ دونوں مسالک کے مابین اختلافات کا حل وحی و عقل کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں بحث طلب ہیں۔
مصنف کی سادگی ہے یا ضرورت سے زائد خوش گمانی کہ تمام کتب کو نظر انداز کرنے کے بعد جو قرآن مجید کا فہم وجود میں آئے گا، اس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ خود جس طرح انہوں نے سورۃ القمر کی پہلی آیت اور واقعہ شق القمر کی جو تفسیر پیش کی ہے، اس سے تو شاید ہی کوئی اتفاق کرے۔
دوسرا چودہ سو سال کے علمی ڈسکورس کی ڈی کنسٹرکشن بھی ایک ناقابلِ عمل حل ہے۔ اس کے بارے میں ہند کے ایک عالم ڈاکٹر ذیشان مصباحی نے خوبصورت تبصرہ کیا کہ یہ بالکل ایسا ہے کہ روڈ ایکسیڈینٹ کو روکنے کے لیے سڑک پر گاڑیاں چلانی ہی بند کر دی جائیں۔ یا پھر یہ ایسی ہی بات ہے کہ طلاق کی شرح کم کرنے کے لیے نکاح پر پابندی لگا دی جائے۔ مصنف ایک خیالی دنیا میں رہتے معلوم ہوتے ہیں جہاں پر کوئی رکاوٹ یا مشکلات نہ ہوں۔ یہ دنیا حقیقت میں کہیں قائم نہیں ہے۔ موجودہ دنیا میں چیلنجز ناگزیر ہیں اور ان سے نمٹنے کا حل یہ نہیں کہ ان کو قبول ہی نہ کیا جائے۔ یقیناً مذہبی لٹریچر میں ایسا مواد موجود ہے جو باعث نزاع ہے۔ اس پر الگ سے گفتگو کی جا سکتی ہے پھر تاریخ کو قرآن اور وحی کی روشنی میں دیکھنے والی بات درست ہے مگر اس کا منہج اور طریقہ کار کیا ہوگا یہ ایک الگ موضوع ہے۔
اختلافات سے انکار نہیں ان کی شدت نے مجموعی طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا یہ بھی درست ہے ان کے تصفیے کی خواہش بھی قابل تحسین ہے۔ مگر یہ تصفیہ ایسے ممکن نہیں جیسے مصنف سوچتے ہیں۔ ہمیں دراصل اختلاف کو برداشت کرنے اور اس کو عناد کی بجائے علمی پیرائے میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو اتفاق کی تو ضرورت ہے لیکن اس سے زیادہ اختلاف کرنے کے طریقہ کار کو جاننے کی ضرورت ہے۔
مصنف جہاں مذہبی لٹریچر سے اس قدر بدظن ہیں کہ اس کو تلف کرنے کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف ان کے حسن ظن کا یہ حال ہے کہ وہ امت کے اجتماعی وجود کی منصوبہ بندی میں نصیری ، قادیانی اور بہائیوں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ تینوں مذاہب اسلام کے بنیادی عقائد عقیدہ توحید اور عقیدہ نبوت کے مسئلہ میں پوری امت سے الگ ہیں۔
ہم مصنف کے درد کو حقیقی درد سمجھتے ہیں۔ وہ واقعی مسلمانوں کے زوال پر رنجیدہ ہیں اور دنیا کی قیادت پر مسلمانوں کو دیکھنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ مگر جو حل انہوں نے تجویز کیے ہیں، وہ کوئی ٹھوس اور قابل عمل حل نہیں ہیں۔ ایک اہم چیز اس ضمن میں جو مصنف نے نظر انداز کی ہے وہ استعمار کا کردار ہے۔ استعمار نے جس طرح سے اپنے مقبوضات جن میں زیادہ تر مسلم اکثریتی علاقے تھے کے وسائل کو لوٹا اور ان کو اپنے ملکوں میں استعمال کیا ہے وہ ایک المناک داستان ہے۔ اس کو جانے بغیر آپ مسلمانوں کے زوال کا مرثیہ مکمل طور پر نہیں بیان کر سکتے۔ مصنف نے اس جانب کوئی بات نہیں کی۔ مصنف سے یہ شکایت اس لیے بھی زیادہ ہے جس طرح سے سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی ہے تو استعمار کا استحصال بھی اس ہی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور یہ ممکن نہیں کہ وہ اس سے ناواقف ہوں اور استعماری قوتوں کے ڈھائے مظالم سے وہ بے خبر ہوں۔
دوسرا جدید ریاست کے قیام کے بعد امت کے اتحاد کی کیا صورتحال ہوگی۔اس پر بھی انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی۔حالانکہ یہ وہ مسئلہ یا چیلنج ہے جو پچھلے تیرہ سو سال میں امت کو درپیش نہیں رہا۔ قومی ریاست کے قیام کے بعد ماسوائے ایک دو ممالک کہ اکثر مسلم ممالک کی دفاعی قوت میں تمام مسالک کا حصہ ہے۔ لہذا اگر مسلکی انتشار ہی امت کے زوال اور اتحاد نہ ہونے کی واحد وجہ ہوتا تو یہ اس کی نفی کر رہا ہے۔ جدید ریاست کے مفادات ہوتے ہیں جن میں مذہب یا مسلکی اختلاف و اتحاد کا کردار بہت کم ہوتا ہے اور ریاستیں ہمیشہ مفادات ہی کو ترجیح دیتی ہیں۔
مصنف کی اس لحاظ سے داد بنتی ہے کہ انہوں نے مسلکی شناخت سے اٹھ کر بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے اخلاص پر بھی ہمیں کوئی شبہ نہیں مگر اس شک سے ڈاکٹر شاز کو میں نہیں نکال سکتا کہ وہ اپنے نکتہ نظر اور فہم کو ہی درست قرار دیتے ہوئے باقیوں کو اس کی پیروی کی دعوت دیتے نظر آتے ہیں۔یہ میرا زوایہ نظر ہے مجھے خوشی ہوگی کہ یہ غلط ہو۔


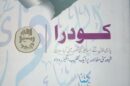
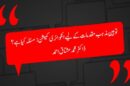
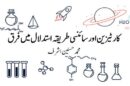
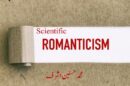

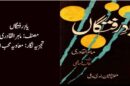


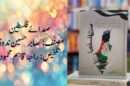






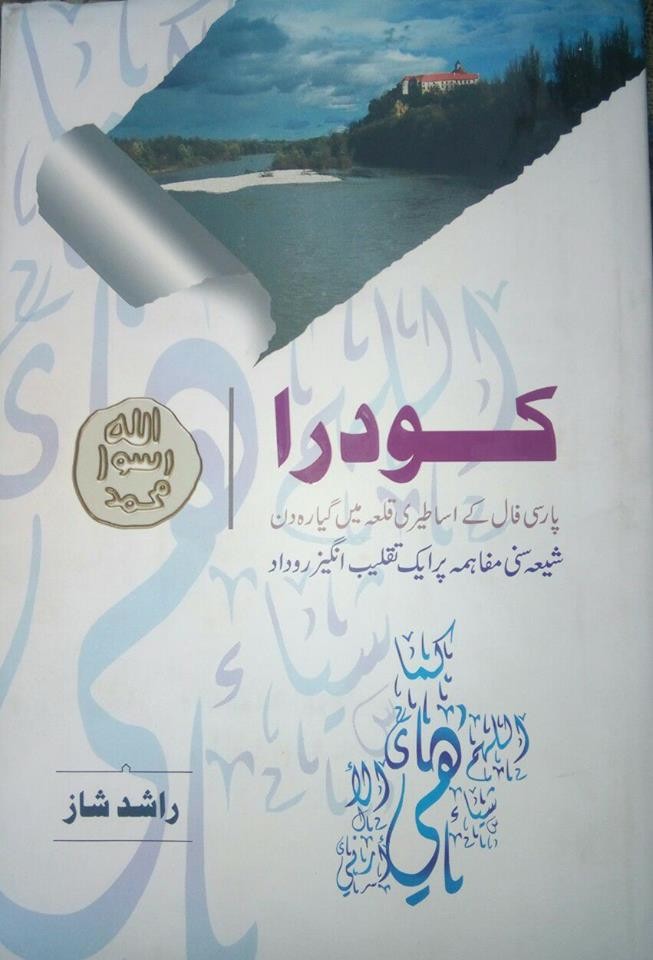
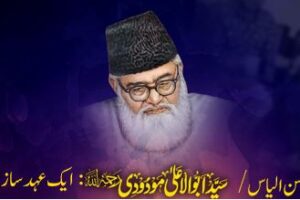
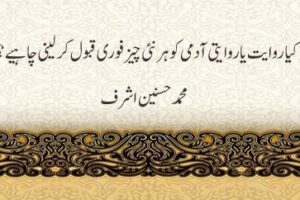
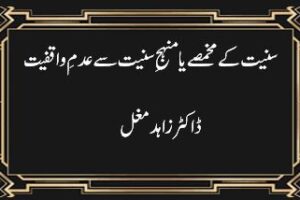
اچھا تبصرہ ہے
بہت شکریہ