
وحید مراد
تہذیبوں میں مذہبی روایت کے ناگزیر کردار پر صرف انبیاء کرام، صوفیاء اور روحانی رہنماؤں نے ہی زور نہیں دیا بلکہ جدید اہلِ فکر نے بھی اس کی گواہی پیش کی ہے۔ جدید مغرب کے بڑے سوشیالوجسٹ، اینتھروپولوجسٹ اور فلسفی اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا کی کوئی تہذیب ایسی نہیں گزری جس میں مذہب ایک بنیادی عنصر کے طور پر موجود نہ رہا ہو۔ چاہے وہ آسٹریلیا کے ابوریجنیز ہوں، افریقہ کے زولو یا امریکہ کے مایا اور ایزٹیک سب کے ہاں الوہیت، روحانیت اور ماورائی ہستی کا تصور کسی نہ کسی شکل میں ضرور پایا گیا ہے اور آج بھی ہر تہذیب میں مذہبی عناصر زندہ ہیں۔ یہ حقیقت واضح کرتی ہے کہ مذہب انسان کی اختراع نہیں بلکہ اس کی فطری طلب ہے؛ ایک ایسی طلب جو معاشرے کو اخلاقی بنیاد اور اجتماعی شناخت فراہم کرتی ہے، ماضی و مستقبل سے متعلق سوالات کے جواب دیتی ہے، انسانی ذہن کے خلا کو پُر کرتی ہے اور بالآخر انسان کو روحانی سکون اور سماجی نظم عطا کرتی ہے۔
اینتھروپولوجی کے بانی ایڈورڈ ٹائلر (Edward Tylor) نے کہا کہ مذہب انسان کا سب سے بنیادی اور لازمی ثقافتی جُز ہے جو ہر تہذیب میں کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا ہے۔ میرچا ایلیادے (Mircea Eliade) اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ انسان اپنی اصل میں ایک مذہبی مخلوق ( Homo Religious) ہے۔ وہ جس دور میں بھی جیے اس کی فطرت اسے ماورائی قوت کی طرف جھکاتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ انسان جو خود کو مذہب سے الگ قرار دیتاہے، اپنے وجود میں معنی اور تقدس کی جستجو سے آزاد نہیں ہوسکتا۔
مشہور مورخ اور فلسفی آرنلڈ ٹوائن بی (Arnold Toynbee) اپنی تحقیقات سے اس نتیجے پر پہنچے کہ ہر تہذیب کی بنیاد کسی نہ کسی مذہب یا اخلاقی روایت پر قائم ہوتی ہے اور جب یہ روایت کمزور پڑتی ہے تو تہذیب بھی زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ ولیم جیمز (William James) نے بتایا کہ مذہبی تجربہ انسان کو وہ سکون اور مقصد عطا کرتا ہے جو نہ عقلِ محض اور نہ سائنسی کامیابیاں دے سکتی ہیں۔ ان کے نزدیک جب انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکتا ہے تو اس کی ذات ایک بلند تر شعور سے جڑ جاتی ہے۔
فریڈرک شلائر ماخر (Friedrich Schleier macher) نے مذہب کو مطلق انحصار (Absolute Dependence) کا احساس قرار دیایعنی جب انسان اپنی محدودیت کو تسلیم کرکے کسی برتر ہستی پر بھروسہ کرتا ہے تو یہی حقیقی مذہبی تجربہ ہے۔ ایمل درکھائم (E. Durkheim) نے مذہب کو ہر معاشرے میں پایا جانے والا ایک سماجی امرِ واقعہ (Social Fact) قرار دیا یعنی یہ انسانی اجتماع کی تخلیق نہیں بلکہ اس کی بنیادی ساخت ہے۔ ماہرِ بشریات میل فورڈ اسپائرو (Melford Spiro) کے مطابق مذہب ایک ہمہ گیر (Universal) انسانی خصوصیت ہے اور کوئی ایسا اجتماعی نظام قائم ہی نہیں رہ سکتا جو مذہب سے یکسر خالی ہو۔
وِکٹر فرانکل (Victor Frankl) نے واضح کیا کہ انسان کی سب سے گہری ضرورت روحانی معنویت ہے، جس کے بغیر انسان ذہنی و اخلاقی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ کارل یونگ (Carl Jung) نے جدید انسان کے روحانی بحران کو اس کی سب سے بڑی بیماری قرار دیا اور کہا کہ اس کی شفا صرف باطن کی دینی اساسات (Religious Archetypes) سے ممکن ہے۔ دوستوفسکی (Dostoevsky) نے اخلاقی بنیادوں کے لیے ماورائی مرجع کی ضرورت پر زور دیا جبکہ البرٹ کامو (Albert Camus) نے اعتراف کیا کہ زندگی کا سب سے بڑا سوال ہی اس کا جواز ہےجو محض مادیت سے کبھی پورا نہیں ہوسکتا۔ یہاں تک کہ فریڈرک نطشے (Friedrich Nietzsche)، جو “خدا کی موت” کا سب سے بڑا داعی سمجھا جاتا ہے، خود اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ خدا کے انکار کے بعد انسان شدید تنہائی اور بے معنویت میں ڈوب جاتا ہے اور مغرب کو اب ایک نئے “خدا” کی تلاش کرناہوگی۔
دہریے اور ملحدین عام طور پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام مذہبی تصورات محض توہم پرستی کی پیداوار ہیں کیونکہ ان کی بنیاد تجرباتی یا سائنسی دلائل پر نہیں ہوتی۔ ان کے نزدیک صرف فلسفہ اور سائنس ہی معتبر ہیں کیونکہ یہ عقل اور مشاہدے پر انحصار کرتے ہیں۔ وہ اصرار کرتے ہیں کہ مذہبی عقائد کو بھی انہی پیمانوں پر پرکھا جائے اور اگر وہ سائنسی معیار پر پورے نہ اتریں تو انہیں رد کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ موقف ایک بنیادی مغالطہ ہے کیونکہ سائنس اور مذہب کا دائرہ کار یکسر مختلف ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں جبکہ مذہب یہ سوال اٹھاتا ہے کہ انسان کیوں زندہ ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے اور موت کے بعد کیا ہوگا۔ یہ دو الگ نوعیت کے سوالات ہیں اور ان کے دلائل کا طریقہ بھی جدا ہے۔
سائنس کے دلائل عقل اور تجربے کے ذریعے شعور کو قائل کرتے ہیں لیکن مذہب کے دلائل محض عقل تک محدود نہیں رہتے؛ وہ انسان کے شعور کے ساتھ ساتھ اس کے ضمیر اور دل کو بھی مخاطب کرتے ہیں۔ فلسفہ اور سائنس انسان کے ذہن کو مطمئن کر لیتے ہیں مگر مذہب دل کو یقین، روح کو سکون اور انسان کو باطنی سرور عطا کرتا ہے۔ جب دل پگھلتا ہے، آنکھ سے آنسو بہتے ہیں یا پیشانی سجدے میں جھکتی ہے تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب مذہبی دلائل اپنی اصل تاثیر ظاہر کرتے ہیں۔
ملحدین یہ بھی کہتے ہیں کہ سائنسی دلائل سب کو تسلیم کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے نتائج ایک ایجاد یا پروڈکٹ کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایجاد کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ کام کرتی ہے جبکہ کسی نظریے یا فلسفے کو ہم تب ہی قبول کرتے ہیں جب وہ ہمارے دل اور ضمیر کو مطمئن کرے۔ اسی لیے سائنس کا مقصد اشیاء پر قابو پانا اور سہولت پیدا کرنا ہے جبکہ مذہب کا مقصد انسان کو اس کی اصل فطرت اور اعلیٰ مقصد سے جوڑنا ہے۔
یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ “عقلی دلیل” بذاتِ خود مطلق معیار نہیں۔ عقل ایک انسانی صلاحیت ہے جو دلائل کو ترتیب دیتی ہے مگر انسان کے فیصلے میں صرف عقل شامل نہیں ہوتی بلکہ ضمیر اور قلب بھی شریک ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بے شمار فلسفیانہ مکاتبِ فکر وجود میں آئے لیکن کوئی ایک فلسفہ ایسا نہیں جو پوری انسانیت کو سکون اور وحدت دے سکے۔ اس کے برعکس، مذہب اپنی دلیل منطق کی خشک زبان سے نہیں بلکہ محبت، شفقت اور رحمت کی زبان سے دیتا ہے۔ وہ دل کو یقین اور روح کو تسلی بخشتا ہے۔
اہلِ فلسفہ کے نزدیک بھی عقل (Reason) محض منطقی مقدمات کا نام نہیں بلکہ ایک ایسا منظم بیان (structured discourse) ہے جو ذہن کو قائل کرتا ہے۔ مگر انسان صرف ذہن نہیں؛ وہ ایک کلّی وجود ہے جس میں دماغ، قلب، ضمیر اور روح سب شامل ہیں۔ امانوئیل کانٹ نے واضح کیا کہ خالص عقل تجربے کی حدود سے باہر نہیں جا سکتی؛ خدا، روح اور ابدیت کو محض محسوسات یا مشاہدے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اخلاقیات اور انسانی ضمیر ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم خدا اور روح کو تسلیم کریں۔ گویا مذہب کا دروازہ “عملی عقل” کے ذریعے کھلتا ہے نہ کہ محض تجرباتی عقل سے۔
ڈیوڈ ہیوم نے اس حقیقت کو مانا کہ عقل بذاتِ خود انسان کو حرکت نہیں دے سکتی۔ عقل راستہ دکھاتی ہے لیکن اصل محرک جذبات اور ضمیر ہوتے ہیں۔ پاسکل کہتے ہیں کہ انسانی ادراک میں دل اور ضمیر ایک ایسا علم فراہم کرتے ہیں جو قیاس اور تجربے کی گرفت میں نہیں آتا۔ مذہب براہِ راست انسانی قلب اور ضمیر پر اثر ڈالتا ہے؛ وہ عقل کے ترازو سے ناپنے کی شے نہیں۔ محض عقل انسان کو قائل نہیں کرتی جب تک دل اور ضمیر اس کی تائید نہ کریں۔
ولیم جیمز نے مذہبی تجربے کو معرفتی قدر (noetic quality) قرار دیا اور کہا کہ یہ علم عطا کرتا ہے جو انسان کو یقین اور معنی بخشتا ہے اور جس کی عملی افادیت زندگی میں ظاہر ہوتی ہے۔ وکٹر فرانکل نے لکھا کہ انسان کی اصل ضرورت خوشی یا طاقت نہیں بلکہ زندگی کی معنویت ہے اور یہ صرف روحانی اقدار سے حاصل ہوتی ہے۔ کارل یونگ کے مطابق مغرب میں ان کے بیشتر مریض اس لیے پریشان تھے کہ وہ اپنی روحانیت سے کٹ گئے تھے۔
جدید سائنس اور نفسیات بھی اسی نتیجے پر پہنچی ہیں کہ اقداری بنیادوں کے بغیر عقل ادھوری ہے۔ انتونیو ڈاماسیو (Antonio Damasio) نے بتایا کہ محض خشک منطق اور مجرد عقل (Pure Reason) فیصلے نہیں کرا سکتی بلکہ جذباتی و اقداری اشارے (somatic markers) بھی ناگزیر ہیں۔ یعنی ہر فیصلہ منطق کے ساتھ ساتھ پچھلے تجربات، جذبات اور جسمانی و دلی کیفیات کے اثرات کے تحت ہوتا ہے۔ جوناتھن ہائٹ (Jonathan Haidt) کے مطابق اخلاقی فیصلے پہلے ضمیر اور فطری بصیرت سے آتے ہیں جبکہ منطقی عقل بعد میں ان کا جواز پیش کرتی ہے۔
اسی تسلسل میں ایلوِن پلانتنگا (Alvin Plantinga) نے وضاحت کی کہ خدا کا وجود، بیرونی دنیا کی حقیقت اور بہت سے بنیادی عقائد اپنی جگہ معقول ہیں اور کسی سائنسی تجربہ گاہ کے محتاج نہیں۔ الیسڈئر مَیک اِنٹائر (Alasdair MacIntyre) نے اس حقیقت پر زور دیا کہ عقل ہمیشہ کسی روایت کے اندر کام کرتی ہے اور مذہبی روایت بھی ایک معقول روایت ہو سکتی ہے جو انسان کو اخلاق، معنی اور غایت فراہم کرتی ہے۔
سائنس کائنات کے “کیا” اور “کیسے” کو بیان کرتی ہے؛ فلسفہ مفاہیم اور اصولوں کی تحلیل کرتا ہے؛ جبکہ مذہب “کیوں” کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تھامس کُن (Thomas Kuhn) نے کہا کہ خود سائنس بھی پیراڈائم کی حدود میں سوچتی ہے اور مائیکل پولانی (Michael Polanyi) نے بیان سے ماورا علم (Tacit Knowledge) کی اہمیت اجاگر کی جو مذہبی تجربے کے دائرے میں آتا ہے۔ ان کے مطابق انسانی علم کا بڑا حصہ اسی پوشیدہ علم پر مشتمل ہے جو زبان اور وضاحت سے ماورا ہوتا ہے لیکن عملی زندگی میں نہایت مؤثر ثابت ہوتا ہے، جیسے سائیکل یا تیراکی میں توازن رکھنا، یا چہرے کے تاثرات اور موڈ کو سمجھنا۔
سورین کیرکیگارڈ (Søren Kierkegaard) نے کہا کہ عقل سوال تو اٹھا سکتی ہے مگر جواب صرف ایمان اور دل سے ملتا ہے۔ وولٹئیر (Voltaire) بھی جو چرچ کا سخت مخالف تھا، آخرکار یہ ماننے پر مجبور ہوا کہ “اگر خدا نہ ہوتا تو ہمیں اسے ایجاد کرنا پڑتا”، کیونکہ انسان اپنی فطرت میں کسی اعلیٰ مقصد اور ماورائی معنی کا محتاج ہے۔
لہٰذا عقل انسان کی عظیم صلاحیت ہے مگر وہ تنہا کافی نہیں۔ عقل راستہ دکھاتی ہے، سائنس سہولت فراہم کرتی ہے، جذبات محرک بنتے ہیں، ضمیر اقدار کا تعین کرتا ہے اور مذہب انسان کو معنی اور غایت بخشتا ہے۔ یہی ہم آہنگی مغربی اور مشرقی دونوں مفکرین نے تسلیم کی مگر دہریے اور ملحدین اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔
مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کی اکثریت منطقی استدلال (Abstract Logical Reasoning) سے واقف ہی نہیں اور نہ انہیں معلوم ہے کہ اسے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ان کی روزمرہ زندگی میں دلائل کا وزن صرف انسانی جذبات اور تعلقات پر ہوتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ خشک عقلی بحث (Dry Rational Debate) کرتے رہتے ہیں وہ بھی حقیقت میں دوسروں کو قائل کرنے کے لیے صرف منطق پر نہیں چلتے بلکہ محبت، پیار، شفقت، نرمی، درخواست، رجھاؤ، رکھاؤ، لجاجت، اعتماد اور کریڈیبلٹی جیسے انسانی اوصاف استعمال کرتے ہیں۔ اکثر لوگ دلیل نہیں بلکہ کسی شخص کے اخلاق، اعتماد، لہجے اور اس کے حوالے (Reference) یا رتبے سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی تاریخ میں بڑے افکار، بڑے مذاہب اور بڑی تحریکیں صرف منطق کی بنیاد پر نہیں بلکہ دلوں کو چھو لینے والی شفقت، محبت اور اخلاقی اتھارٹی کے ذریعے قبول کی گئی ہیں۔ عقل اپنی جگہ ایک قوت ہے لیکن دل کی زبان اور انسانی تعلقات کا اثر زیادہ گہرا اور دیرپا ہے۔


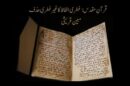















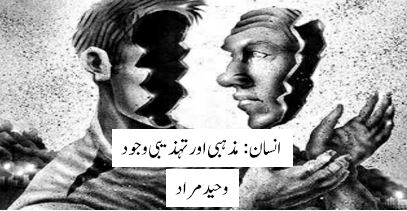
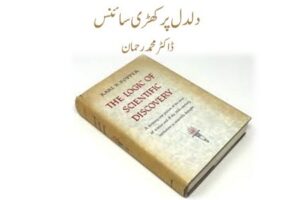
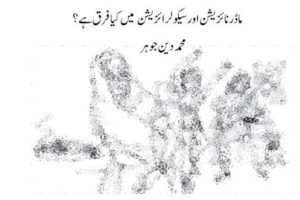

کمنت کیجے