از مولانا محمد علی صدیقی کاندھلویؒ
تحقیق وتخریج: ڈاکٹر انعام الحق غازی/نوید الرحمن داور
مولانا ضیاء الدین سنامی کا زمانہ:
مولانا سنامی اور شیخ المشائخ نظام الدین میں معاصرت ہے۔ مولانا سنامی اگر 641 ھ میں پیدا ہوئے تو شیخ المشائخ636ھ میں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ مولانا سنامی کی وفات اگر 718ھ میں ہے تو شیخ المشائخ کی وفات 725ھ میں ہوئی ہے یعنی شیخ المشائخ مولانا سنامی سے 5 سال پہلے تشریف لائے تو شیخ المشائخ ہی مولانا سنامی سے 7 سال بعد دنیا سے روانہ ہوئے۔ مولانا سنامی نے اپنی ساری زندگی کی بہاروں میں جو سیاسی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں وہ یہ ہیں:
ناصر الدین محمود 644ھ- 664ھ
غیاث الدین بلبن 664ھ-686ھ
معزالدین کیقباد 686ھ-689ھ
جلال الدین فیروز 689ھ-695ھ
شہاب الدین 715ھ-716ھ
قطب الدین مبارک شاہ 716ھ-718ھ
اس طرح مولانا ضیا ء الدین سنامی نے 641ھ سے لے کر 718ھ تک اپنی عمر کی 77 بہاریں دیکھی ہیں۔ یہ زمانہ دو دَوروں کا مجموعہ ہے: ترکی دور ِ حکومت اور خلجی دورِ حکومت۔ ناصر الدین سے کیقباد تک ترکی اور جلال الدین سے قطب الدین مبارک شاہ تک خلجی عہد ہے۔ مولانا سنامی کی عمر 644ھ میں صرف تین سال کی تھی جب سلطان ناصر الدین محمود نے تختِ حکومت کو رونق بخشی۔ اُسی کے زمانے میں مولانا سنامی بچپن اور لڑکپن سے گذر کر جوانی کے دور میں داخل ہوئے۔ سلطان ناصر الدین محمود کا انتقال 664ھ میں ہوا ہے۔ اس وقت مولانا سنامی عمر کی 23 بہاریں دیکھ چکے تھے ا ور وہ جوان تھے۔
ناصر الدین محمود، سلطان شمس الدین التمش کے بعد پہلا طاقت ور بادشاہ ہے جس نے جہاد کی طرف بھرپور توجہ دی۔ اُس زمانہ میں تارتاریوں نے دریائے سندھ عبور کر کے ملتان وغیرہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ ناصر الدین محمود نے ماہِ رجب 644ھ میں لشکر لے کر تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کےلئے دہلی سے کوچ کیا۔ ماہِ ذی قعدہ 644ھ میں دریائے راوی کو عبور کر کے مقامِ سوہدرہ میں قیام کیا اور غیاث الدین بلبن کو فوج دے کر دوآبہ سندھ ساگر کی طرف روانہ کیا۔ غیاث الدین نے تارتاریوں کو مقابلہ کر کے دریائے سندھ کے پار بھگا دیا اور گکھڑوں وغیرہ کو مناسب سزا دے کر منقاد و مطیع بنایا۔ ناصر الدین محمود نے واپس ہو کر نمازِ عید الاضحی جالندھر میں پڑی اور محرم میں دہلی واپس آ گیا۔
ناصر الدین محمود اخلاق وعادات اور مذاق کے اعتبار سے شمس الدین التمش کا عکس تھا۔ مؤرخ ِ فرشتہ کا بیان ہے:
“یہ بادشاہ شجاعت میں اور سخاوت میں اپنے زمانہ میں بے مثل تھا۔ ذاتی مصارف کا بوجھ اس نے کبھی خزانۂ شاہی پر نہ ڈالا۔ اپنے ذاتی مصارف قرآنِ عزیز کی کتابت سے پورے کرتا تھا”[1]۔
نظام الدین احمد[2] مولف طبقات اکبری کا بیان ہے:
“سلطان ناصر الدین محمود ہر سال قرآن شریف اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا۔ اور اُن کا ہی ہدیہ سلطان کے ذاتی خوردو نوش میں صرف ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کے لکھے ہوئے قرآن کو ایک امیر نے معمول سے زیادہ قیمت دے کر لے لیا۔ اُس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ آئندہ سے لکھے ہوئے نسخہ ہائے قرآن کو پوشیدہ طریقہ پر ہدیہ کیا جائے”[3]۔
منتخب التواریخ میں بدایونی کا بیان ہے:
“عجیب و غریب واقعات جو خلفائے راشدین کے حالات سے مشابہ ہیں ، ناصر الدین محمود کے بارے میں منقول ہیں”[4]۔
علامہ منہاج سراج نے طبقاتِ ناصری میں اُن کا چہرہ اس طرح پیش کیا ہے:
“اللہ تعالی نے اِس بادشاہ کی ذاتِ معظم اور جسمِ مبارک میں اولیاء کے اوصاف اور انبیاء کے اخلاق امانت رکھے تھے۔ تقوی، دینداری، زہد، برائیوں سے حفاظت، شفقت و رحمت، احسان و عدل، انعام و مکرمت، حیا، صاف دلی اور پاک طینتی، ثابت قدمی اور وقار، روزہ داری اور شب بیداری، تلاوت اور سخاوت، کم ازاری انصاف اور بردباری، علماء سے محبت، مشائخ سے دوستی، حلم اور دوسری پسندیدہ خصلتیں۔ نیز سلطنت اور ملک داری کے لئے جو خاص چیزیں ضروری ہیں وہ بھی موجود تھے”[5]۔
ضیاء الدین برنی نے تاریخِ فیروز شاہی میں اور میر خورد نے سیر الاولیاء میں اُن کا پُرشوکت انداز میں چہرہ پیش کیا ہے۔ مولانا عبد الحی نے نزہۃ الخواطر میں جس انداز میں ناصر الدین کا چہرہ پیش کیا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے:
“عادل فاضل بادشاہ خلفائے راشدین کا نمونہ تھا۔ التمش کی اولاد میں اگرچہ سب سے چھوٹا تھا مگر صلاح و فضل میں سب سے بڑا تھا۔ 644ھ میں برسر آرائے حکومت ہوا۔ ظلم کا نام و نشان مٹا دیا اور عدل و کرم کا پورے ملک میں آوازہ بلند ہو گیا۔ یہ بادشاہ عاد ل فاضل، متقی، عبادت گزار، حلم و وفا کا مجسمہ، زاہدانہ زندگی، خیرات کا دلدادہ۔ ادب و علم سے رغبت کرنے والا، انشا پرداری اور کتابت میں ماہر، پورے بیس سال اِنہی اوصاف کی آغوش میں گذارے”[6]۔
اس تقوی اور کسر ِنفسی کے ساتھ ناصر الدین محمود پر حبِ رسول کا بھی بڑا غلبہ تھا۔ حضور اقدس ﷺ کا نام ِنامی زبان پر لانے میں حد درجہ احترام کرتا تھا ۔ اُس کے ایک ندیمِ خاص کا نام محمد تھا۔ وہ اس کو ہمیشہ اُسی نام سے پکارتا تھا۔ ایک روز محمود نے اُسے تاج الدین کہہ کر آواز دی۔ وہ آیا اور شاہی حکم کی تعمیل کر کے گھر چلا گیا۔ تین روز تک بادشاہ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ بادشاہ نے اُسے گھر سے بلا بھیجا اور اُس سے غیر حاضری کا سبب دریافت کیا تو اُس نے عرض کیا کہ جناب مجھے ہمیشہ میرے نام محمد سے پکارتے تھے، اُس روز خلاف ِعادت مجھ کو تاج الدین کے نام سے پکارا ۔ میں یہ سمجھا کہ میرے سے آپ کو کوئی بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، اس لئے میں نے اپنی صورت نہیں دکھائی اور یہ تین روز میں نے بڑی بے چینی میں گذارے۔ بادشاہ نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم سے بدگمان نہیں ہوں۔ لیکن جب میں نے تاج الدین کہہ کر پکارا تھا اُس وقت میں وضو سے نہ تھا۔ مجھے شرم آئی کہ محمد کا نام وضو کے بغیر لوں[7]۔
یہ تھے سلطان ناصر الدین محمود۔ اُن کی وفات کے وقت مولانا ضیاء الدین سنامی کی عمر 23سال تھی۔ اِس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیمی زمانہ سارا ناصر الدین محمود کا زمانۂ حکومت ہے۔اُس دور میں دہلی میں بڑے بڑے اہلِ علم موجود تھے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ قیاس یہی ہے اُس کے زمانۂ حکومت میں 16 سال کی عمر میں دانشمندی سے فراغت کے بعد سنام سے اپنے والد محمد بن عوض کے پاس چلے گئے ہوں گے جو رضیہ سلطانہ کے زمانے سے حکومت میں مستوفی کے عہدے پر تھے۔ یہ صدر محاسب یا اکاؤنٹنٹ جنرل کا عہدہ تھا اور بہت بڑے علماء کو دیا جاتا تھا۔ دہلی میں والدمحترم کے پاس رہ کر مختلف اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ مولانا سنامی کے سامنے معاشی الجھن کوئی نہ تھی۔ والد کا سایۂ عاطفت تھا اور فارغ البالی تھی۔ اس لئے پورے اطمینان و سکون کے ساتھ تعلیمی منزلیں طے ہو گئیں۔ رہنے کی کوئی پریشانی نہ تھی کیونکہ والد موجود تھے۔
مولانا سنامی بلبن کے زمانے میں:
664ھ سے 686ھ تک بلبن کی حکومت کا زمانہ ہے۔ مولانا ضیاء الدین سنامی نے 33 سال کی عمر سے 45 سال کی عمر کا بہترین حصہ بلبن کی حکومت میں گذارا ہے۔ اِس دور کے علماء پر ضیا الدین برنی کا تبصرہ یہ ہے:
“سلطان بلبن کے عہد میں بہت سے نامور علماء ، جن کو نوادر اساتذہ کہا جا سکتا ہے، موجود تھے اور تدریس کا کام کر رہے تھے۔ اور بہت سے اور اساتذہ ، مفتی اور سربرآوردہ علماء، جو عہدِ شمس کے علماء کے شاگرد تھے یا اُن کی اولاد میں تھے، درس دیتے اور فتاوی کا جواب لکھتے، معتبر سمجھے جاتے تھے۔ یہ سب اساتذہ جن میں سے ہر ایک اس پائے کا تھا کہ اُس سے پوری اقلیم زینت حاصل کر سکتی تھی عہدِ بلبنی کو مزین کیے ہوئے تھے”[8]۔
اس زمانے میں دہلی میں دو دارالعلوم قائم تھے: مدرسہ مغربہ اور مدرسہ ناصریہ۔ اُن میں تفسیر و حدیث کی تعلیم ہوتی تھی۔ تفسیر میں کشاف، ایجاز اور عمدہ التفاسیر، حدیث میں مشارق الانوار، مصباح الدجی، صغانی اور مصابیح السنہ ،فقہ میں ہدایہ، مجمع البحرین، قدوری اور نحو میں ابن الحاجب کافیہ اور زمخشری کی مفصل، ادب میں مقامات ِحریری ، منطق میں قطبی ، کلام میں شرح مواقف اورتمیہد عبد الشکور سالمی۔ تصوف میں قو ت القلوب، رسالہ قشیریہ، مرصاد العباد، لوائح اور طوالع شوق و ذوق سے پڑھی اور پڑھائی جاتی تھیں۔
یہ مدارس اور مساجد میں تعلیم گاہیں صرف علمی گہوارے نہ تھے بلکہ حکومت کی پوری مشینری کے چلانے کے لئے کَل پرزے بنانے کے کارخانے تھے۔ اس سے اس وقت دہلی کی پوری فضا ، خاص طور پر مدرسوں اور مسجدوں میں طلبہ اور علماء کے حلقے قضا، افتاء، احتساب کے تذکروں ، اِن منصبوں پر علماء کی تقرری اور قاضیوں ور مفتیوں کے جاہ و جلال اور دولت و ثروت کے قصوں سے معمور تھے۔ ضیاء الدین برنی نے بلبن کے زمانے کو خیر الاعصار کہا ہے۔ اُس کے دور میں بڑے بڑے علماء و مشائخ سرکاری ملازم کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ مولانا زاہد[9] اور اُن کے ہم خیال علماء حکومت کی ملازمت کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور بالعموم سرکار کے دربار سے گریز کرتے تھے لیکن بلبن کی دینی دلچسپیوں سے متآثر ہو کر کچھ اہم شخصیتیں حکومت سے وابستہ ہو گئیں تھیں۔ اِس سلسلے میں مولانا شمس الدین در مراجی جو شیخ المشائخ اور مولانا سنامی کے اساتذہ میں سے ہیں ، مولانا شمس الدین پانی پتی، حسن سنجری اور شمس دبیر خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔
واقعہ یہ ہے کہ غیاث الدین بلبن کا دورِ حکومت صرف تاریخِ ہند ہی نہیں بلکہ پورے عالمِ اسلام کی تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ جس وقت وہ دہلی کے تخت پر بیٹھا تھا دنیائے اسلام پر مصائب کی گھٹائیں چھا رہیں تھیں۔ تاتاری سیلاب اُمنڈتا آ رہا تھا۔ تباہی اور بربادی کے اس دور میں بلبن ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے نہ صرف ہندوستان کو تاتاریوں کی دستبرد سے محفوظ کیا بلکہ وسطِ ایشیا کے سینکڑوں برگشتہ بخت انسانوں کو اپنے دامن میں پناہ دی۔ اُس کے زمانے میں دہلی اسلامی دنیا کی اُمنگوں کا مرکز بن گیا اور بلبن کی سیاسی بصیرت انتظامی صلاحیت اور دینی دلچسپیوں کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔
بلبن کے زمانے کے علماء:
علماء کے ساتھ بلبن کا برتاؤ عقیدت و احترام کا تھا۔ وہ انتہائی عقیدت کے ساتھ نمازِ جمعہ کے بعد مولانا برہان الدین ( بلخی) کے مکان پر حاضر ہوتا تھا۔ مولانا اپنے زمانے کے متبحر عالم تھے۔ طریقت اور شریعت کا شاہکار تھے۔ مشارق الانوار خود کتاب کے مصنف علامہ حسن صغانی سے پڑھی تھی اور ہدایہ علامہ مرغینانی صاحبِ ہدایہ سے پڑھی تھی۔ صاحبِ ہدایہ علامہ مرغینانی نے جب اُن کو بچپن میں دیکھا تو فرمایا تھا کہ :
“یہ بچہ ایسا بزرگ ہو گا کہ بادشاہ اُس کے دروازے پر آئیں گے”[10]۔
یہ پیش گوئی بلبن کے ذریعے پوری ہوئی۔ شیخ نظام الدین بلخی اُن کے وفورِ علم اور کمال کے مداح تھے۔
بلبن کے زمانے میں علماء میں مندرجہ ذیل خاص طور پر قابل ذکر ہیں:
1۔ مولانا برہان الدین بلخی
2۔ مولانا برہان الدین بزار
3۔ مولانا نجم الدین دمشقی
4۔ مولانا سراج الدین سنجری
5۔ مولانا شرف الدین دلوالجی
6۔ مولانا منہاج الدین جرجانی
7۔ قاضی رفیع الدین گاؤرزنی
8۔ قاضی شمس الدین اوجی
9۔ قاضی رکن الدین سامالی
10۔ قاضی جلال الدین کاشانی
11۔ قاضی سدید الدین
12۔ قاضی ظہیر الدین
13۔ قاضی جلال الدین
اِن میں ہر شخص علم کا ناپیدا کنار سمندر تھا۔ افسوس ہے کہ اُن میں سے بیشتر کے حالات معاصر تذکروں اور تاریخوں میں نہیں ملتے۔ بلبن کو قاضی شرف الدین دلوالجی، مولانا سراج الدین سنجری اور مولانا نجم الدین دمشقی سے خاص عقیدت تھی۔
عبد اللہ یوسف علی اپنی کتاب ہندوستان کے معاشرتی حالات میں لکھتے ہیں کہ:
“اِن کتبوں میں جو سلاطینِ دہلی کے عہدِ حکومت پر روشنی ڈالتے ہیں، آپ کو صرف ایک کتبہ کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ یہ پالم کا کتبہ قلعۂ دہلی کے آثار قدیمہ کی عجائب گاہ میں موجود ہے۔ یہ ایک گاؤں کے کنویں میں نصب تھا جو موجودہ دہلی سے صرف 12 میل کے فاصلے پر ہے”[11]۔
اس کتبہ میں چونکہ بلبن برسرِ حکومت آنے سے پہلے ناصر الدین محمود کا وزیر تھا، اس لئے دونوں کے زمانے کی تعریف کی ہے۔ بلبن کا ذکر اِن لفظوں میں ہے :
“وہ بادشاہ جس کی شاندار اور قابلِ تعریف حکومت میں تمام ملک مطمئن ہے۔ بنگال کے گود شہر سے افغانستان کے شہر غزنی تک اور دکن میں رامیشور تک ہر جگہ ملک اس طرح منور ہو رہا ہے جیسے درختوں کی خوبصورتی سے موسم ِبہار میں زمین مزین ہو جاتی ہے ۔ اور اِس بادشاہ کی خدمت میں متعدد راجے آتے رہتے ہیں ۔ اُن کے منکوں سے گرے ہوئے جواہرات کی چمک دمک پھیل جانے سے سارا ملک جگمگا رہا ہے”[12]۔
بہرحال یہ تھے غیاث الدین بلبن ۔ اُن کا زمانہ لوگوں کے لئے بڑی رحمت تھا۔ اس نے ایک نہایت پرفتن دور میں لوگوں کو آرام و آسائش کی زندگی بہم پہنچائی تھی ۔ جب اس کا جنازہ کو شک محل سے نکالا گیا تو ارکانِ دولت نے رنج و غم سے مغلوب ہو کر اپنے کپڑوں کو پارہ پارہ کر لیا اور ننگے سر جنازے کے پیچھے پیچھے چلے۔ ملک الامراء چھ ماہ تک اور دوسرے اُمراء چالیس روز تک زمین پر سوئے اور ماتم کرتے رہے۔ تمام بزرگانِ شہر نے ایصالِ ثواب کے لئے کھانا تقسیم کیا۔ 686ھ میں اس کی وفات ہوئی۔
مولانا ضیاء الدین نے 662ھ سے لے کر 686ھ تک کا زمانہ غیا ث الدین بلبن کے عہد میں گذارا ہے۔ عمر کا باقی حصہ علاء الدین خلجی اور قطب الدین مبارک کے زمانۂ حکومت میں گذرا۔ علاء الدین کے زمانۂ حکومت کو دہلی کے سیاسی اور تمدنی حالات کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت ہے۔ اُس زمانے میں مسلمانوں کے سیاسی اور روحانی دونوں ادارے ارتقا کی منزلیں طے کر رہے تھے اور مشکلات و مصائب کی ابتدائی منزلوں سے گذرنے کے بعد ایسے مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں اُن کے اثرات و افادیت کا جائزہ صاف طور پر ممکن تھا۔ شمس الدین التمش، ناصر الدین محمود اور غیاث الدین بلبن نے جس عمارت کی بنیادیں استوار کی تھیں، اُس کو علاء الدین نے اپنے حسنِ تدبیر اور صلاحیت ِجہاں بانی سے پایۂ تکمیل کو پہنچا دیا تھا۔ فتوحات اور وسعتِ ملکی کے اعتبار سے بقول شیخ محمد اکرام آئی سی ایس کے:
“ہندوستان کا جتنا علاقہ اُس کے زیرِ نگیں تھا، برطانوی حکومت سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوا”[13]۔
اسلامی ہند کے اُس دور میں حکمرانی کرنے والے علاء الدین خلجی کے مذہبی معتقدات کے بارے میں بے شمار غلطیاں ضیاء الدین برنی مؤرخ نے پھیلا دی ہیں۔ برنی کے علاوہ کسی معاصر مورخ یا تذکرہ نویس نے علاء الدین خلجی کے اسلام سے بے تعلقی کا شکوہ نہیں کیا۔ امیر خسرو نے اس کی اسلام پروری، دینداری اور پاس ِشریعت کے ترانے گائے ہیں۔ مطلع الانوار میں ہے:
شاه محمد كہ بتائید راے کرد قوی شرع رسول خدائے[14]
اپنی مثنوی میں امیر خسرو نے ایک جگہ سلطان کو ایمان پناہ کہا ہے اور لکھا ہے:
قاعدہ ٔ ملک نو بنیاد دین[15]
عصامی محمد بن تغلق کے عہد کا مؤرخ ہےا ور شاعر ہے۔ اس نے اپنی کتاب فتوح السلاطین برنی کی تاریخِ فیروز شاہی سےآٹھ سال پہلے لکھی ہے۔ عصامی نے علاء الدین کے معتقدات کی تعریف کی ہے اور اس کو شاہ ِ دین پرور بتایا ہے۔ لکھا ہے:
بہ عہدش کسے جز غم دین نخورد بہ دورش کس از غم شکایت نکرد
غم خلق می خورد تاز ندہ بود زشاہاں ہمو گوئے عصمت ربود
غرض چوں ہمیں شاہ فیروزقن کہ بودست دین پرور ودوں شکن[16]
امیر حسن عہد ِعلائی کے مشہور شاعر اور بزرگ ہیں۔ اُس نے جگہ جگہ علاء الدین کی دین پروری، دین داری کی تعریف کی ہے اور سلطان کو دین پرور، دین پناہ ، اسلام پرور وغیرہ کے القابات سے مخاطب کیا ہے۔
قاضی ضیاء الدین برنی نے علاء الدین پر الزامات عائد کئے ہیں۔ اُن کے پس منظر میں خود برنی کے اپنے مذہبی رجحانات ، اپنے معتقدات و نظریات کار فرما ہیں۔ برنی کے ذہن میں کچھ معاشرتی تعصبات کام کر رہے ہیں۔ وہ خاندانی نجابت و شرافت کا قائل تھا۔ اُسی ذہنی پستی نے علاء الدین کو اس کی قلم کاری کی عدالت میں ایک ملزم بنا کر رکھ دیا۔
مولانا ضیاء الدین سنامی کے بارے میں خود برنی کا بیان ہے:
“وہ عہد علائی کی ساری مدت وعظ کہتے اور تفسیر بیان کرتے رہے”۔[17]
یہ تھا مولانا ضیاء الدین کا زمانہ۔ اس میں مولانا نے علمی، معاشرتی ، اخلاقی اور احتسابی کام کئے۔
حوالہ جات
[1] ۔ تاریخِ فرشتہ از محمد قاسم فرشتہ، مترجم محمد فدا علی، مطبع جامعہ عثمانیہ، دکن، 1936ء جلد: 1، ص: 431
[2] ۔ مرزاخواجہ نظام الدین احمد ( 1551ء- 1594ء) ہندوستانی مؤرخ تھے۔ اُن کی وجۂ شہرت اُن کی کتاب طبقاتِ اکبری ہے جس میں اُنہیوں نے مغل شہنشاہ اکبر کے عہدِ حکومت تک کی تاریخ بیان کی ہے۔
[3] ۔ طبقات اکبری، خواجہ نظام الدین احمد،ترجمہ وترتیب، محمد ایوب قادری، اردو سائنس بورڈ، لاہور، 1990 ، ص:146
[4] ۔ منتخب التواریخ از عبد القادر بدایونی، مترجم احتشام الدین، منشی نول کشور، لکھنو، ص:340
[5] ۔ طبقاتِ ناصری، منہاج سراج، مترجم غلام رسول مہر، ص: 251
[6] ۔ نزہۃ الخواطر، محولہ بالا، مولانا عبد الحی، ج1، ص: 125
[7] ۔ تاریخِ فرشتہ از محمد قاسم فرشتہ، مترجم محمد فدا علی، مطبع جامعہ عثمانیہ، دکن، 1936ء جلد: 1، ص: 433
[8] ۔ تاریخ فیروز شاہی از ضیاء الدین برنی محولہ بالا ص:346
[9] ۔ مراد مولانا کمال الدین زاہد ہیں جو کہ سلطان المشائخ کے استاذ تھے۔ غیاث الدین بلبن نے اُنہیں اپنے دربار کا حصہ بنانے کے کوشش کی مگر اُنہوں نے سختی سے انکار کر دیا۔ پورے واقعے کے لئے دیکھیئے سیر الالیاء محولہ بالہ ص: 213
[10] ۔ فوائد الفواد ، خواجہ امیر حسن سنجری ، ترجمہ، خواجہ حسن ثانی نظامی، اُردو اکادمی، دہلی ،1990ء ص: 406
[11] تاریخ ہند کے ازمنۂ وسطیٰ میں معاشرتی اور اقتصادی حالات، عبد اللہ یوسف علی، انڈین پریس ، الہ آباد، 1928ء ص: 98۔
[12] تاریخِ ہند کے ازمنۂ وسطیٰ میں معاشرتی اور اقتصادی حالات، محولہ بالاِ ص: 99
[13] ۔ آبِ کوثر، شیخ محمد ٓکرام، ادارہ ثقافتِ اسلامیہِ لاہورِ 1984ء، ص: 146
[14] ۔ مثنوی مطلع الانوار، امیر خسرو، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ، 1926، ص: 30
[15] ۔مثنوی مطلع الانوار، محولہ بالا، ص:30
[16] فتوح السلاطین، امیر حسن عصامی، مدراس یونیورسٹی، مدراس، 1948ء، ص: 303
[17] ۔ تاریخ فیروز شاہی از ضیاء الدین برنی بہ تصحیح سر سید احمد خان، سر سید اکیڈمی، علی گڑھ، 2005ء ص:289



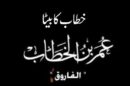



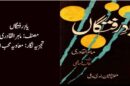


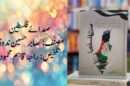










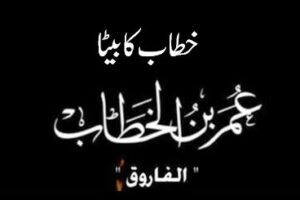
کمنت کیجے