
عمران شاہد بھنڈر
میں نے آج سے کوئی پندرہ برس قبل کہیں پڑھا تھا کہ برطانوی فلسفی ڈیوڈ ہیوم نے اٹھارویں صدی میں فلسفہ علت و معلول کے متعلق جو خیالات پیش کیے تھے،وہ گیارہویں صدی میں ایرانی متکلم ابو حامد غزالی پہلے ہی پیش کرچکے تھے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی اور ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ ایک ’موحد‘ اور متشکک کے خیالات ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں ہیوم کو پہلے ہی سرسری طور پر پڑھ چکا تھا، لیکن یہ جاننے کے بعد اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کے علاوہ غزالی کو بھی پڑھنا شروع کیا، بالخصوص ان کی کتاب ”تہافت الفلاسفہ“ میں علت و معلول کی بحث جو مذکورہ کتاب کے سترھویں باب میں کی گئی ہے۔ مقصود ان مماثلتوں اور امتیازات کا سراغ لگانا تھا جو دونوں مفکروں کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ مطالعے کے دوران میرا یہ احساس مزید گہرا ہوتا گیا کہ دونوں مفکرین کے فلسفہ علیت میں صرف ایک مماثلت ہے جب کہ امتیازات بیسیوں ہیں۔ غزالی علیت کی آڑ میں خدا اور معجزات کی تصدیق کرانا چاہتے ہیں، جب کہ ہیوم آغاز سے اختتام تک متشکک ہے۔ وہ محض تجربیت کا متشکک نہیں بلکہ عقل کے تصورات تشکیل دینے کی صلاحیت کا بھی متشکک ہے۔ جیسا کہ ہیوم کہتا ہے کہ ہمارے تمام تر علم کی بنیاد تجربہ ہے (سوائے ریاضی)۔ ہم حسیات کی وساطت سے ارتسامات حاصل کرتے ہیں اور عقل کا کام محض یہ ہے کہ وہ پوری احتیاط سے کام لیتے ہوئے ان ارتسامات کو تصورات میں تبدیل کر دے۔ چونکہ تجربے سے حاصل ہونے والے ارتسامات میں کہیں بھی خدا کا کوئی سراغ نہیں ملتا، اس لیے، ہیوم کے مطابق، عقل کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ماورائے حسیات و تجربہ خود سے تصورات گھڑے۔ ہیوم جب علت و معلول کے مابین نسبت کے بطورِ لزوم ظاہر نہ ہو سکنے کا تجزیہ کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے پیشِ نظر یہی رہتا ہے کہ علت و معلول کے درمیان جو لزوم تجربے میں ظاہر نہیں ہوتا، اس لزوم کو ماورائے تجربہ دریافت نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے قبل کہ ہم ہیوم کے فلسفہ علت کا جائزہ لیں، ضروری ہے کہ پہلے غزالی کے علت و معلول کے بارے میں خیالات کا مختصر جائزہ پیش کر دیا جائے۔ غزالی لکھتے ہیں،
”جو چیز ازروئے عادت سبب مانی جاتی ہے، اور جو مسبب مانی جاتی ہے، ان دو میں اقتران و اتصال یعنی ان کا ساتھ ساتھ ہونا ہمارے نزدیک ضروری نہیں۔ بلکہ ہر دو چیزیں جن میں یہ وہ نہیں، وہ یہ نہیں اور ایک کا اثبات دوسری کے اثبات کو متضمن نہیں، اور نہ ایک کی نفی دوسری کی نفی کو متضمن، تو ان میں ایک کا موجود ہونے سے دوسری کا موجود ہونا لازمی نہیں، اور نہ ہی ایک کے عدم سے دوسری کا عدم لازم۔ جیسے پانی سے سیرابی، کھانے سے سیری، آگ کے چھو جانے سے جلنا، طلوعِ آفتاب سے روشنی، گردن مارنے سے موت، دوا پینے سے شفا و صحت۔۔۔“ (تہافت الفلاسفہ، ص، 417)۔
غزالی کا یہ بیان فلسفیانہ نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی سرشت میں مذہبیت سے بھرپور ہے۔ یعنی غزالی چیزوں کے درمیان ایسی خصوصیات نہیں دیکھتے جو اپنی آزادانہ حیثیت رکھتی ہوں، اور ان خصوصیات کی بنیاد پر مخصوص نتائج پیش کرتی ہوں بلکہ غزالی اشیا میں ”موجود“ خصوصیات کو اشیا سے ماورا تصور کرتے ہیں۔ اس اقتباس سے جو نکتہ پوری قوت سے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اشیا کے درمیان کوئی لازمی رشتہ ہے اور نہ ہی اشیا ایسا کوئی لزوم رکھتی ہیں کہ ایک کے بعد دوسری کی توقع کی جائے۔ بلکہ غزالی کا یہ کہنا حیرانی کا باعث ہے کہ دو اشیا میں تعامل ہو اور وہ مخصوص نتیجہ پیدا نہ کریں۔ مثلاََ اگر پانی پیا ہے تو ممکن ہے کہ پیاس نہ بجھے، آفتاب طلوع ہوا ہے تو ممکن ہے روشنی نہ ہو۔ بنظر غور دیکھیں تو غزالی نے جو مثالیں پیش کی ہیں، ان کو عملی زندگی میں ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اگر وہ یہ ثابت کردیتے کہ پانی پینے سے پیاس نہیں بجھتی، آفتاب کے طلوع ہونے سے فلاں وقت روشنی نہیں ہوئی تو یقیناََ ان کے موقف کو تقویت ملتی۔ اس کے برعکس غزالی نے لفظ ”عادت“ استعمال کر کے اس امر کا اثبات کر لیا ہے کہ عادت کی تشکیل میں مسلسل تکرار کا عمل شامل ہوتا ہے۔ یعنی ہم عادت کی وجہ سے اشیا کے مابین مخصوص نسبتوں کو اس لیے دریافت کرنے لگتے ہیں کہ اشیا اپنا ایک مخصوص تفاعل رکھتی ہیں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا کہ اگر اشیا کے مابین ایسی کوئی نسبت نہیں پائی جاتی کہ وہ تکرار کا باعث بن سکے تو پھر عادت کی تشکیل کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ عادت اس وقت تشکیل پاتی ہے جب اشیا اپنے مخصوص عمل کا اظہار بار بار کرتی ہیں۔ مثلاََ زید پانی اس لیے پیتا ہے کہ اس سے پیاس بجھتی ہے۔ کھانا اس لیے کھاتا ہے کہ اس سے بھوک مٹتی ہے۔ دونوں کے درمیان رشتہ تو ہے لیکن ”لزوم“ موجود نہیں ہے۔ اس عمل کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ غزالی ایک طرف تو اشیا کے درمیان رشتے کے لزوم کے قائل نہیں ہیں، اس پر مستزاد یہ کہ وہ اشیا کی خصوصیات کے بھی منکر ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص پانی پی لیتا ہے تو ضروری نہیں کہ ا س کی پیاس بجھ جائے۔ غزالی کی فکر کا یہ پہلو واضح کر دیتا ہے کہ ان کے ہاں اشیا اپنا آزادانہ وجود اور خصوصیات نہیں رکھتیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اشیا اپنے مخصوص تفاعل کا اظہار نہ کریں۔
غزالی کے برعکس ہیوم چونکہ ایک تجربیت اور تشکیک پسند فلسفی ہے، اس لیے اس کے لیے اس کے اپنے فلسفے کی رو سے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی بھی عمل پر کوئی ”حتمی“ حکم صادر کرے۔ ہیوم یہ ہرگز نہیں کہتا کہ اشیا اپنی خصوصیات نہیں رکھتیں یا اشیا کے درمیان رشتے میں کوئی لزوم نہیں پایا جاتا۔ ہیوم ”تجربیت پسند“ ہونے کے ناتے ایسا کہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پانی پینے سے پیاس نہیں بجھتی، یا آفتاب کے طلوع ہونے سے روشنی نہیں ہوتی۔ ایسا کہنا ہیوم کی تمام تجربیت کی نفی ہوتی۔ ہیوم فقط یہ کہتا ہے کہ علت و معلول کے درمیان جو لزوم پایا جاتا ہے وہ لزوم تجربے میں ظاہر نہیں ہوتا، اور ماورائے تجربہ اس لزوم کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ وجہ اس کی یہ کہ وہ لزوم کسی ارتسام کی صورت میں ہماری عقل تک نہیں پہنچتا کہ عقل اپنی قوت کا استعمال کرکے اس کو تصورات میں تبدیل کر دے۔ غزالی کے پیشِ نظر ایک مربوط و منظم فلسفیانہ فکر کی تشکیل ہرگز نہیں تھی۔ وہ صرف اپنی مرضی سے چند خیالات اخذ کرکے اسے مکمل طور پر مذہب کے سپرد کر دیتے ہیں۔ غزالی کہتے ہیں کہ ”آگ فاعلِ بالطبع ہے فاعلِ مختار نہیں۔“ غزالی مزید کہتے ہیں کہ اگر جلنے کے لیے کوئی چیز تیار ہو تو اس کے باوجود ہم یہ نہیں مانتے کہ اس چیز کو آگ چھوئے اور وہ جل اٹھے۔ غزالی کے نزدیک،
”بلکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ احتراق کا فاعل جو روئی میں سیاہی اور روئی کے اجزا میں پراگندگی پیدا کر دے، اور اسے سوختہ کر دے وہ بلاشرکت غیرے صرف اللہ تعالی ہے، یا تو بہ وساطتِ ملائکہ یا بلاواسطہ۔“ (تہافت، ص،419)۔
واضح رہے کہ غزالی اس نتیجہ تک کسی ’دلیل‘ کی بنیاد پر نہیں پہنچتے ہیں۔یعنی اگر تجربے میں علت ظاہر نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ علت کہیں اور ظاہر ہو جاتی ہے۔یہاں غزالی نے صرف اپنا عقیدہ بیان کیا ہے۔ یہاں ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جب آگ اور روئی میں کوئی لازمی نسبت نہیں ہے تو ملائکہ اور آگ میں لازمی نسبت کی کیا دلیل ہے؟ غزالی کے اس نکتے پر میرا اعتراض یہ ہے کہ جب اشیا کے درمیان کوئی لزوم نہیں پایا جاتا اور نہ ہی ان میں ایسے اوصاف پائے جاتے ہیں تو غزالی کے ذہن میں علت و معلول کا تصور کیسے جنم لیتا ہے؟ یعنی اگر علت و معلول تجربے سے ماخوذ نہیں ہیں تو یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اور اگر ان کا ماخذ تجربہ نہیں ہے تو تجربہ کے بغیر ان کو ماورا پر لاگو کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں کائنات (معلول) کو بنیاد بنا کر ایک ایسا تصور اس سے اخذ کر لیا جاتا ہے جس کی عدم موجودگی کا دعویٰ بھی خود ہی کیا جاتا ہے؟ یہ ایسا تضاد ہے جس کو غزالی کبھی نہ دیکھ پائے۔ غزالی کے برعکس ہیوم چونکہ ایک فلسفی تھا، اس لیے اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ایک مربوط فکر میں کوئی غیر مربوط تصور کو نہ صرف داخل کر دے بلکہ اس تصور کو ہی کائنات کی علت سمجھ لے۔ اگر اشیا کا اندرون تجربے میں ظاہر نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ عقل اس اندرون پر اپنا تصور قائم کر رہی ہے۔ ایک ایسا تصور (علت و معلول) جس کی تجربے میں تو تصدیق ممکن نہیں ہے لیکن اسے ماورائے تجربہ کسی ”ہستی“ سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ ہیوم یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہم شعلے اور حرارت کے درمیان تعلق کی حقیقت کو نہیں جانتے، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی لاعلمی کو عقیدے سے ڈھانپ لیا جائے۔اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ ہیوم متکلمین کے اس طرح کے دعوؤں سے آگاہ تھا۔ ہیوم لکھتا ہے،
”بہت سے فلسفی اپنی عقل کو مجبور پاتے ہیں کہ بالاستثنا تمام واقعات عالم کا مبدہ اسی ذات کو قرار دیں جس کی طرف عوام صرف معجزات اور فوق الفطرت واقعات و حوادث کے ظہور کو منسوب کرتے ہیں۔ وہ عقل و ذہن کو اشیا کی صرف انتہائی علت ہی نہیں مانتے بلکہ ان کے نزدیک عالمِ فطرت کا ہر واقعہ براہِ راست صرف اسی عقل کا معلول ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو عام طور پر علت کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے ان کی حیثیت صرف ان مواقع (occasions) کی ہے جن پر کوئی واقعہ ظاہر ہوتا ہے، ورنہ کسی معلول کی واقعی و بالذات علت عالم فطرت کی کوئی قوت نہیں بلکہ ایک ہستی برتر کا یہ ارادہ ہے کہ فلاں چیز ہمیشہ فلاں چیز کے ساتھ وابستہ رہے۔ بیلیئرڈ کی ایک گیند دوسری کو اس قوت سے حرکت دیتی ہے جو صانع فطرت نے اس کے اندر ودیعت کی ہوتی ہے۔وہ یوں تعبیر کرتے ہیں کہ جب پہلی گیند دوسری سے ٹکراتی ہے تو اس موقع پر خود خدا اپنے ارادہ خاص سے اس کو متحرک کر دیتا ہے۔“ (فہمِ انسانی، ص، 99)۔
مذکورہ بالا اقتباس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہیوم متکلمین کے خیالات سے بہت اچھی طرح سے آگاہ تھا اور اُن کے اِن خیالات کو اُن کے اپنے ہی خلاف استدلال کے طور پر پیش کرتا تھا۔ متکلمین کائنات کے مشاہدے سے جو”صفات“ اخذ کرتے ہیں، کائنات کو سب سے پہلے ان صفات سے محروم کرتے ہیں، اور کائنات میں موجود صفات کو مستعار لے کر ماورائے کائنات ایک ’ہستی‘ سے منسوب کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کائنات میں موجود صفات اس کی اپنی نہیں ہیں بلکہ خدائی ارادے سے اس میں ودیعت کی گئی ہیں۔ وہ اس اہم ترین نکتے کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جو صفات (علت و معلول، لزوم وغیرہ)تجربے میں ظاہر نہ ہوں ان کا ماورائے تجربہ، منطقی انداز میں اطلاق، محض ایک واہمہ ہے۔ یعنی ہر شے کو اس کی صفات سے محروم کر کے ان صفات کا ماخذ کسی اور”ہستی“ کو قرار دے دیا جائے جب کہ اس ”ہستی“ اور اشیا کے مابین نسبت بطورِ لزوم خود کو ظاہر نہ کرتی ہو۔ہیوم سوال اٹھاتا ہے کہ اگر ایک گیند کو چھڑی ماری جائے اور وہ گیند دوسری گیند سے ٹکرا کر اس میں حرکت کو پیدا کرتی ہے، کیا یہ مشاہدہ اس مشاہدے سے زیادہ عسیر الفہم ہے کہ وہ حرکت کسی ”ہستی“ نے پیدا کی ہے؟ اگر ان دونوں قضایا کو سمجھنا ہو تو کس کو سمجھنا آسان ہے؟ بلاشبہ چھڑی سے گیند کی حرکت کو سمجھنا آسان ہے جب کہ کسی ہستی کا گیند کو حرکت دینے کا تصور ناقابلِ فہم ہے۔ غزالی چونکہ ایک مذہبی پس منظر رکھتے تھے، اس لیے اس قسم کی معجزاتی دنیا میں رہنا اور معجزات کی توقع رکھنا ان کے لیے معمولی بات تھی، لیکن اگر یہی مثال ان لوگوں کے سامنے رکھی جائے جو کسی مذہب اور ”مطلق ہستی“ کی موجودگی پر یقین نہیں رکھتے وہ کبھی بھی اس قسم کا مہمل نتیجہ اخذ نہیں کریں گے۔ ہیوم کے لیے کسی ”مطلق ہستی“ کا تصور کرنا اور اس ہستی سے تمام تر طاقت کو منسوب کرنا واہموں کی دنیا میں پناہ لینے کے مترادف ہے۔ یہ تجربے سے واضح ہوتا ہے اور نہ ہی عقل اس کو ثابت کر سکتی ہے۔ دراصل، متکلمین جو منہج بروئے کار لاتے ہیں اسے ”تقلیبی منہج“ کہتے ہیں۔ یعنی کائنات اور انسان سے صفات اخذ کر کے انہیں خدائی صفات قرار دے دیا جائے اور ان ہی صفات کو خدا کے ارادے کے تابع کر کے دوبارہ انسان اور کائنات کا حصہ بنا دیا جائے، جب کہ حقیقت میں کوئی ایک بھی ایسی صفت نہیں ہے جو باتمام و کمال خدا سے منسوب کی جا سکے۔
ہیوم کے بعد جو اہم ترین نکتہ عیاں ہوا وہ یہی ہے کہ کائنات کی وضاحت کرتے ہوئے کسی بھی ماورائے کائنات تصور سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی۔ اگر اشیا میں لزوم موجود نہیں ہے تو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ لزوم ماورائے اشیا کسی”ہستی“ میں موجود ہے۔ اگر علت تجربے میں ظاہر نہیں ہوتی تو وہ ماورائے تجربہ بھی ظاہر نہیں ہوتی، اس کی صرف منطقی انداز میں توجیہہ پیش کی جاتی ہے اور منطقی درستی حقیقت کا متبادل نہیں ہوتی۔ یہ محض خیال کی صورت ہے، جس میں مافیہا کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ مافیہا کی کمی کو پورا کرنے کے لیے منطق سے دست بردار ہو کر دوبارہ کائنات کی صفات پر غور کرنا پڑتا ہے تاکہ جو نتائج پیش کیے گئے ہیں انہیں کوئی ٹھوس بنیاد فراہم کی جا سکے۔ منطق صورت کے اعتبار سے تو درست ہوسکتی ہے، تاہم جب تک اس میں مافیہا موجود نہ ہو، اس کی حیثیت محض خیال کی درستی تک محدود ہو گی۔
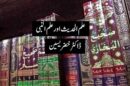
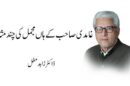
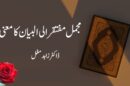







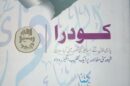






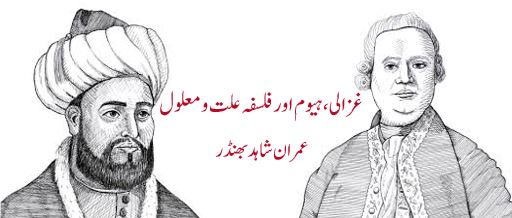
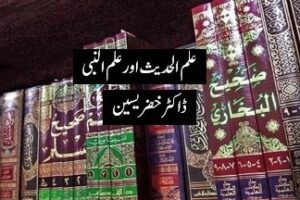

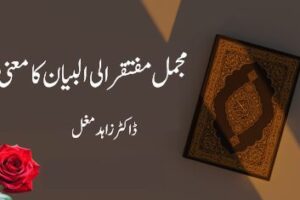
کمنت کیجے