میں نے ۳۱/جولائی اور ۴/اگست کو دو پوسٹیں تحریر کی تھیں جن میں مذہبی تجدد کو موضوع بناتے ہوئے نہایت مختصراً محترم غامدی صاحب کے کام، اس کی ’اہمیت‘ اور اس کام کی قبولیت عامہ کو موضوع بنایا تھا۔ اس پر حسبِ سابق محترم ڈاکٹر محمد امین صاحب بگڑ بیٹھے اور بالکل ناجائز طور پر مجھے تجدد کی مقبولیت کا ”جعلی پروپیگنڈا“ کرنے والا اور محترم غامدی صاحب کے تجدد کا ”حامی“ وغیرہ وغیرہ قرار دیا۔ میری دونوں تحریریں ایک طرح کی ”رپورٹنگ“ یا رپورتاژ تھا جس میں صورتِ مسئلہ کو معروضی طور پر، یا اگر آپ چاہیں تو غیرجانبدارانہ طور پر بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ کسی بھی موضوع پر علمی گفتگو کے لیے اول صورتِ مسئلہ معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے ورنہ ایسی ہر سرگرمی لاحاصل رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ صورتِ مسئلہ بیان کرنے والی تحریر اور حمایت کے لیے لکھی جانے والی تحریر باہم مختلف ہوتی ہیں، اور اس فرق کو بالکل ہی نظرانداز کر دیا گیا۔ اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ تجدد کا ناقد اور مخالف ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم تو تجدد کے مقر اور حامی ہو، تو یہ نہ صرف علم اور مکالمے کی موت ہے بلکہ تہذیب کی موت بھی ہے۔ محترم ڈاکٹر محمد امین صاحب چونکہ لٹھ اٹھائے، گُتکائی فراٹوں میں بگولا آسا، افتائی للکار میں شعلے اگلتے، سو ”مقتدر علما“ کی والہانہ قیادت کرتے ہوئے جناب عمار خان ناصر پر دھاوا زن تھے اس لیے ناچیز کی گزارشات پر ضروری اعتنا بھی نہیں فرما سکے اور ناچیز کو بلاوجہ ”رگڑ“ دیا۔ لیکن کیا کریں اک عرض تمنا ہے سو کرتے رہیں گے۔ ذیل میں صورت مسئلہ کو پھر سے عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا مقصد محترم غامدی صاحب کے تجدد کی حمایت بالکل نہیں ہے کیونکہ مجھے نیمے دروں نیمے بروں ان کے تجدد کی حمایت کرنے کا کوئی شوق ہے اور نہ کبھی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ میری مجموعی پوزیشن ہمیشہ تجدد کے خلاف رہی ہے اور میری تحریریں اس پر گواہ ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے مذہبی دانشوران علمی گفتگو میں مذہبی اخلاقیات کو گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ زیر نظر تحریر صورت مسئلہ کا ”علمیانہ“ بیان ہے (کیونکہ ”عالمانہ“ بیان تو قائدِ مقتدران محترم ڈاکٹر محمد امین صاحب ہی فرما سکتے ہیں)۔
بنیادی قضیہ:
بنیادی قضیہ یہ ہے کہ برصغیر میں اٹھارھویں صدی مسلم تہذیب کے بتدریج زوال اور شکست کی صدی ہے، اور جو وسط انیسویں صدی میں مکمل انہدام سے دوچار ہو گئی۔ یہ برصغیر میں سقوطِ غرناطہ کی آمد تھی۔ کسی بھی تہذیب کے زوال، شکست اور انہدام سے تین چیزیں براہ راست متاثر ہوتی ہیں: طاقت اور معیشت کا نظام اور ان کو جواز دینے والے نظریات یعنی روایتِ علم۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ سیاسی طاقت اور معیشت تو منہدم ہو جائیں اور علم کی روایت کو خراش تک نہ آئے۔ یہ تینوں آنول نال سے باہم مربوط اور جڑی ہوتی ہیں۔ طاقت اور معیشت کا زوال و انہدام حسی مشاہدے کی چیز بھی ہیں لیکن زوالِ علم کو ”دیکھنے“ کے لیے بصارت کے ساتھ بصیرت کے لیے رتی بھر دماغ کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ جو کام نئے تاریخی مؤثرات نے مسلم سیاست اور معیشت کے ساتھ کیا عین وہی کام ہماری علمی روایت کے ساتھ بھی ہوا جس کا سب سے اولین مظہر حنفی وہابی مناقشہ ہے جو انیسویں صدی کے آغاز میں ظاہر ہوا اور جس میں مسئلہ توحید پر بہت ہی بڑا نزاع ہوا اور جس نے ہماری علمی روایت کو جڑوں تک ہلا دیا۔ اسے مباحثۂ عظیم ( The Great Debate) کہا جا سکتا ہے اور جو ہماری مابعد علمی روایت کا صورت گر بھی ہے۔ یہ مناقشہ ہماری علمی روایت پر افکارِ جدیدیت کے دباؤ کا براہ راست نتیجہ تھا۔ اس میں بنیادی سوال دو ہی تھے کہ درست توحید یعنی ”صحیح اسلام کیا ہے؟“ اور ”مسلمان کون ہے؟“
تاریخی پس منظر:
اس مناقشے کے چند ایک پہلو قابل غور ہیں۔
اس بحث میں احناف نے اپنے روایتی معقولی وسائل استعمال کیے جو علمیاتی اور ہرمینیاتی تھے جبکہ وہابی صرف جدید ہرمینیاتی وسائل کو بروئے کار لائے۔ احناف علم الکلام، اصول فقہ اور دیگر علوم آلیہ سے لیس ہو کر اس بحث میں شامل ہوئے اور جدید ہرمینیاتی وسائل کے سامنے ان کو شکست فاش ہوئی۔ جدید عہد کے اولین مباحثۂ عظیم میں احناف کی شکست کا ایک فوری نتیجہ یہ ہوا کہ معقولی وسائل اور علوم آلیہ مابعد علمی مباحث سے خارج ہو گئے اور ہمارے زندہ مسائل سے ان کا تعلق مطلقاً ختم ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حصولِ برکت اور ثواب کی حد تک وہ درس نظامی میں شامل رہے اور آج تک ہیں، اور بتدریج معقولات بھی منقول کی طرح کے علوم بن کر رہ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان اصولی/ عقلی اور آلیہ علوم کا ہمارے علمی شعور اور ہمارے تاریخی اور سماجی حالات سے کوئی تعلق ہی باقی نہ رہا۔ ان علوم کے اندراس کا بڑا سبب یہ تھا کہ وہ تمام معقولی اور علوم آلیہ جنھیں لے کر احناف میدان میں اترے تھے اس معرکے میں کام آئے، اور آئندہ نمو پانے والی علمی ”روایت“ سے مطلقاً زائل ہو گئے۔ معقولی اور آلیہ علوم کی عدم موجودگی میں باہمی مباحث ایک صوابدیدی ہرمینیات پر منتقل ہو گئے اور فتوے کو جھگڑوں میں مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی اور تکفیر کی گرم بازاری ہوئی جو آج تک باقی ہے۔ اب تو علمی بحث شروع ہی نہیں ہوتی اور سیدھا تکفیری علم بلند ہو جاتا ہے جیسا کہ محترم ڈاکٹر امین صاحب نے دلیل کی بجائے جدید جمہوری اور شماریاتی طریقے سے جناب عمار خان ناصر کی ”گمراہی“ کو ”ثابت“ اور ”نافذ“ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر معقولات باقی رہے ہوتے یا کہیں دلیل کا گزر ہوتا تو محترم ڈاکٹر صاحب کو بھی سو مقتدر علما اکٹھے نہ کرنے پڑتے کیونکہ اعداد و شمار دلیل پر غالب نہیں آتے۔
اہل علم اس امر سے یقیناً واقف ہیں کہ ہمارے کلاسیکل علوم کی طویل روایت میں صاحبِ علم ہونے کا اعزار انھی شخصیات کو ملتا رہا ہے جو اصول میں کلام کریں اور جو علوم آلیہ میں مہارت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اسی باعث ملا نظام الدین سہالوی رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا درس نظام سرتاسر علوم آلیہ اور معقولات پر مشتمل تھا اور اس میں قرآن و حدیث کا حصہ بہت کم تھا کیونکہ جو متون مقصود ہوتے ہیں ان کو کبھی ذریعہ نہیں بنایا جاتا۔ روایتی معنی میں، انیسویں صدی کے آغاز سے اب تک ہماری مذہبی روایت میں کوئی چھوٹا یا بڑا اصولی پیدا نہیں ہوا۔ اس سے یہ باور کرنا مشکل نہیں کہ ہمارے ہاں اصولی مباحث کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا ہے۔ ایک ایسے عہد میں جب ہمیں مباحثِ اصول ہی کی ضرورت تھی ان کے خاتمہ بالخیر نے ہماری پوری علمی روایت کا مزاج اور طریقۂ کار بدل دیا۔ اٹھارھویں صدی میں جدید عہد کے بنیاد گزار حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بالکل نئی چیز متعارف کرائی جسے انھوں نے اصولِ تفسیر قرار دیا۔ یہ ہماری علمی روایت کے ایک بڑے موڑ کو ظاہر کرتی ہے جسے معقولات کے خاتمے اور ہرمینیات کے غلبے کا آغاز کہا جا سکتا ہے۔ مباحث اصول کے خاتمے کے زمانے میں ہمارے اہل علم کی توجہ مذہبی متون کے تراجم، تفسیر نگاری اور جدید منہج پر سیرت نگاری کی طرف منعطف ہو گئی۔ اندازہ ہے کہ گزشتہ دو صدیوں میں اس طرح کے علوم کی پیداوار کسی بھی سابقہ دو صدیوں سے زیادہ ٹھہرے گی۔ اور یہ حنفی وہابی مناقشے ہی کا تسلسل تھا کیونکہ اس میں متحجر معقولی اور آلاتی علوم پٹ گئے اور ہرمینیاتی یعنی تعبیری اسالیب زیادہ مؤثر رہے اور بتدریج وہی ہماری علمی روایت پر غالب آ گئے۔ ہرمینیاتی علوم میں افتائی طریقۂ کار کے پیوند سے علوم کا مجموعی مزاج تکفیری ہو گیا اور اس سے جو سنگین مسائل پیدا ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں۔
جنگ آزادی سنہ ۱۸۵۷ء کے بعد یہ صورت حال زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ فرقہ پرستی کی اساس ہی عبارتی نزاعات اور متنی تعبیرات پر استوار ہوتی نظر آتی ہے۔ اگر مباحث اصول زندہ رہیں تو فرقہ پرستی کمزور ہو جاتی ہے اور صوابدیدی ہرمینیاتی مواقف تاریخی عمل سے غیر اہم ہو جاتے ہیں کیونکہ اصول کی بحث علوم کو متحجر نہیں ہونے دیتی۔ مابعد جنگ آزادی چار بڑے مذہبی دھارے سامنے آئے جو تجدد، سیاسی اسلام (political Islam) اور روایتی مزاج کو ظاہر کرتے ہیں۔ اصل میں تجدد اور سیاسی اسلام ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اگر جدیدیت کے اثرات روایت شعور اور علم میں ظاہر ہوں تو تجدد ہے اور اگر روایت عمل میں ظاہر ہوں تو سیاسی اسلام (political Islam) ہے۔ اور ان دونوں میں عقلی، نظری اور اصولی مواقف غیر حاضر رہے ہیں۔ پانچ دھارے یہ ہیں: (۱) آقائے سرسید کے تتبع میں متجددین؛ (۲) اہل دیوبند اور ان کی علمی و سیاسی تحریک؛ (۳) بریلوی مکتب فکر؛ (۴) اہل حدیث مکتب فکر؛ (۵) اہل تصوف؛ ایک عام درجے کا صاحبِ علم بھی اس امر سے واقف ہے کہ یہ مکاتب فکر و عمل ہرمینیاتی اختلافات میں سامنے آئے ہیں اور مباحث اصول سے مطلق خالی ہیں۔ خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روایتی علوم آلیہ اور روایتی علم الکلام اور اصول فقہ کا ان فرقوں کی تشکیل میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کیونکہ یہ سب مذہبی دھارے تقریباً ایک ہی طرح کی درسی کتب پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن آپس میں مکالمہ کرنے کے قابل بھی نہیں ہو پاتے۔
محترم غامدی صاحب کی عظمت:
[التماسی نوٹ در خدمت ڈاکٹر امین صاحب: یہاں ”عظمت“ کے لفظ کی وجہ سے مجھے تجدد کا حامی قرار نہ دیا جائے۔]
گزشتہ دو صدیوں کی انتشاری صورتِ حال میں محترم غامدی صاحب کے ہاں جو علمی ادراک ظاہر ہوا ہے وہ کئی لحاظ سے اہم ہے۔ میرے علم کی حد تک اٹھارھویں صدی کے بعد یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی صاحبِ علم نے اپنی تعبیرات میں کارفرما فقہی وژن اور علمیاتی اصولوں کو مرتب حالت میں بیان کر دیا ہے۔ گزارش ہے کہ محترم غامدی صاحب جس بھی دینی تعبیر/تعبیرات کو سامنے لا رہے ہیں ان کی بنیاد میں کارفرما ہرمینیاتی اور علمیاتی اصولوں کو انھوں نے نہایت مرتب انداز میں صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ تجدد کے بالمقابل جن چار دھاروں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے پاس نئے یا پرانے کسی طرح کے اصول موجود نہیں ہیں، اور ان کا ہر مذہبی موقف کلاسیکل روایت سے بلا اصول چنا اور اٹھایا (pick and choose) ہوا ہے، اور محترم غامدی صاحب کا رد کرنے کے لیے وہ اس کا صرف ذکر کرتے ہیں۔ میں تجدد کے مرتب شدہ ان اصولوں کی کچھ تفصیل گزشتہ دو پوسٹوں میں لکھ چکا ہوں، اور میں ان کے صحیح اور غلط کی بحث ابھی نہیں اٹھا رہا۔
”میزان“ بنیادی طور پر ”اصول و مبادی“ کی صورت میں نئے مرتب شدہ اصولِ فقہ اور ان کے ایرادات کی کتاب ہے۔ یہ ”اصول و مبادی“ ہرمینیاتی (hermeneutical) ہیں اور یہ کتاب انھیں اصولوں پر لکھی گئی ہے۔ ان ”اصول و مبادی“ نے کلاسیکل اصول فقہ کی جگہ لی ہے۔ اور اسی کتاب میں محترم غامدی صاحب نے مقدمہ نمبر دو کے تحت ایمانیات وغیرہ کو شامل کیا گیا ہے اور یہ حصہ تجدد کے علمیاتی (epistemological) اصولوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دو مقدمات ایک طرح سے محترم غامدی صاحب کے اس علمی موقف کا اظہار ہیں کہ عمل اور شعور (ایمان) کو ایک ہی اصول کے تحت زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ ہماری کلاسیکل معقولات میں بھی عمل اور شعور (ایمان) کے مباحث اصول دین اور اصول فقہ کی بڑی روایتوں میں ظاہر ہوئے ہیں اور ان پر غیرمعمولی کلام موجود ہے۔ میں ذاتی طور پر اسے محترم غامدی صاحب کی عظمت قرار دیتا ہوں کہ تین صدیوں کے علمی ویرانے میں انھوں نے مباحثِ اصول کو ایک بار پھر متعارف کرایا ہے اور علمی گفتگو کی بنیاد فراہم کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ میں دیانت داری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اب محترم غامدی صاحب کے اصول و مبادی سے باہر کوئی گفتگو سرے سے ممکن ہی نہیں ہے۔ ان سے باہر جو کچھ ممکن ہے وہ محترم ڈاکٹر امین صاحب اور دیگران و مقتدران و ’مشران‘ کی مہمات کی صورت میں سامنے آ ہی رہا ہے۔ اگر ہمارے ”روایتی“ لوگوں نے آقائے سرسید کے ساتھ بحثوں میں کچھ سیکھا ہوتا تو آج شاید ہمارے حالات بہت کچھ مختلف ہوتے۔ آقائے سرسید کے وقتوں میں اصول اہل تجدد کے پاس تھے نہ اہل روایت کے پاس۔ لیکن ”اہلِ روایت“ کو فتویٰ کی سہولت میسر تھی۔ یہ سہولت اب صرف اس وقت ہی کارگر ہوتی ہے جب جدید ریاست کے مفادات بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اس وجہ سے تجدد کے سامنے ”اہل روایت“ کی بے بسی گہری ہو گئی ہے اور ان کے غصے میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن اہل روایت کے عزم صمیم کی داد دینا پڑتی ہے کہ وہ مذہبی مباحث کو اصول پر منتقل کرنے پر غور فرمانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔
روایتِ اصول، اصولِ تجدد اور روایت کی تعریف:
پہلا سوال یہ ہے کہ محترم غامدی صاحب کے طے کردہ ”اصول و مبادی“ روایتی اصول فقہ اور روایتی اصول دین (علم الکلام) کا تسلسل ہیں یا کسی انقطاع کو ظاہر کرتے ہیں؟ محترم غامدی صاحب کے ”اصول و مبادی“ سے بننے والی تعبیر کو میں تجدد قرار دیتا ہوں، اور اسے کلاسیکل روایتِ اصول میں ایک انقطاع عظیم سمجھتا ہوں۔ اگر تجدد کے بالمقابل روایت کا لفظ استعمال کیا جائے تو دوسرا سوال یہ ہے کہ روایت کی تعریف کیا ہے اور اس کا نمائندہ کون ہے؟ جیسا کہ اصحابِ علم واقف ہیں کہ ہماری ہم عصر ثقافت میں ”روایت“ کی دو تعریفات و مفاہیم متداول ہیں۔ ایک ٹی ایس ایلیٹ کا تصور جو ادب میں روایت کے مسئلے کو زیربحث لاتا ہے اور اردو داں طبقے میں اس تصور کو محمد حسن عسکری نے متعارف کرایا اور کشاں کشاں یہ مذہبی مباحث میں بھی در آیا۔ دوسرا مکتبِ روایت کا تصور ہے جو رینے گینوں اور شوآن وغیرہ کے ہاں ملتا ہے۔ میں روایت کے ان دونوں تصورات کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہوں اور اسے مذہبی مطالعات کے لیے مضر خیال کرتا ہوں۔
میرے نزدیک مذہبی تناظر میں روایت کی تعریف کرنا بہت آسان ہے اور ہمیں اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ مذہبی علوم میں روایت سے مراد وہ معقولی تصورات ہیں جو کلاسیکل اصول فقہ اور اصول دین میں ظاہر ہوئے ہیں۔ مذہبی اور غیر مذہبی علوم کے کسی بھی شعبے میں روایت کی جو بھی تعریف متعین کی جائے گی وہ نظری (theoretical) ہی ہو گی کیونکہ روایت کی تعریف خالصتاً ایک نظری مسئلہ ہے۔ بعدہٗ، میں اس شخص کو روایتی اور روایت کا نمائندہ قرار دیتا ہوں جو روایتاً منتقل ہونے والے کلاسیکل اصولِ فقہ اور اصولِ دین کو اپنا علمی اور معقولی موقف قرار دیتا ہو اور ان پر مرتب ہونے والی تعبیرِ دین کو تسلیم کرتا ہو۔ میرے نزدیک کلاسیکل معقولاتی اصول ہماری روایت ہیں جن میں اصولِ فقہ تعبیر اور اصولِ دین علم اور اس کی تشکیلات کو موضوع بناتے ہیں۔ آج کل ”اہل روایت“ ہونے کا مفہوم بدل گیا ہے۔ اب ”اہل روایت“ سے مراد ایسے احباب ہیں جنھوں نے پرانی کتابوں سے pick and choose کے ذریعے تین چیزوں میں سے دو چیزیں اختیار کر لی ہوں اور تیسری چھوڑ دی ہو۔ پرانی کتابوں میں (۱) مذہبی موقف موجود ہوتا ہے؛ (۲) فتویٰ مذکور ہوتا ہے؛ اور (۳) اصول موجود ہوتا ہے۔ آج کل کے اہل روایت اول الذکر دو چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں اور تیسری چیز کا ذکر کرنا بھی مناسب خیال نہیں کرتے۔ میرے نزدیک روایتی ہونے سے مراد کلاسیکل مباحثِ اصول کو پیش نہاد (foreground) کرنا ہے نہ کہ کلاسیکل مذہبی مواقف کو decontextualize کر کے انھیں اختیار کرنا۔ یہ تینوں چیزیں نہایت متوازن انداز میں امام عالی مقام غزالی علیہ رحمۃ میں نظر آتی ہیں۔ ان کے ہاں معقولی اصول، روایتی مذہبی موقف اور فتویٰ ایک توازن میں کام کرتے ہیں۔ ہمارے موجودہ اہل روایت میں کلاسیکل مذہبی موقف اصول کے بغیر اور فتوے کے ساتھ ہیں۔ جبکہ محترم غامدی صاحب فتویٰ سے حد درجہ احتراز برتتے ہیں اور بعض اوقات ضروری محل پر بھی اس سے پہلو بچاتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کے ہاں نئے اصولوں کی ”دریافت“ ہے۔
میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ محترم غامدی صاحب اب اصولوں سے لیس ہو کر مذہبی تعبیر کا کام کر رہے ہیں۔ ان اصولوں کی موجودگی میں دو چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے کہ (۱) محترم غامدی صاحب اپنی تعبیر دین کو ان اصولوں پر قائم کرنے میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں؟ (۲) یہ اصول چونکہ خود ان کے وضع کردہ اور ”عقلی“ ہیں اور جو ان کی تعبیر دین میں متصرف ہیں، اس لیے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ وہ ”عقلی“ بھی ہیں یا نہیں؟ اصول کا افادیت یہ ہے کہ تصورات عقل اور مشترک استدلال سے ان کے ساتھ رد و قبول کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ ان کے مخاصم چار گروہوں نے کچھ کلاسیکل مذہبی مواقف کا بستہ مضبوطی سے تھام رکھا ہے، جہاں سے فتوے کے صرف ”پنے“ برآمد ہوتے ہیں اور اس بستے میں موجود اصول کی کتابوں کو دیمک چاٹ گئی ہے۔ اسی باعث ان چار گروہوں میں محترم غامدی صاحب کے لیے فتوے کی گرم بازاری ہے، اور ان کے مخاصمین کی زبان بھی بہت گھٹیا ہو گئی ہے۔ اہل روایت میں قدیم یا جدید عقل کا کوئی تصور ہی بار نہیں پاتا اور وہ اپنے اصولوں کو جانتے ہیں اور نہ ان کا بیان کر سکتے ہیں اور نہ وہ روایتی اصول فقہ اور اصول دین کو محترم غامدی صاحب کے ”اصول و مبادی“ کے سامنے لانے کے فکری وسائل رکھتے ہیں۔ محترم غامدی صاحب کے خلاف لکھی گئی کتابوں اور یو ٹیوب پر ”حنفی اصولی منہج“ کا بیان اور دفاع دیکھ کر موجودہ ”علمی“ صورت حال کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے محترم ڈاکٹر امین صاحب بھی افتائی کام ثواب کے لیے کر رہے ہیں ورنہ الا ماشاء اللہ انھیں مباحث علوم سے اتنی ہی مناسبت ہے جتنی مسلم حکمرانوں کو عدل سے ہے۔
تجدد اور روایت کا تنازع:
اس وقت صورت مسئلہ یہ ہے کہ اہلِ تجدد اصول کے تحت اپنے نئے تعبیری مواقف سامنے لا رہے ہیں جبکہ اہل روایت کلاسیکل مذہبی مواقف کے علمبردار تو ہیں لیکن ان کے پاس کوئی اصول نہیں ہیں کیونکہ ان کا سرمایۂ معقول و اصول پہلے معرکے میں ہی لٹ گیا تھا۔ تجدد اور روایت کا باہمی نزاع اس وقت تک فیصل نہیں ہو سکتا جب تک بحث کو اصول کے دائرے میں آگے نہ بڑھایا جائے۔ اس امر کی ضرورت ہے کہ کلاسیکل اصول فقہ اور اصول دین کا موازنہ و مناقشہ محترم غامدی صاحب کے اصول و مبادی سے کیا جائے۔ اہلِ روایت اس کام کی کوئی استعداد نہیں رکھتے کیونکہ وہ خود کلاسیکل اصول فقہ اور اصول دین سے صرف تبرک کی حد تک وابستہ ہیں۔ اٹھارھویں صدی کے اوائل میں احناف اور وہابیت کے درمیان جو مناقشہ ہوا، وہ صورت حال تھوڑے بہت فرق کے ساتھ اب بھی جوں کی توں باقی ہے۔ جس طرح آقائے سرسید کی تکفیر اور دشنام دہی سے روایت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا اسی طرح محترم غامدی صاحب کی گمراہی کو مؤول کرنے سے کچھ نہیں ہو گا۔ بنیادی مسئلہ عقل و فکر کی جنگ کا ہے جو متجددین ابھی تک جیتتے چلے آئے ہیں اور حالیہ آثار بھی یہی ہیں۔ لیکن اس امر کا اظہار محترم ڈاکٹر امین صاحب کو بہت ناگوار گزرتا ہے۔
سیاسی اسلام اور روایت:
ہماری علمی روایت میں جو مسائل تجدد سے پیدا ہوئے ہیں عین وہی صورت حال سیاسی اسلام نے پیدا کی ہے۔ جس طرح تجدد کے سامنے افتائی تزویرات نہیں چل سکتیں اور مباحث اصول کی ضرورت ہے، بعینہٖ سیاسی اسلام کے روبرو بھی نئے سیاسی نظریے (political theory) کی ضرورت ہے۔ ایسے نظریے کو اولاً مکمل طور پر سیاسی ہونا چاہیے تاکہ درپیش دنیا کی سیاسی اور معاشی ہیئت کو سمجھا جا سکے۔ ابتدائی درجے میں اسے اخلاقی اور نظریاتی (ideological) پہلوؤں سے دور رکھنا چاہیے۔ (یہاں میں تھیوری اور آئیڈیالوجی میں جائز فروق کو روا رکھ رہا ہوں۔) جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ تجدد کی اصل عقلی اور فکری وسائل کو بروئے کار لائے بغیر، یعنی کسی اصول اور معقولی مبحث کے بغیر، افکارِ جدیدیت اور مذہب میں تطبیق ہے۔ بعینہٖ سیاسی اسلام کی اصل عقلی اور فکری وسائل کو بروئے کار لائے بغیر، یعنی کسی اصول اور معقولی مبحث کے بغیر، ادارہ جاتی جدیدیت ( institutional Modernity) اور شریعت کے اجتماعی احکام کی تطبیق ہے۔ ان مسائل کا سامنا بھی صرف اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب مباحث کو اصول کے تناظر میں آگے بڑھایا جائے۔
اصول و مبادی اور ردِ تجدد:
تجدد اور روایت کے مناقشے میں بنیادی سوال کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے جو اس وقت فراموشگاری میں ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ ہدایت اور عقلی علم کی باہمی نسبتیں کیا ہیں، اور خود عقلی علم سے کیا مراد ہے؟ ہدایت علم کے تصورات پر اثرانداز ہوتی ہے اور عقلی علم ہدایت کی حیثیت، معنویت اور تفہیم پر اثرانداز ہوتا ہے۔ ہدایت اور علم کو ذہن کے الگ الگ خانوں میں نہیں رکھا جا سکتا۔ عقلی علم فہم دنیا ہے، اور ہدایت خبر غیب۔ ہمارے کلاسیکل مباحث اصول ان امتیازات پر حرف نہیں آنے دیتے۔ الوہی ہدایت اپنی آٹونومی اور ساورنٹی میں انسان اور دنیا کو بدلنے کے مطالبات رکھتی ہے اور مباحث اصول اس استحضار کو سربلند رکھتے ہیں۔ لیکن تاریخ میں ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ دنیا، الوہی ہدایت کو ہی بدل دینے کا جبر سامنے لے آئے۔ اس وقت ہمیں انھی حالات کا سامنا ہے۔ تہذیبی اور علمی شکست کے حالات میں طاقتور جدید تاریخی مؤثرات نے مسلم شعور کو روند ڈالا ہے۔ تجدد کے اصول و مبادی اسی شکست خوردہ شعور کے دنیاوی حاصلات ہیں جن کو یہ شعور الوہی ہدایت تک توسیع دینا چاہتا ہے۔


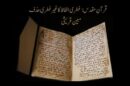
















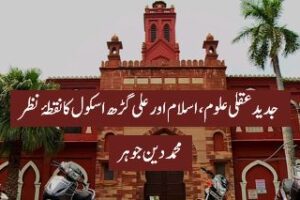


کمنت کیجے