
عمران شاہد بھنڈر
کسی بھی الٰہیاتی متن کی تفہیم کا قدیم منہج یہ ہے کہ اس میں قرأت کا حتمی مقصد مصنف کی منشا کو دریافت کرنا ہوتا ہے۔ اگر مصنف کی منشا دریافت ہو گئی اور اس کا مقصد متعلقہ لوگوں پر عیاں ہو جائے تو قرأت کا مقصد مکمل ہوجاتا ہے۔ اس منہج کے تحت متن اپنی خود مختار اور فعال حیثیت سے محروم ہوتاہے اور نہ ہی قاری معنی خیزی کے عمل میں کوئی فعال اور تخلیقی کردار ادا کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ جدیدیت میں وہی مرکزیت جو الٰہیاتی متون کی تعبیرات کے دوران خدا کو حاصل ہوئی تھی وہی مرکزیت جدید مصنف نے حاصل کر لی۔ جدید تنقید میں مرکزیت کا مطلب یہ ہے کہ متن کا ایک ماخذ اور ایک منبع ہے اور وہ جدید مصنف ہے۔ لہذا مصنف کے منشا و مقصد کو دریافت کر لیا جائے تو متن کے حتمی معنی تک رسائی ہو سکتی ہے۔تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ منہج بہت سی الجھنیں اور مسائل پیدا کرتا ہے اور اس منہج کے حصار میں رہتے ہوئے ان الجھنوں کو دور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ قرآن کی جو تعبیرات ہوئی ہیں ان کی روشنی میں خدا کی منشا و مقصد کی بجائے انسان بطور ایک قاری فعال کردار ادا کرتا ہے۔ ان متنوع تعبیرات کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مسلمانوں میں کئی فرقے جنم لے چکے ہیں اور ہر فرقے کی قرآنی متن کی ایک مخصوص تعبیر ہے۔ صرف یہی بات کافی نہیں ہے، ہر فرقہ دوسرے فرقوں کی تعبیرات کو غلط ہی نہیں کہتا بلکہ انہیں کافر بھی قرار دیتا ہے۔ اس قرآنی متن کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کو کئی اہم اسلامی مفکرین نے خدا کا کلام ماننے سے انکار بھی کیا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا کی منشا و مقصد مرکزیت میں نہیں ہے بلکہ اصل حیثیت قاری کی ہے جو اپنے مخصوص علمی، سماجی اور ثقافتی پس منظر میں قرآن یا دیگر متون کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ یہ تسلیم نہ کر لیا جائے کہ خدا معنی پر قادر نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی ایک ”وحدانی الٰہیاتی معنی“ کی ترسیل کر رہا ہے جس کے بعد تعبیرات کا امکان ختم ہو گیا ہو۔ معنی تاریخ کے مختلف ادوار میں متن کی ’مرکزی‘ حیثیت کو تسلیم کیے بغیر تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ جدید ماہرینِ لسانیات نے مختلف متون میں سات اصولوں کو دریافت کیا ہے۔ ان اصولوں میں مصنف کی منشا، صرف و نحو کی سطح پر تطابق یا ہم آہنگی، نظم جس کا تعلق خیال، خیالیہ (تھیم) اور معنوی جہت میں ربط کی تشکیل، سیاق، علمی جہت، متن کی قبولیت اور بین المتونیت کا پہلو اہم قرار پاتے ہیں۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی متن میں معنی کیسے پیدا ہوتا ہے اور کیا معنی کی ”حتمی تعیین“ ممکن ہے؟ اگر تو متن کو فعال تسلیم کرکے قرأت کی بنیاد متن کے داخلی رشتوں پر رکھی جائے تو الٰہیاتی اور غیر الٰہیاتی متون میں حتمی معنی کا تعین ناممکنات میں سے ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب مصنف کو پہلے ہی مرکز میں رکھا جا چکا ہو۔ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ الٰہیاتی متون کی لاتعداد تعبیرات ہوتی ہیں۔ اس لیے کوئی بھی مصنف ہو، خدا یا انسان وہ کسی بھی لکھت کو لکھتے وقت زبان کے اصول و قواعد کا پابند ہوتا ہے۔ زبان ایک ثقافتی تشکیل ہے اور زبان کے داخلی رشتے کسی بھی مخصوص ثقافت اور سماج کی اقدار کا معنوی اظہار ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھی زبان کو مدِ نظر نہ رکھا جائے اور مصنف یہ دعویٰ کرے کہ وہ زبان میں الفاظ کی ترتیب تبدیل کر کے ایک ایسی ترتیب قائم کرتا ہے جو اس زبان میں ناقابلِ فہم ہے تو یہ ایک طرح کی خود کلامی ہوتی ہے اور خود کلامی جو کہ انتہائی درجے کی مبہم ہوتی ہے اس کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہذا اگر کوئی مصنف یہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی قابلِ فہم متن کی تشکیل کرے تو اسے ہر لحاظ سے زبان کے داخلی رشتوں کا پابند ہونا پڑتا ہے۔ یہ مصنف کی منشا و مقصد کی پہلی ڈی کنسٹرکشن ہوتی ہے کہ جب وہ خود کو زبان کے داخلی اصولوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے اسے انہی مفاہیم، تصورات، خیالیہ، خیال اور معنی کے اعتبار سے قابلِ فہم انداز میں پیش کرتا ہے جن کی وہ خود بھی پیداوار ہوتا ہے تاکہ اس کا پیغام قابلِ فہم ہو جائے۔ یہاں یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ کسی بھی کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ اس کتاب میں مختلف خیالات، معنی کی جہات اور تصورات موجود ہوتے ہیں، جو کہ اس موضوع سے اپنی وحدت کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ نظم کس درجے کا ہے اس کا تعین ناقد اور ماہرینِ لسانیات کرتے ہیں۔ مذہبی متون کا تجزیہ ایک مخصوص پس منظر میں اپنے عقیدے سے منسلک رہتے ہوئے اور تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عقیدہ رکھنے والے اس کا صحیح معنوں میں تنقیدی جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ انتہائی محتاط رہتے ہوئے زبان میں پنہاں معنی خیزی کے عمل کو یکسر نظر انداز کرتے ہیں۔
زبان میں معنی خیزی کا عمل قرأت کی خصوصیت ہے لیکن خیالات، تصورات اور معنی کی جہت متعین کرنا زبان کے داخلی اصولوں کے متعین کردہ اثرات کے مرہونِ منت ہوتے ہیں۔ نقاد جانتا ہے کہ زبان معلول نہیں، جس کو بروئے کار لاکر کوئی مفکر و مفسر اپنی مرضی کے معنی پہنا دے۔ زبان معنی کی علت ہے نہ کہ مصنف۔ نقاد یہ بھی جانتا ہے کہ متن ان معنوں میں خود مختار نہیں ہے کہ وہ بین المتونیت کے اصولوں کو نظر انداز کر دے۔ جیسا قرآن میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جو بائبل میں موجود ہیں۔ اس طرح نقاد کا کام ان تصورات اور معنویت کا سراغ لگانا بھی ہے جو دوسرے متون سے تعلق رکھتے ہیں۔
زبان کے چند قواعد میں سے ایک بنیادی’لفظ‘ کا استعمال ہے۔ ساختیات کے تحت جو مباحث موجود ہیں ان کے مطابق کسی بھی سائن (لفظ یا نشان) میں ایک اس کی موضوعی صورت شامل ہوتی ہے اور دوسری اس کی حقیقی صورت جس کے تحت کوئی بھی لفظ بامعنی کہلاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ لفظ میں دو تصورات شامل ہوتے ہیں: ایک دال (سگنی فائر) اور دوسرا مدلول (سگنی فائڈ)۔ دال ایک بولا یا لکھا ہوا لفظ ہے۔ جبکہ ان سے جو تصور پیدا ہوتا ہے وہ حقیقی چیز ہوتی ہے۔ لہذا ’لفظ‘ میں دال اور مدلول دونوں یکجا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کی گہرائی میں اتریں (جیسا کہ ابتدائی بحث میں وضاحت کی گئی ہے) تو اصل زد اس موضوعی تصور پر پڑتی ہے جو کسی کلمے یا تحریر میں معنی کی تشکیل کا دعوے دار ہے۔ کیونکہ مابعد ساختیات کے مباحث میں ایک لفظ جس میں دال اور مدلول دونوں شامل ہوتے ہیں وہ دوسرے الفاظ سے مل کر معنی کو پیدا کرتا ہے۔ ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے رشتہ کسی لزوم کے تحت نہیں ہوتا جو کہ کسی مصنف کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، بلکہ الفاظ کے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے زبان کی داخلی ساخت کے پابند ہوتے ہیں۔ جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ مصنف کی موضوعیت کی نفی ہو جاتی ہے تو وہ نفی الفاظ کے باہمی رشتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس حوالے سے جو چند اصول تشکیل دیے گئے ہیں ان میں ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے فرق، دونوں کے درمیان تضاد کی نوعیت، لفظ کا کسی موضوعی لزوم کے بغیر دوسرے الفاظ کے ساتھ اپنے تعلق میں خود مختار ہونا، ان کے درمیان اضافیت وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں جو رشتہ انتہائی اہم ہے وہ ’افتراق‘ کا ہے جو ایک مفسر اور دوسرے مفسر کی تفسیر میں کسی نہ کسی سطح پر قائم رہتا ہے۔ متن کی تعبیر میں ’افتراق‘ کی مصنف کی منشا تک تخفیف ممکن نہیں ہوتی۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ متن کے تمام داخلی رشتوں کو نظر انداز کر کے متن سے مصنف کو برآمد کر لائیں۔ ان معنوں میں متن میں جو معانی پیدا ہوتے ہیں ان میں مصنف کی موضوعیت تحلیل ہو جاتی ہے اور متن ایک فعال کردار کی حامل معروضیت تشکیل دیتا ہے۔ واضح رہے کہ میں نے”مصنف کی موت“ نہیں بلکہ اس کی ’تحلیل‘ کہا ہے۔انتہائی توجہ سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ مصنف اس متن میں اگر کسی معنی پر قادر نہیں ہے تو وہ کس حیثیت میں متن کے اندر موجود ہے۔ خواہ کسی الٰہیاتی تصنیف کا مصنف ہو، یا کسی غیر الٰہیاتی تصنیف کا، وہ اپنی تصنیف میں گُم ہو جاتا ہے۔ معنی پر اس کی گرفت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی منشا و مقصد پر قاری اور نقاد سے متن کے اندرونی رشتوں کی بنیاد پر مطابقت قائم ہو جاتی ہے۔ یہاں تصنیف اور متن کے فرق کی تفہیم بھی ازحد ضروری ہے۔ تصنیف ایک کتاب ہوتی ہے جو اپنی معروضی حیثیت رکھتی ہے۔ متن اس کتاب کے اندر ہوتا ہے۔ متن صرف وہی ہو سکتا ہے جو متن کے اصولوں کے تابع ہو۔ متن کی لاتشکیل کا نکتہ متن کی تشکیل کے بعد پیدا نہیں ہوتا، بلکہ جونہی تصنیف وجود میں آنا شروع ہوتی ہے، اس کے اندر متن کی لاتشکیل کے پہلو بھی عیاں ہونے لگتے ہیں۔ لہذا ہر تشکیل اپنی سرشت میں لاتشکیل ہوتی ہے اور ہر لاتشکیل لازمی طور پر ایک تشکیل بھی ہوتی ہے۔ یعنی کسی بھی متن کی لاتشکیل ایک الگ متن کی صورت میں ایک نئی تشکیل ہوتی ہے۔
آگے بڑھنے سے پہلے یہ انتہائی اہم نکتہ سمجھنا ضروری ہے کہ لفظ جس میں دال اور مدلول شامل ہوتے ہیں، وہ دوسرے الفاظ سے رشتے میں آکر معنی کی تشکیل کرتا ہے نہ کہ خارجی مدلول یا معروض سے، لہذا لفظ دوسرے الفاظ سے مل کر جس معنی کو وجود میں لاتا ہے، وہ دال یا سگنی فائر کی سطح پر ہوتا ہے۔ وہ متن کے اندر دوسرے الفاظ سے اپنے روابط رکھتا ہے۔یہاں پہلی لاتشکیل ہی لفظ کا دوسرے الفاظ کے ساتھ ارتباط ہے نہ کہ اس میں مصنف کی موضوعیت دریافت کی جائے اور متن کی فعالیت پر زبردستی کوئی معنی مسلط کر دیا جائے۔ متن کی فعالیت جب عملی سطح پر قرأت کے دوران واضح ہو جائے تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا کہ متن کی معروضیت کو تسلیم کر لیا جائے۔ مذہبی متون کی تفہیم میں متن کی معروضیت کی تفہیم کے بعد بھی معنی کو دال کی سطح پر نہیں آنے دیا جاتا۔ دال یا سگنی فائر معنی کا انہدام ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ حتمی اور آخری معنی کی تعبیر کا انکار ہے کہ جس کے بعد یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ یہی تعبیر آخری ہے۔معنی دکھائی تو دیتا ہے لیکن اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب اس کے بعد کوئی تفہیم ممکن نہیں ہے۔ لاتشکیل ایک مستقل قرأت ہے۔ وہ متن کو ان معنوں میں غیر مستحکم اور سیال مانتی ہے، جس میں معنی اپنا نظارہ کرواتا ہے، اور پھر اگلے لمحات میں اسے متعین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں متن کی قرأت زیرِ بحث ہے، کسی کا عقیدہ نہیں جسے کوئی شخص معروضی سطح پر اختیار کیے ہوئے ہے۔
جونہی ہم متن کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ جان کر حیران رہ جاتے ہیں کہ متن کے اندر الفاظ کے انگنت رشتے موجود ہیں، افتراقات کا ایک وسیع سلسلہ ہے۔ جہاں ایک ہی لفظ مختلف الفاظ سے تعلق میں آ کر مختلف معانی کی تشکیل کرتا ہے۔ قرأت کے عمل میں دو رجحان دکھائی دیتے ہیں۔ ایک وہ جس کے تحت معنی سے معنی کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہ معانی تخلیقی نوعیت کے نہیں ہوتے۔ ان کا قاری مجہول ہوتا ہے جیسا کہ عقیدہ پرستوں کی اکثریت ہوتی ہے۔ وہ مصنف سے آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی ذہنی سطح پر مصنف کے حصار میں رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ تاہم عملی سطح پر وہ اس حصار سے ماورا ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ معنی کی تشکیل پر نظر رکھتا ہے۔ اس کے برعکس نقاد کا کام متن کی لاتشکیل کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن جس ترتیب سے ”نازل“ ہوا وہ ترتیب بعد میں قائم نہیں رہی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کسی ترتیب کے بغیر ”نازل“ ہوا؟ یہ تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تاہم جس ترتیب میں قرآن موجود ہے اس ترتیب سے جب کوئی قاری نظم کو تلاش کرتا ہے تو وہ بھی ایک نیا نظم تشکیل دیتا ہے۔ یہ نیا نظم نہ تو قرآن کے ”نزول“ کے وقت تھا اور نہ ہی یہ نظم قرآن کی موجودہ ترتیب سے ماخوذ ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر قرآن کی موجودہ ترتیب میں ایک نظم موجود ہے تو پھر وہ نظم انہیں سورتوں کی ترتیب میں دکھائی دینا چاہیے۔ ”سورہ المائدہ“ کی تیسری آیت یہ کہتی ہے کہ”آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔“ اگر قرآن کو مکمل کر دیا گیا تھا تو پھر اس آیت کو معنویت کے اعتبار سے آخر میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ترتیب قائم کی گئی ہے، اس میں بھی معنوی اعتبار سے نظم موجود نہیں ہے۔ ورنہ ”نزول“ اور قرآن کو مجتمع کرنے کی ترتیب میں احکامات کو مکمل کرنے کی آیت آخر میں ہوتی۔ اسی طرح کے دیگر مسائل بھی ہیں جن کا قاری کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فی الوقت مجھے اس پہلو سے بھی تفصیلی بحث مقصود نہیں ہے، یہاں پر صرف یہی کہنا مقصود ہے کہ جو مفسرین نظم کی الگ ترتیب قائم کرتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر سے دریافت کیا گیا نظم ہے، وہ نظم بھی ان کی بطور قاری موضوعی تشکیل ہوتا ہے۔کیونکہ وہ جو ترتیب قائم کر رہے ہیں وہ قرآن کی ترتیب نہیں ہے۔ ورنہ اگر قرآن کو مجتمع کرنے کی ترتیب میں نظم موجود تھا تو اس نظم کو ایک الگ ترتیب سے ثابت کرنے کی کیوں ضرورت پیش آگئی؟ یہ بطور قاری ان کا حق ہے کہ متن کو فعال مانتے ہوئے اس میں موجود معنی کی موضوعی تشکیل کریں، کیونکہ ان سے پہلے بھی مختلف مفکر قرآنی مفاہیم پر متفق نہیں ہوئے ہیں۔
بعض مفکر متن میں معنویت کے اس لامتناہی سلسلے کا فکری سطح پر بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اپنی عقیدہ پرست خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ دوسرے مفسرین پر برس پڑتے ہیں اور اس تسلسل میں وہ انتہا کے تخفیف پسند واقع ہوتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ متن مستحکم اور غیر سیال ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ بھی انہیں خدا کی منشا کے تابع ہو جانا چاہیے۔ اگر بنظر غور دیکھا جائے تو ان کی یہ قرأت بھی ان کی اپنی تفہیمی سطح کے زیرِ اثر تشکیل پاتی ہے۔ یہ متن کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا۔ وہی مفکرین بعد ازاں یہ دعویٰ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے ”اظہار کی ساخت“ کو سمجھنا ناممکن ہے۔ یعنی جس ”اظہار کی ساخت“ کو وہ خود ہی نہیں سمجھ پاتے اسی کے بارے میں حتمی فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ کوئی بھی اعلیٰ درجے کا متن ہو اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس جیسا متن دوبارہ نہیں لکھا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے متون کی تشکیل کے بعد جو متون وجود میں آتے ہیں وہ ایک مختلف زمانے اور گزشتہ متون کی تفہیم کی ارتقا شدہ شکل ہوتے ہیں۔ یہ دعویٰ سرے سے ہی غلط ہے کہ فلاں متن جیسا متن لکھ کر لاؤ۔ جہاں تک آسمانی متون کا تعلق ہے تو انہیں عام انسان کی لکھی ہوئی کتابوں سے زیادہ بہتر طور پر قابلِ تفہیم ہونا چاہیے۔ کیونکہ ان کتابوں کا مقدمہ ہی انسان کی اصلاح کے تصور پر کھڑا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ایک متن کو ترتیب دے اور پھر اسی متن کو ناقابلِ تفہیم بھی بنا دے؟ اگر خود ہی ناقابلِ تفہیم بنا دیا جائے تو پھر اس سے اصلاح کا سوال بھی بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ متن میں ابہام شعری خصوصیت ہے جسے بعض شعرا جان بوجھ کر قائم کرتے ہیں۔ شعری ابہام کی بنیادی صفت ہی یہ ہوتی ہے کہ اس میں مضمر معانی کا تعین نہیں ہوتا۔ تاہم الٰہیاتی کتابوں میں ابہام کا مقصد سمجھ سے بالاتر ہے۔ ”عہد نامہ جدید“ کی کتاب”مکاشفہ“ میں اسی قسم کا ابہام پایا جاتا ہے کہ معنی سے متعلق چند مسیحی سکالرز بھی ایک دوسرے سے متفق نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ وہ تمثیلیں، علامتیں، تشبیہات اور تلمیحات ہیں جو ایسے مناظر کو پیش کرتی ہیں جو ابھی انسان کے مشاہدے میں نہیں آئے۔
متون کی تعبیرات کا جو سلسلہ چل نکلا ہے، اس کی حوصلہ شکنی فکری سطح پر جمود کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جبکہ تعبیرات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، اس کا تعین متن، اس کا قاری اور نقاد حالات کے تقاضوں کے تحت خود ہی کر لیں گے۔ متن اگر فعال ہے تو اس کی تعبیر بھی تخلیقی ہوتی ہے۔ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قدامت پسندوں کی طرح سماج کو ماضی میں نہیں دھکیلا جا سکتا۔ بعض لوگ کی فکری تربیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جہاں موجود ہوں وہاں زندہ نہیں ہوتے، اور جہاں زندہ ہوں وہاں موجود نہیں ہوتے۔ وہ تمام تعبیرات کو غلط قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ تمام “غلط” تعبیرات میں ان کی اپنی تعبیر بھی شامل ہے۔
نوٹ: مضمون کے دوسرے حصے میں میری کوشش ہو گی کہ مختلف سورتوں کی مثالیں دے کر یہ دکھایا جائے کہ قرآن کی کئی سورتوں میں نظم موجود ہے۔ اگرچہ سورتوں کے درمیان معنوی اعتبار سے کوئی ربط یا نظم موجود نہیں ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
عمران شاہد بھنڈر صاحب یو۔کے میں مقیم فلسفہ کے استاد اور کئی گرانقدر کتب کے مصنف ہیں۔



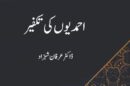
















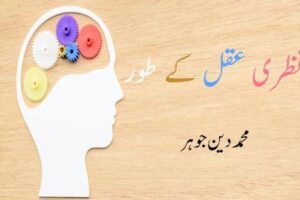
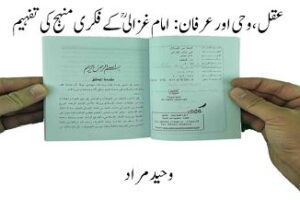
کمنت کیجے