کیا غزالی نے طبعی و تجرباتی علوم سیکھنے سے روک دیا تھا؟ تھافت الفلاسفۃ کے باب ستراں کا مقدمہ
بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ امام غزالی مسلمانوں کی موجودہ علمی زبوں حالی کے ذمہ داری تھے۔ امام غزالی پر مسلمانوں کی موجودہ قحط الحالی کی ذمہ داری کا الزام لگانے والے مفکرین نے کتاب “تھافت الفلاسفۃ ” (Incoherence of Philosophers) کو یا پڑھا نہیں ہوتا اور یا اس کے مقدمے سے آگے نہیں پڑھا ہوتا کیونکہ جس نے پڑھا ہو وہ ایسی باتیں نہیں کرسکتا۔ ان لوگوں کے پاس امام غزالی کو کوسنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ غزالی نے اس کتاب میں علت و معلول (cause and effect) کے تصور کا انکار کردیا جس کی وجہ سے مسلمانوں نے طبعی و تجرباتی علوم کا مطالعہ نہ کیا۔ یہ بات بذات خود غلط ہے کیونکہ اہل مذہب کبھی علت و معلول کے اصول کا انکار نہیں کرسکتے کیونکہ ذات باری کے اثبات کی ان کی دلیل اسی اصول پر قائم ہے۔ بات یہ ہے کہ اشاعرہ و امام غزالی جب دنیا میں علت و معلول کے اصول کا اقرار و انکار کرتے ہیں تو دو الگ مفاہیم مراد ہوتے ہیں، فی الوقت اس بات کو ایک جانب رکھئے۔ کتاب “تھافت الفلاسفۃ” کے مقدمے ہی میں امام صاحب نے بات کو اس طرح واضح کردیا ہے کہ ناقدین کا یہ الزام بے معنی ٹھہرتا ہے لیکن ہم مقدمے سے آگے بڑھ کر کتاب کے ایک خاصے حصے کا خلاصہ پیش کرتے ہیں جس سے غلط فہمیاں پوری طرح دور ہوجاتی ہیں۔
اس کتاب کے بیس ابواب کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: الہیات اور طبعیات۔ ابتدائی سولہ مباحث خالص الہیات سے متعلق ہیں جبکہ آخری چار کو امام صاحب نے طبعیات کے تحت رکھا ہے۔ باب نمبر ستراں وہ باب ہے جس میں امام صاحب نے علت و معلول کے اصول پر بحث کرتے ہوئے امکان معجزہ کی اصولی بنیادوں کو واضح کیا ہے۔ آخری چار ابواب سے قبل امام صاحب نے ایک تعارفی مقدمہ تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہی “طبعیات” ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ طبعیات سے متعلق فلاسفہ کے علوم کو اصول و فروع میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اصول آٹھ علوم پر مشتمل ہیں:
1۔ وہ علم جو جسم بحیثیت جسم کے امور سے بحث کرتا ہے جیسے کہ حرکت، زمان و مکان وغیرہ، اسے فزکس کہتے ہیں
2۔ وہ علم جو ان عناصر سے بحث کرتا جن سے یہ عالم بنا ہے، اسے زمین و آسمان کا علم (On the heavens and worlds) کہا جاتا ہے
3۔ وہ علم جو اشیا کے تغیر و فساد، بڑھوتری و نشونما وغیرہ کے اصولوں سے بحث کرتا ہے۔ ان امور کو کتاب الکون و الفساد (On generation and corruption) میں جمع کیا جاتا ہے
4۔ وہ علم جو زمین سے بالائی سطح پر رونما ہونے والے امور سے اشیا میں ہونے والے تغیر و فساد کے تعلق سے بحث کرتا ہے جیسے کہ بادل و بارش، زلزلہ، ہواؤوں وغیرہ کے اثرات
5۔ معدنیات سے متعلق علم
6۔ نباتات سے متعلق علم
7۔ حیوانات اور ان کے طبائع سے متعلق علم
8۔ نفس انسانی سے متعلق علم
فروع سات علوم پر مبنی ہیں:
1۔ طب: انسانی بدن کے احوال، صحت و امراض سے متعلق
2۔ نجوم: ستاروں کی حرکت سے انسانوں کے اعمال وغیرہ سے متعلق تخمینہ لگانا
3۔ فراست: ظاہری جسمانی مظاہر سے اخلاقی احوال کا استنباط
4۔ تعبیر: خوابوں وغیرہ کی تعبیر سے متعلق
5۔ طلسمات: عالم ارضی و علوی کے عناصر کے ملاپ سے ایسے اثرات پیدا کرنا جو ششدر کردینے والے ہوں
6۔ جادو: عالم ارضی کو ملا کر حیران کرنے والے نتائج پیدا کرنا
7۔ کیمیا: معدنیات و عناصر کے خصائص میں تبدیلی لاکر انہیں سونے و چاندی میں تبدیل کرنے کی کوشش
طبعی علوم کے اس خلاصے کے بعد آپ لکھتے ہیں:
لا نخالفهم شرعاً في شيء منها وليس يلزم مخالفتهم شرعاً في شيء من هذه العلوم وإنما نخالفهم من جملة هذه العلوم في أربعة مسائل
مفہوم: ان علوم میں سے کسی کے بارے میں بھی ہم شرعی نکتہ نگاہ سے ان کی مخالفت نہیں کرتے اور نہ ہی ان میں مخالفت کرنا ضروری ہے۔ اس باب میں ہم ان کی مخالفت چار مسائل میں کرتے ہیں
چنانچہ فزکس و کیمیا وغیرہ کجا امام غزالی تو علم نجوم و طلسم کو بھی کلی طور پر رد نہیں کررہے، ایک اور مقام پر آپ کہتے ہیں کہ علم نجوم ظنی علوم میں سے ایک ہے۔ وہ چار مسائل جن پر آپ نے نقد کیا درج ذیل ہیں:
1۔ فلاسفہ کا یہ دعوی کرنا کہ اشیا کے اقتران (concurrence) کے مشاہدے سے ان کے مابین علت و معلول ہونے کا جو تصور پیدا ہوتا ہے وہ تعلق لازم و اٹوٹ ہےجس کے برعکس ہونا نہ کسی کی قدرت میں ہے اور نہ ہی ایسا ہونے کا کوئی امکان۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر ان کی یہ بات درست مان لی جائے تو معجزے کا امکان ختم ہوجاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ لوگ معجزات سے متعلق جمیع آیات کی تاویل کرتے ہیں
2۔ یہ دعوی کہ انسانی نفس ایک قائم بالذات جوہر ہے نیز یہ انسانی بدن میں منعکس نہیں، نیز موت کا مطلب انسانی نفس و بدن کے تعلق کا منقطع ہوجانا ہے ۔ ان کا دعوی ہے کہ یہ امور قطعی عقلی دلیل سے ثابت ہیں
3۔ یہ دعوی کہ روح یا نفس انسانی کا معدوم ہونا محال ہے
4۔ یہ دعوی کہ روح انسانی کا اجسام میں دوبارہ لوٹنا محال ہے (اسی بنا پر فلاسفہ جسمانی حشر و نشر کا انکار کرتے تھے)
جو مسلمان امام غزالی پر معترض ہیں کہ انہوں نے علت و معلول پر نقد کرکے مسلمانوں کو زوال کا شکار کردیا وہ یہ تائیں کہ انہیں فلاسفہ کا یہ نظریہ قبول ہے کہ معجزات کا ظہور محال ہے؟
امکان معجزہ کو ثابت کرنے کے لئے باب ستراں میں آپ نے دو اصولوں پر بحث کی ہے:
1۔ اشعری اصول پر جس کے مطابق اشیا میں کوئی تاثیر (potential) نہیں بلکہ واحد مؤثر ذات باری ہے نیز اشیا کا اقتران اللہ کی عادت کی بنا پر ہے کہ وہ ایک کے بعد دوسری شے کو پیدا فرماتے ہیں۔ اشعری فریم ورک میں اللہ کی یہ عادت اشیا کے مابین تعلقات کے ان تجرباتی علوم کی بنیاد فراہم کرتی ہے جن کا ذکر اوپر گزرا، یہاں جنہیں دنیاوی اسباب کہا جاتا ہے اس کا معنی “معرف یا علم” (indicator) ہوتا ہے نہ کہ مؤثر و موجب ہونا، انہیں صرف مجازی معنی میں اسباب یا علل کہا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ کی عادت کا تجرباتی علوم کے مطالعے کی بنیاد ہونا، اس بات کو امام صاحب نے عین باب نمبر 17 ہی میں واضح کیا ہے جہاں وہ ناقدین کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ تمہارے نظرئیے کی رو سے تو پھر طبعی علوم کا اعتبار محال ہوگیا کہ ممکن ہے گھر میں رکھی کتاب میرے گھر جانے تک درندہ بن جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ کسی شے کا عقلا ممکن ہونا اور اس کے عملا واقع ہونا دو الگ باتیں ہیں اور جب بار بار کے مشاہدے سے ہمیں معلوم ہوجائے کہ الف کے بعد ب ہوتا ہے تو ہم مستقبل میں بھی اس کی توقع رکھنے میں حق بجانب ہوتے ہیں کہ الف کے بعد ج نہیں ب ہوگا، لیکن ج کا ہونا محال قرار نہیں دیا جاسکتا۔
2۔ فلاسفہ کے اصول پر کہ خود ان کے مطابق عالم میں ایسے اسباب (بمعنی مؤثرات) ہوسکتے ہیں جن کی بنا پر یہ معجزات ظاہر ہوتے ہوں اگرچہ انسان اب تک انہیں معلوم نہ کرسکا ہو
بتائیے اس میں ایسی کونسی بحث ہے جس نے لوگوں کو طبعی علوم سیکھنے سے روک دیا ہو؟ الغرض زیر بحث مسئلے میں امام غزالی پر اعتراض کرنے والوں نے آپ کی دیگر کتب تو کجا تھافت الفلاسفۃ بھی نہیں پڑھی ہوتی اور یہ لوگ بعض مستشرقین کی جانب سے امام صاحب کے بارے میں پھیلائی ہوئی سطحی قسم کی تحقیقات کو سچ مان کر اپنی “مفکری” کا رعب جھاڑتے رہتے ہیں۔



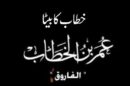



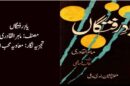


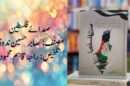







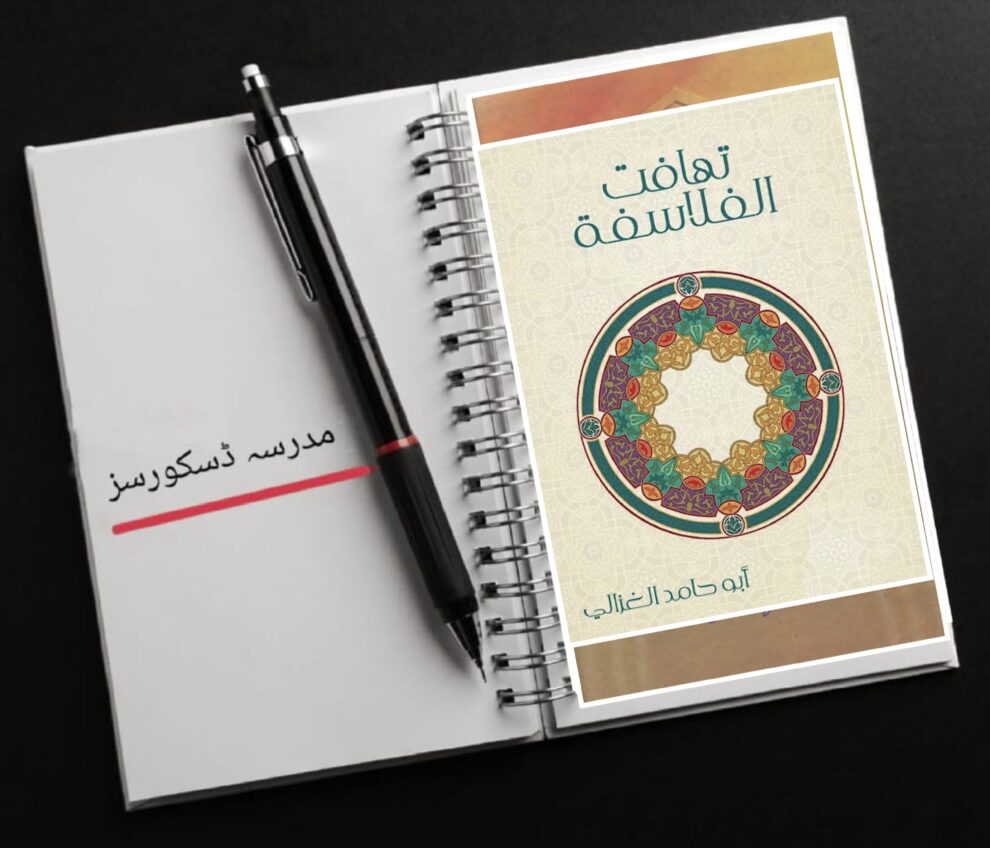

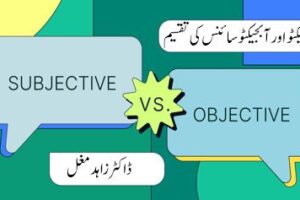
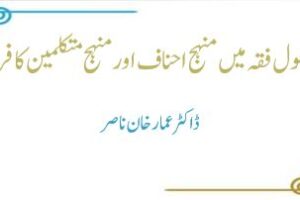
کمنت کیجے