
ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر
ستمبر کو ستمگر کہا گیا ہے اور دسمبر کے لئے بھی کچھ رومانویت برتی گئی ہے کسی نے کہا ”دسمبر اب مت آنا“ اور کسی نے کہا ”اس سے کہنا دسمبر آگیا ہے“ مگر جنوری کے لئے کسی نے کچھ نہ کہا۔ شائد سال کے ہر مہینے سے ہماری کوئی یاد وابستہ ہوتی ہے کچھ تلخ یادیں، کچھ اداس اور کچھ زندگی آمیز خوشگوار یادیں۔ وہ 7/جنوری کا سرد دن تھا، کراچی والوں کے لئے 10 درجے کی سردی بھی بہت ہوتی ہے۔ شام کے سات بج رہے تھے اور میں ایک گھنٹہ قبل ہی کمبل میں گھسی تھی۔ اس دن تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا آبائی پیشہ ”ڈرائیوری“ ہو۔ یونیورسٹی کی تعطیلات تھیں اور گھر کے سارے اوندھے سیدھے کام، بچوں کے بچوں کو اسکول سے لینا اور چھوڑنا، مختلف بینکوں میں فیسیں جمع کروانا، ایک بیٹی کے کپڑے ٹیلر کے یہاں سے اٹھانا، بہو کی گروزری کی لسٹ سے نبردآزما ہوتے ہوتے اور گھر آتے آتے شام کے چھ بج گئے تھے لہٰذا کمبل میں گھس کر ایک کپ گرما گرم چائے پی کر کچھ دیر کا مراقبہ (قیلولہ نہیں) ضروری تھا۔ مجھے چوبیس گھنٹوں میں سے وہ وقت سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے جو میں اپنے ساتھ گزارتی ہوں۔
تقریباً سات بجے کے قریب میرے موبائل پر ایک اجنبی نمبر چمکنے لگا جس کی طوالت بتاتی تھی کہ فون باہر سے آیا ہے۔ دوسری طرف میرے(کبیر احمد جائسی میرے سگے ماموں نہیں، بلکہ میری امی کے ماموں زاد بھائی تھے۔) ماموں کبیر احمد جائسی کا بڑا بیٹا ساجد تھا۔
”کیا حال ہے ساجد“میں نے پوچھا”ماموں کی طبیعت کیسی ہے۔“
”ابھی دو گھنٹے قبل شام پانچ بجے ابو کا انتقال ہوگیا ہے آپ کو اطلاع دینی تھی“اس انتہائی تکلیف دہ خبر پر میں نے اناﷲ پڑھا۔ ساجد نے فون ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی کو دے دیا تھا جو مجھے ماموں کی بیماری اور انتقال کی تفصیلات بتاتے رہے اور میرا معاملہ شائد اس سے مختلف نہیں تھا۔
شور برپا ہے خانہ دل میں
کوئی دیوار سی گری ہے ابھی
ایک گھنٹے تک تو میں صرف ماموں کو سوچتی اور یاد کرتی رہی پھر پاکستان بھر میں پھیلے ان کے دوستوں کو ان کی وفات کی خبر ایس ایم ایس کی۔ ڈاکٹر کبیر احمد کی وفات کا سب سے اذیت ناک پہلو یہ تھا کہ ابھی ان کے کئی کام ادھورے تھے، ابھی ایرانی تفاسیر کی چوتھی اور آخری کتاب پر ان کا کام چل رہا تھا، وہ مشاہیر کے ان سینکڑوں خطوط کو بھی مرتب کرنا چاہتے تھے جو ان کے علمی خزانے میں موجود تھے اور اپنے آخری خط میں انہوں نے مجھے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ شخصیات پر دوسو صفحات مرتب کرچکے ہیں لیکن مسودہ مجھے بھجوانے کی مہلت انہیں موت نے نہ دی۔ قرطاس کے دفتر میں عبدالسلام ندوی پر مرتب کردہ ان کی کتاب آخری مراحل میں تھی اور میں انہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی، سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔
حرکت قلب بند ہوئی اور قلم رک گیا۔ معلوم نہیں کون سا حادثہ زیادہ بڑا ہے!
کبیر احمد جائسی کی شناخت کے کئی پہلو تھے ان کا شاعرانہ، صحافیانہ اور مدیرانہ کردار بھی تھا کئی برس تک ”ادیب“ کے معاون مدیر کے طور پر کام کرتے رہے اقبال شناس بھی تھے کشمیر کے اقبال انسٹیٹیوٹ سے تین سال وابستہ رہے اور اقبال کے حوالے سے ان کی کئی گراں قدر تحریریں بھی ہیں، لیکن ان کی شخصیت کا سب سے غالب پہلو ان کی ایران شناسی تھی۔ انہوں نے فارسی زبان و ادب کے حوالے سے اہم کام کیئے اور ایرانی دانشوروں کو پاک و ہند میں متعارف کرایا۔
کہتے ہیں مرد کی کامیابی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے یہاں یہ معاملہ بھی نہیں تھا۔ ان کی زندگی میں ایک ہی عورت آئی جو ان کی بیوی ساجدہ تھی اور جو فقط ساڑھے گیارہ سال ان کا ساتھ دے کر جوانی میں ہی اچانک رخصت ہوگئی۔ کبیر احمد جائسی کی شادی 9/نومبر 1959ءمیں ہوئی تھی اور 5/مئی 1971ءکو ان کی بیوی مختصر علالت کے بعد اچانک چل بسیں۔ جس عمر میں بعض لڑکیاں اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کرتی ہیں اس عمر تک ساجدہ خالہ (وہ میری رشتہ کی خالہ بھی تھیں) چھ بچوں کو جنم دے کر خاموشی سے اس جہاں میں چلی گئیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ گزشتہ نسل تک ہندوستانی معاشرے میں لڑکیوں کے کئی نام رکھے جاتے تھے۔ پتا نہیں اس میں کیا حکمت ہوتی تھی کہ ایک لڑکی کا ننھیالی، ددھیالی اورسسرالی نام الگ الگ ہوتے تھے۔ ساجدہ ممانی /خالہ کا بھی سسرالی نام حسنہ تھا، یہ وہ نام تھا جو شادی کے بعد ان کی ساس نے رکھا تھا۔ بیوی کے انتقال کے بعد چند لوگوں نے جو یقیناً ان کے بہی خواہ رہے ہوں گے ان کو دوسری شادی کا مشورہ دیا ایک موقع پر ایک بیوہ خاتون کا نام بھی لیا گیا لیکن ان کے دل اور گھر پر راج کرنے والی ساجدہ ہی تھی وہ گئی تو انہوں نے دل اور گھر کے دروازوں کو آہنی زنجیروں سے مقفل کردیا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
کبیر احمد جائسی 16/نومبر 1934ءمیں جائس، ضلع رائے بریلی، یوپی میں پیدا ہوئے۔ (ان کے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ پر 16/ نومبر 1936ءدرج ہے، جو غلط ہے۔) جائس میں ان کا آبائی گھر محلہ شِیخَانہ میں تھا۔ وہیں ان کی پیدائش اس تاریک اور ہوا کا گزر نہ ہوسکنے والی کوٹھری میں ہوئی جس کو وہاں کی زبان میں ”سودر والی کوٹھری“ کہا جاتا ہے۔ جائس کے ہر مکان میں سودر والی کوٹھری ضرور ہوتی ہے جس میں اس گھر کے مکینوں کی اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کے والد ظہیر احمد اورسیر تھے اور 1919ءمیں اعظم گڑھ چلے گئے تھے لہٰذا کبیر احمد کا بچپن اور نوجوانی کا زمانہ اعظم گڑھ میں بھوج پوری زبان بولنے والوں کے درمیان گزرا۔ اعظم گڑھ میں ان کو بہت سے بزرگوں کی صحبت نصیب رہی جن میں مولانا عبدالسلام ندوی، اقبال سہیل اور کیفی چریاکوٹی کے نام اہم ہیں۔ خصوصاً عبدالسلام ندوی (1956ء) کے اثرات بہت دیرپا تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم شبلی ہائی اسکول، اعظم گڑھ سے حاصل کی، شبلی کالج سے انٹر کیا، یہیں ان کی پہلی کتاب ”نقوش فانی“ کے نام سے1958ءمیں طبع ہوئی جبکہ وہ چوبیس سالہ نوجوان تھے۔ یہیں ان کی شادی ہوئی۔
جولائی1960ءمیں وہ اعظم گڑھ سے علی گڑھ آگئے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے گریجویشن اور پھر فارسی میں ایم اے کیا۔ وہ جنوری 1961ءسے ڈاکٹر ابن فرید مرحوم کی ادارت میں شائع ہونے والے رسالے ”ادیب“ علی گڑھ کے معاون مدیر کے طور پر کام کرنے لگے۔ شائد کم لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ شاعر بھی تھے اور صبا تخلص کرتے تھے۔1969ءمیں ان کی غزلوں کا مجموعہ ”صحرا صحرا“ کے عنوان سے شایع ہوا۔ جس پر اترپردیش اردو اکیڈمی نے 1972ءمیں انہیں انعام سے نوازا۔ پاکستان میں اس کا اضافہ شدہ ایڈیشن ”جاویداں مضراب“ کے نام سے قرطاس کے تحت شائع کیا گیا۔ اپنی شاعری کے بارے میں جائسی لکھتے ہیں: ”ہر ایک شخص کا ایک کوبڑ ہوتا ہے میرا کوبڑ یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر شاعر ہوں۔“( کبیر احمد جائسی، جاوداں مضراب (حرف آغاز)، ص:26، قرطاس، کراچی 2008ء)لیکن شاعری ان کی روٹی روزی کا مسئلہ حل نہیں کرسکتی تھی جبکہ مقالہ نویسی اور نثرنگاری ان کی پیشہ ورانہ زندگی کی ضرورت تھی یوں وہ نثر کے ہوکر رہ گئے۔
ان کی شاعری پر شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں:
”صبا جائسی کے کلام میں ایک رومانوی حزن ملتا ہے جو فانی سے مختلف ہے اگرچہ وہ فانی کے حددرجہ قائل رہے ہیں اور شائد اب بھی ہیں، مجھے ان کے رومانوی حزن میں ان چھوٹے چھوٹے لیکن انتہائی سچے غزل گویوں کا تاثر ملتا ہے جن کا ذاتی لہجہ اردو غزل پر ہمیشہ کے لیے اپنا اثر چھوڑ گیا ہے۔ میری مراد قائم، سوز، احسنﷲ بیان اور مصحفی وغیرہ سے ہے۔“ ( شب خون (الٰہ آباد) بابت جنوری1970ء، ص: 76، )
یہیں ان کی بیوی کا انتقال ہوا اس زمانے میں وہ اپنے پی –ایچ- ڈی مقالے پر کام کررہے تھے ان کے نگران پروفیسر نذیر احمد (سابق صدر شعبہ فارسی اور ڈین کلیہ فنون، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی) تھے۔ بیوی کی وفات کے محض دو سال بعد انہوں نے پی- ایچ- ڈی کا مقالہ مکمل کرلیا۔ یہ دو سال معمولی نہیں تھے۔ ایک طرف معاشی مسائل تھے جن سے نبٹنے کے لئے وہ چھوٹی موٹی ملازمتیں کرتے رہے دوسری طرف بیمار بزرگ والدین کا ساتھ تھا اوپر سے چھ بچوں کی ذمہ داری لیکن بہرحال یہ چومکھی انہوں نے لڑی اور پھر تو جیسے پوری زندگی ان کے لئے چومکھی ہوگئی۔ وہ خود لکھتے ہیں:
”نومبر 1969ءسے لے کر ستمبر1974ءتک کا دور میری زندگی کا تکلیف دہ اور تاریک ترین دور تھا، اسی دور میں ایک تقرری کے سلسلے میں اپنے استاد رہنما پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد سے میرا اختلاف ہوا جس کے نتیجے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کا دروازہ میرے لیے اس طرح بند کردیا گیا کہ میں پھر کبھی اس میں داخل ہی نہ ہوسکا، اسی تاریک ترین دور میں میری اہلیہ کا اچانک انتقال ہوا اور میں زندگی کے اجاڑ صحرا میں یکہ وتنہا رہ گیا، اسی تاریک ترین دور میں لگائی بجھائی کرنے والوں نے میرے خیرخواہوں اور مداحوں کے دلوں میں میرے خلاف بدگمانیوں کا ایک پہاڑ کھڑا کردیا۔ ستمبر 1974ءمیں جب مجھے جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی میں لکچررشپ ملی تو میں ہر طرح سے ٹوٹا اور بکھرا ہوا تھا۔“ ( کبیر احمد جائسی، شمس کبیر (پیش لفظ)، ص:۹، قرطاس، کراچی، 2004ء)
علی گڑھ سے اگلی منزل دہلی تھی جہاں وہ ستمبر1974ءمیں پہنچے۔ انہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں فارسی کا استاد مقرر کیا گیا تھا۔ اس جامعہ سے وہ چھ سال یعنی اکتوبر 1980ءتک وابستہ رہے۔ اس دوران ان کے والدین کا بھی انتقال ہوگیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی ملازمت کے دوران ان کی چار کتابیں منظرعام پر آئیں۔
۱۔ بازگشت (1975ء) : یہ کتاب فارسی ادب سے متعلق جائسی صاحب کے مقالات کا مجموعہ ہے جس میں انہوں نے تین ایسے ایرانی اساطین ادب پر تنقیدی نظر ڈالی ہے جن کے بارے میں اردو دان طبقے کو کم علم تھا یعنی مجیربیلقائی، احمد کسروی اور استاد عبدالعظیم قریب۔ ”حافظ اور اقبال“ کے عنوان سے ان کا مشہور مقالہ بھی اسی کتاب میں شامل ہے۔
۲۔ تاریخی اور علمی مقالے (1976ء) : اس کتاب میں جائسی صاحب نے اپنے استاد پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد کے تین رسائل (Monographs) کا انگریزی سے اردو ترجمہ کیا ہے۔
۳۔ تاریخ ادبیات تاجکستان (1977ء) : اردو کی یہ وہ پہلی کتاب ہے جس نے اردو دان طبقے کو اس بات کا احساس دلایا کہ فارسی ادب صرف ایران ہی کی میراث نہیں ہے بلکہ اس کی پیشرفت میں اس علاقے کے ادباءاور شعراءکا بھی قابل ذکر حصہ ہے جس کو قدیم زمانے میں ماورا النہر (Transoxiana) کہا جاتا تھا۔ اس ضخیم کتاب کو جائسی صاحب نے انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا۔ تاجیکی ادبیات کے مطالعہ کی یہی وہ پہلی اینٹ تھی جس پر آگے چل کر انہوں نے ایک مضبوط عمارت تعمیر کی۔ اس ترجمہ پر انہوں نے تیسری بار اترپردیش اکیڈمی ایوارڈ (1977ء) حاصل کیا۔
۴۔ آذری (1978ء) : آذری، آذر بائیجان کی زندہ زبان ہے جس کے بارے میں اردو دنیا لاعلم تھی۔ اس فارسی کتاب کا اردو میں ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ کبیر صاحب کا ایک عالمانہ مقدمہ بھی ہے۔
دہلی سے اگلا پڑاؤ کشمیر کا تھا۔ اواخر1980ءیا شائد اوائل 1981ءمیں وہ کشمیر یونیورسٹی کے اقبال انسٹیٹیوٹ (سری نگر) سے وابستہ ہوگئے۔ اس وقت انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر پروفسیر آل احمد سرور تھے اور وہ ہی کبیر جائسی کو بحیثیت ریڈر سری نگر لائے۔ اس تین سالہ دور میں ان کی تین کتابیں منظرعام پر آئیں۔
۵۔ علامہ اقبال مصلح قرن آخر : یہ معروف ایرانی مفکر علی شریعتی کی اس مشہور تقریر کا ترجمہ ہے جو انہوں نے تہران کے دینی مدرسہ حسینیہ ارشاد میں دی تھی۔ جائسی صاحب نے صرف اس تقریر کا ترجمہ ہی نہیں کیا بلکہ اس پر ایک طویل اور پرمغز مقدمہ لکھ کر اردو دان طبقہ کو علی شریعتی کے حیات و افکار سے روشناس کرایا۔ جگن ناتھ آزاد لکھتے ہیں:
”حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر علی شریعتی کی اس تقریر کا اردو ترجمہ کرکے ڈاکٹر جائسی نے اقبالیات کے سلسلے میں ایک اہم کام انجام دیا ہے، اقبال پر انگریزی یا یورپ کی دوسری زبانوں میں جو کام ہورہا ہے وہ اپنی اصل صورت میں یا اردو ترجموں کی صورت میں ہم تک بہت جلد پہنچ جاتا ہے لیکن ایران یا دوسرے مشرقی ممالک میں جو کام ہورہا ہے اس سے ہم اکثر ناآشنا رہتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کا سبب فارسی زبان سے ہماری بیگانگی یا بے اعتنائی ہے یہی سبب ہے کہ تاجکستان، افغانستان اور ایران میں اقبال پر جو کام ہورہا ہے وہ اپنی بے پایاں اہمیت کی اہمیت کے باوجود ہم اردو والوں تک نہیں پہنچ رہا ہے۔“ ( اقبال ریویو، لاہور، بابت جنوری1983ء، ص: 225)
۶۔ محمد اقبال : یہ دراصل تاجکستان کے مشہور شاعر و ادیب میرسید میرشکر کا ایک دیباچہ ہے جو انہوں نے اقبال کے فارسی مجموعہ کلام ”پیام مشرق“ کے لئے لکھا۔ یہ فارسی مجموعہ 1966ءمیں دوشنبہ (تاجکستان) سے شائع ہوا۔ جسے ڈاکٹر جائسی نے اردو کا قالب دیا کتاب میں انہوں نے ایک طویل مقدمہ بھی لکھا جس میں میرسید میرشکر کی سوانح حیات اور افکار پر تنقیدی نظر ڈالی ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ کرنے میں جائسی صاحب نے جو محنت کی وہ قابل تعریف ہے کیونکہ اصل کتاب روسی رسم الخط میں تھی پہلے یہ ساری کتاب فارسی رسم الخط میں منتقل کی گئی اور پھر اردو میں ترجمہ کیا گیا۔
۷۔ ذبیح اﷲ صفا، حیات و کارنامے : ان کی یہ طبع زاد کتاب بھی اسی دور میں شائع ہوئی۔
سری نگر کی حسین وادیوں میں اپنی زندگی کے تین سال گزارنے کے بعد ان کا اگلا ٹھکانہ پھر علی گڑھ تھا جہاں جنوری1984ءکو انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ علوم اسلامیہ میں علوم فارسی کے ریڈر کے طور پر اپنی خدمات کا آغاز کیا اور اپنی سبکدوشی (30/نومبر 1996ء) تک تقریباً تیرہ سال اسی شعبہ سے منسلک رہے یہی وہ دور ہے جب میرا کبیر ماموں سے قلمی رابطہ استوار ہوا۔ ہمارے درمیان1997ءءسے آخری وقت تک خط و کتاب کا سلسلہ جاری رہا ان کے تقریباً ۴۵ خطوط میرے پاس محفوظ ہیں جس میں ان کی اس دور کی علمی و تحقیقی فتوحات کا تذکرہ بھی محفوظ ہے اس دور میں ان کی پانچ مزید کتب منظرعام پر آئیں۔
۸۔ انعکاس (1987ء) : یہ ان کے آٹھ علمی مقالات کا مجموعہ ہے۔ پہلا مقالہ مجیر بیلقائی پر ہے جو خاقانی جیسے استاد سخن کا شاگرد تھا۔ دوسرا مقالہ علی شریعتی اور اقبال، تیسرا مقالہ حافظ کی شاعری پر ایک نئی نظر، چوتھا مقالہ سعید نفیسی کے اجتہادات پر ہے۔ پانچواں مضمون پروفیسر ہادی حسن مرحوم کی علمی خدمات پر ہے۔ چھٹا مضمون اقبال کی رمزیت پر، ساتواں مضمون محمد شاہی عہد کی ایک غیرمطبوعہ نادر فارسی مثنوی ہے اور آٹھواں مضمون محمد شاہ کے بھائی شاہزادہ اختر کی ایک غیرمطبوعہ مثنوی پر ہے۔
۹۔ سوویتی۔ تاجیکی ادبیات کے بانی (1989ء) : یہ کتاب تین ابواب پر مشتمل ہے پہلے باب میں تاجکستان کا جغرافیہ اور تاجک قوم کی اصل سے بحث کی گئی ہے۔ کتاب کا دوسرا باب سوویتی۔ تاجیکی ادبیات کے معمار اول صدرالدین عینی کی حیات، ان کے عہد اور ان کی شاعرانہ کاوشوں سے متعلق ہے۔ تیسرے باب میں صدرالدین عینی کے شریک کار ابوالقاسم لاہوتی کے عہد، حیات و شاعری سے بحث کی گئی ہے۔اس کتاب پر ڈاکٹر جائسی کو سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ کا حقدار قرار دیا گیا۔
10۔ جدید تاجیکی شعراء(1990ء) : یہ کتاب ان چھ سوویتی۔ تاجیکی شعراءکے مطالعے پر مشتمل ہے جو انقلاب بخارا (1920ء) سے قبل پیدا ہوئے تھے۔ مگر ان کی اٹھان انقلاب بخارا کے بعد کے پرہیجان ماحول میں ہوئی۔
11۔ چند ایران شناس (1992ء) : یہ کتاب ایسے چار مقالات پر مشتمل ہے جن میں چند غیر ایرانیوں کا تذکرہ ہے۔ جنہوں نے ایران اور ایرانی قوم کو اس کے ادب کے ذریعے جاننے اور اپنے ہم وطنوں کو اس سے متعارف کرانے کی کوشش کی ہے۔ ان دانشوروں میں ایک احمد آتش ہیں جن کا تعلق ترکی سے ہے۔ دوسرے اٹلی کے الیساندرو بوزانی ہیں۔ تیسرے میخائل زند چند کا تعلق اسرائیل سے اور چوتھے پروفیسر یرژی بیچکا ہیں جن کا تعلق چیکوسلاویکیہ سے ہے۔
12۔ ایرانی تصوف (1993ء) : کبیر احمد جائسی کی یہ وہ تصنیف ہے جس میں انہوں نے ایران کے مشہور شیعہ عالم سعید نفیسی کی تصوف پر ایک اہم کتاب ”سرچشمہ تصوف درایران “کے مباحث سے اردو دان طبقے کو متعارف کرایا ہے۔
13۔ مثنوی ناہید و اختر (1994ء) : یہ کتاب فارسی میں ہے جس میں ڈاکٹر جائسی کا فارسی زبان میں لکھا ہوا مقدمہ اور مثنوی کا اصل متن ہے۔ یہ وہی مثنوی ہے جو محمد شاہ کے چھوٹے بھائی نے لکھی تھی اور انعکاس میں اس پر اردو میں مضمون بھی ہے۔
30/نومبر 1996ءکو60 سال کی عمر میں وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ملازمت سے ریٹائر ہوئے۔ دسمبر کے اواخر میں یونیورسٹی کا مکان چھوڑ کر ایک کرایہ کے مکان میں منتقل ہوگئے۔ ساڑھے تین سال کے عرصہ کے بعد جب اقراءکالونی، نیو سرسید نگر میں ان کا ذاتی مکان بن گیا تو انہوں نے اس کا نام ’ساجدہ منزل‘ رکھا اور 30/مئی 1999ءمیں وہ اپنے نئے گھر میں منتقل ہوگئے۔ یہ میرا مشاہدہ ہے کہ وہ اساتذہ کے جن کا قلم سے خصوصی رشتہ ہوتا ہے سبکدوشی کے بعد ان کا قلم سے رابطہ اور بھی مضبوط ہوجاتا ہے یہی معاملہ کبیر صاحب کے ساتھ ہوا۔ ملازمت سے سبکدوشی کے بعد بھی ان کا قلم رواں رہا اور جو تخلیقات منظرعام پر آئیں وہ انڈیا کے علاوہ پاکستان کے ادارہ قرطاس (کراچی) سے بھی طبع ہوئیں۔
جائسی صاحب نے تنگ دستی کے انتہائی شدید دن دیکھے تھے لہٰذا فطری طور پر ان میں قناعت کا جذبہ پیدا ہوگیا تھا۔ جہاں ایک روپے میں کام چل سکتا وہاں کبھی انہوں نے سوا روپیہ خرچ نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے ہندوستانی ایروگرام پر خط لکھا البتہ اگر انہیں کوئی مضمون بھیجنا ہوتا تب مجھے لفافہ موصول ہوتا۔ انہوں نے شائد ہی کبھی کوئی کاغذ، جس پر چند سطور لکھنے کی گنجائش ہو، ضائع کیا ہو۔ ایک بار انہوں نے مجھے اپنا ایک مقالہ ”تفسیر نسفی“ جس کاغذ پر لکھ کر بھیجا تھا اسے ہم پنّی کہہ سکتے ہیں۔ جو ٹریسنگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب مجھے یہ قیمتی مقالہ اس قدر کمزور اور بوسیدہ کاغذات پر لکھا ہوا ملا تو میری جان نکل گئی کہ اب اس کی حفاظت کار دشوار تھی، ان کے بعض خط بھی اسی پنّی نما کاغذ پر لکھے ہوئے ہیں جن کو موصول ہوتے ہی میں مضبوط کاغذ پر چپکاکر محفوظ کرلیتی تھی۔
شمس کبیر کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں کہ جب ستمبر1974ءمیں انہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی میں لکچررشپ ملی تو سردیوں کے آنے پر انہیں احساس ہوا کہ ان کے پاس ایک ہی گرم شیروانی ہے۔ ملازمت کے پہلے سال ان کے کسی دوست نے دہلی کے کسی فٹ پاتھ سے دو پتلون (قیمت 70روپے) اور دو کوٹ (قیمت90روپے) خریدکر جائسی کو دیئے۔ انہوں نے اپنی بائیس سالہ مدت ملازمت میں کوئی کوٹ اور پتلون نہیں سلوایا۔
میرے والدین ہندوستان سے پاکستان جولائی1962ءمیں آئے تھے اس وقت میری عمر سات سال تھی۔ ہندوستان میں اگر میری ماموں سے کوئی ملاقات ہوئی ہو تو میرے ذہن میں محفوظ نہیں البتہ ہمارے پاکستان آنے کے بعد کبیر جائسی صاحب ایک بار 1987ءمیں کراچی آئے تھے۔ اس موقع پر ان سے دو ایک ملاقاتیں ہوئیں تھیں، اس وقت جامعہ کراچی میں میری نئی نئی تقرری ہوئی تھی۔ میرا کبیر ماموں سے قلمی رابطے کا آغاز اگست 1997ءمیں ہوا، یہ رابطہ ان کے انتقال کے وقت تک برقرار رہا۔ اس پندرہ سالہ عرصہ میں میرے پاس ان کے پچاس سے زائد خطوط آئے۔ یہ خط و کتابت بوجوہ کئی کئی ماہ معطل بھی رہی۔ مجھے یاد ہے میں نے اپنے ابتدائی خطوط میں ان سے اپنی یادداشت یا سوانح مرتب کرنے کی فرمائش کی تھی جو وہ کاموں کی زیادتی کی وجہ سے ٹالتے رہے اور یہ کام نہ ہوسکا۔
ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی شائع ہونے والی کتابوں کی تفصیل یہ ہے۔
14۔ ایران کی چند اہم فارسی تفسیریں، جلد اول (2000ء) ،قرطاس۔
15۔ ایران کی چند اہم فارسی تفسیریں، جلد دوئم (2001ء) : قرطاس کراچی۔
16۔ ڈھونڈو گے انہیں (2002ء) : مطبوعہ قرطاس کراچی۔ اس کتاب میں علی گڑھ سے تعلق رکھنے والی بارہ شخصیات کے خاکے شامل ہیں۔
17۔ شمس کبیر (2004ء) : مطبوعہ قرطاس کراچی۔ یہ کتاب ان خطوط کا مجموعہ ہے جو شمس الرحمن فاروقی نے کبیر احمد جائسی کو اپریل 1958ءسے مارچ 2000ءتک کے عرصے میں لکھے۔
18۔ جاویداں مضراب (2005ء) : صحرا صحرا کے عنوان سے شائع ہونے والے ان کے شعری مجموعے کا یہ دوسرا ایڈیشن ہے جو نظرثانی اور اضافوں کے بعد قرطاس کراچی سے شائع کیا گیا۔
19۔۔ ایران کی چند اہم فارسی تفسیریں، جلد سوئم (2010ء) : مطبوعہ قرطاس کراچی۔
20۔ عبدالسلام ندوی۔ ایک مطالعہ : قرطاس کراچی۔
جہاں تک ان کی اداریہ نویسی کا تعلق ہے پہلے انہوں نے ’کانفرنس گزٹ‘ بعدازاں ’تہذیب الاخلاق‘ کی ادارت سنبھالی۔ یہ دونوں جرائد اپنے مقاصد کے اعتبار سے ہم آہنگ ہیں ان کی اشاعت کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو ایک طرف جدید علوم سے روشناس کرانا ہے تو دوسری طرف اپنے قابل ذکر علمی، ثقافتی اور تہذیبی ورثے سے واقف کرانا ہے۔ ان دونوں جرائد کا تعلق علی گڑھ سے ہے۔ جائسی نے ان جرائد کے لئے متنوع عصری مسائل پر سوسے زائد اداریے سپرد قلم کیے۔ 1989ءتا 1992ءوہ ’مجلہ علوم اسلامیہ‘ اور ’بلیٹن اور اسلامک اسٹڈیز‘ بھی نکالتے رہے۔
ڈاکٹر جائسی کے دوسو سے زائد علمی مقالے ہندوستان اور دیگر ممالک کے اہم جرائد میں شائع ہوچکے ہیں۔ انہوں نے پچیس سے زائد قومی اور بین الاقوامی کانفرنسوں اور سیمینار میں شرکت کی جوکہ دہلی، سری نگر اور علی گڑھ وغیرہ میں منعقد ہوئے نیز 1977میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لئے تہران بھی گئے اور ایک سے زائد مرتبہ پاکستان بھی آئے۔
کبیر جائسی کا انتقال ہوگیا ہے لیکن ابھی کرنے کے بہت سے کام باقی ہیں اپنے آخری خط میں انہوں نے مجھے اطلاع دی تھی کہ شخصیات پر دوسو صفحات کے قریب ایک مسودہ اشاعت کے لئے تیار ہے۔2005ءکے اوائل میں انہوں نے مجھے اطلاع دی تھی کہ ان کے مقالات کا ایک مجموعہ مرتب کیا ہوا رکھا ہے۔ گزشتہ پچاس برسوں میں اساطین ادب نے ان کو جو خطوط لکھے وہ سب ان کے پاس محفوظ ہیں اگر ان کو مرتب کیا جائے تو بلامبالغہ چار جلدوں میں آئیں گے۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ ان کے تمام علمی کاموں کو سمیٹ کر محفوظ کردوں۔ ان کی وفات ان کے لواحقین کے لئے ہی صدمہ نہیں بلکہ علمی دنیا بھی اداس ہے۔
شاد باید زیستن نا شاد باید زیستن
(مطبوعہ ”الایام“،شمارہ 7،جنوری ۔ جون 2013ء)
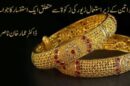
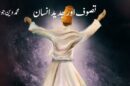
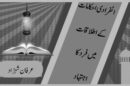
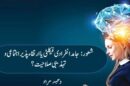


















کمنت کیجے